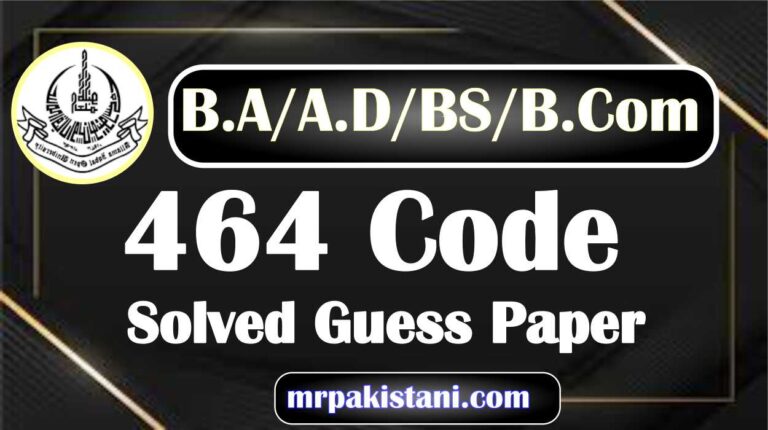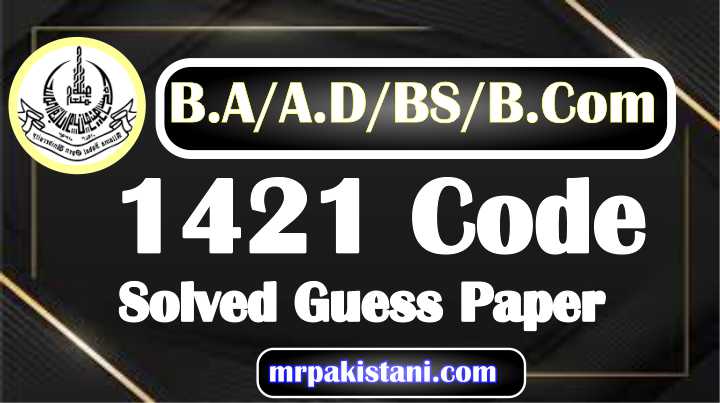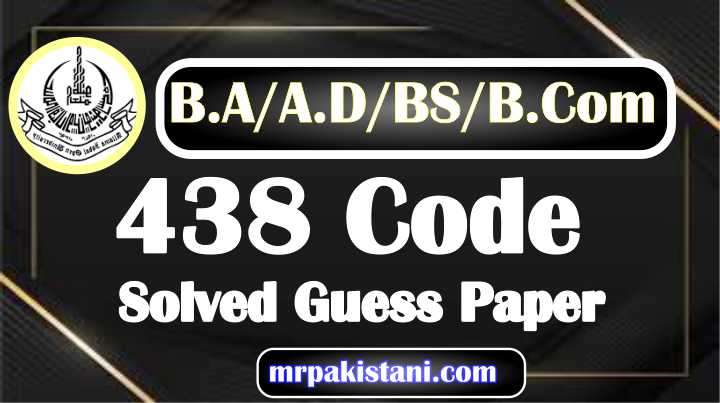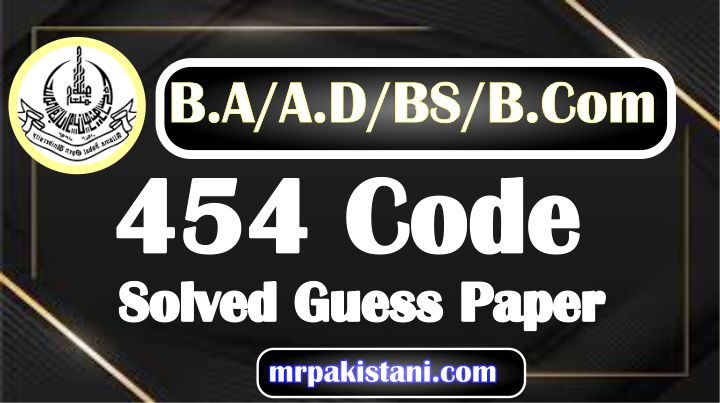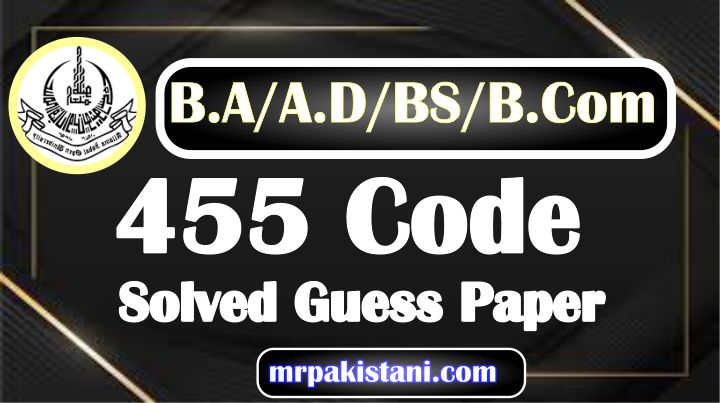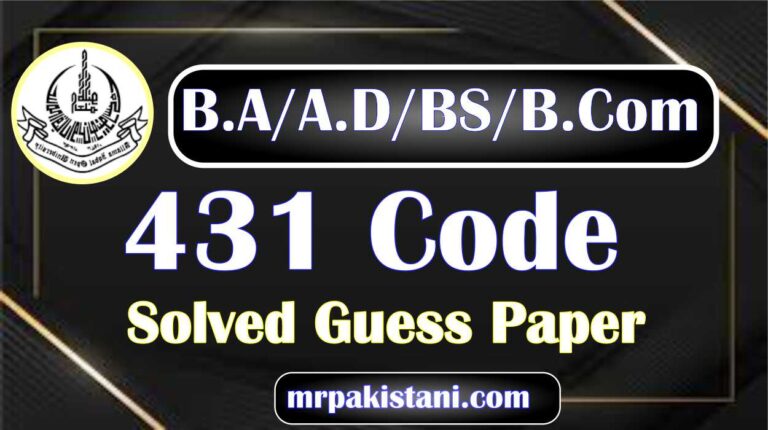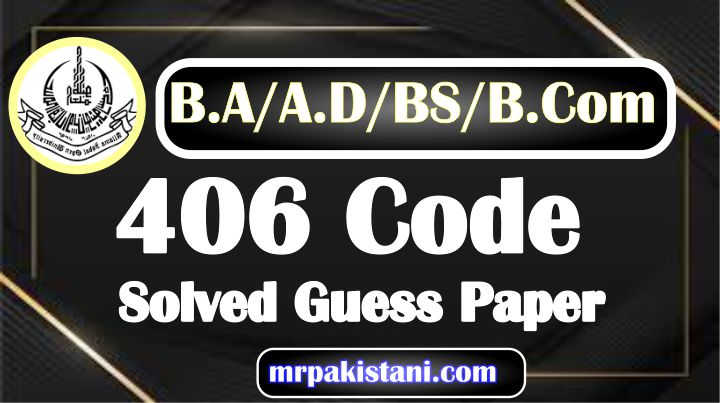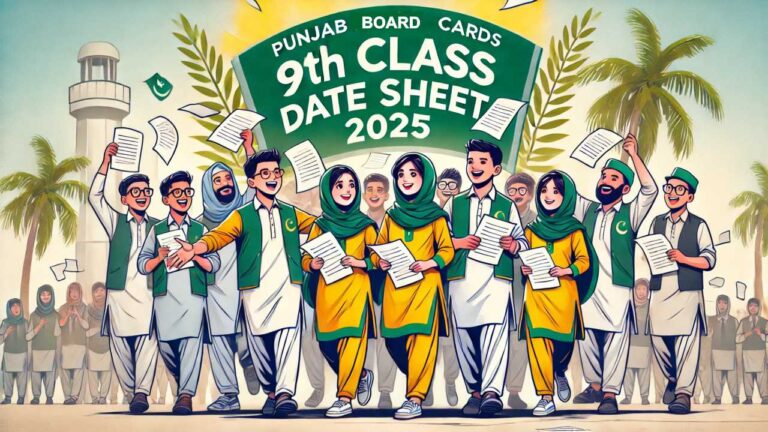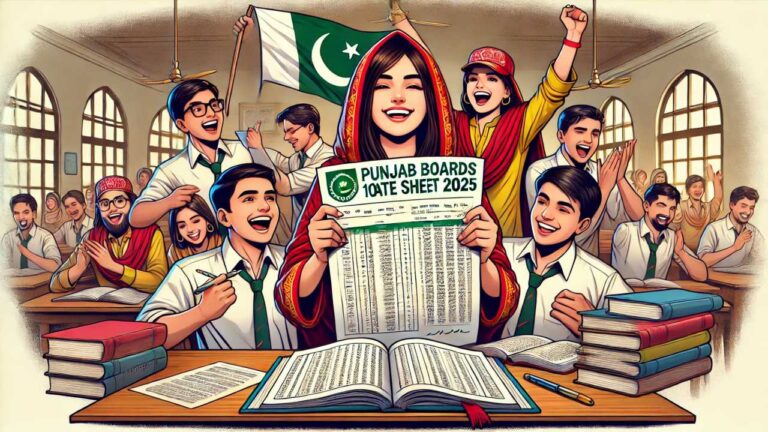AIOU 464 Code Islamic Fiqh Solved Guess Paper
Get ready for your exams with the AIOU 464 Code Islamic Fiqh Solved Guess Paper 2025, specially compiled to highlight the most expected questions from the book “اسلامی فقہ”. This guess paper focuses on major topics including the basic principles of Fiqh, various schools of thought, and practical applications of Islamic jurisprudence. Ideal for last-minute revision, this resource can help you understand key concepts quickly and perform better in exams. For more educational resources and free downloads, visit mrpakistani.com and subscribe to our YouTube channel Asif Brain Academy.
464 Code Islamic Fiqh Solved Guess Paper | 📥 Download PDF
سوال نمبر 1:
فقہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف کریں۔ نیز فقہ کی ضرورت و اہمیت اور تدوین فقہ کے بارے میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔
فقہ کا لفظ “فَقِهَ” سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں “سمجھنا، گہرائی سے جاننا”۔ لغت میں فقہ کا مطلب ہے کسی چیز کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا، خصوصاً دین کے معاملات میں۔
فقہ کی اصطلاحی تعریف:
فقہ کی اصطلاحی تعریف یوں کی جاتی ہے: “شریعتِ اسلامی کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔” اس میں عبادات، معاملات، معاشرت، حدود و تعزیرات، نکاح و طلاق، اور دیگر عملی امور شامل ہوتے ہیں۔
فقہ کی ضرورت و اہمیت:
- عملی زندگی کی رہنمائی: فقہ انسان کو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا شرعی حل مہیا کرتا ہے۔
- اللہ کی رضا: فقہی احکام پر عمل کر کے بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور نجات کا مستحق بنتا ہے۔
- اجتماعی نظام: فقہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کرتا ہے اور اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔
- دینی شعور کی بیداری: فقہ کے ذریعے مسلمان کو حلال و حرام، جائز و ناجائز اور فرائض و مستحبات کی پہچان ہوتی ہے۔
- عدل و انصاف: فقہ کے اصول عدل پر مبنی ہوتے ہیں جو انسانی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔
تدوینِ فقہ:
فقہ کی تدوین کا عمل دورِ نبوی ﷺ سے ہی غیر رسمی طور پر جاری تھا۔ نبی کریم ﷺ کے بعد صحابہ کرامؓ، خصوصاً خلفائے راشدینؓ نے اجتہاد کیا اور فتاویٰ دیے۔ باقاعدہ تدوین فقہ کے ادوار درج ذیل ہیں:
1. دورِ صحابہؓ:
صحابہ کرامؓ اجتہاد کے ذریعے لوگوں کو مسائل کا شرعی حل فراہم کرتے تھے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، زید بن ثابتؓ اور دیگر فقہ میں نمایاں تھے۔
2. دورِ تابعین:
تابعین نے صحابہ سے سیکھے ہوئے علم کو آگے بڑھایا اور فتاویٰ مرتب کیے۔ اس دور میں فقہ کو ترتیب دینے کی کوشش کی گئی۔
3. ائمہ مجتہدین کا دور:
اس دور میں چار مشہور فقہی مذاہب کی بنیاد رکھی گئی:
- امام ابو حنیفہؒ: فقہ حنفی کے بانی۔
- امام مالکؒ: فقہ مالکی کے بانی۔
- امام شافعیؒ: اصول فقہ کے بانی اور فقہ شافعی کے مؤسس۔
- امام احمد بن حنبلؒ: فقہ حنبلی کے بانی۔
ان ائمہ نے قرآن و حدیث، اجماع، قیاس اور دیگر اصولوں پر مبنی فقہی نظام مرتب کیا۔
نتیجہ:
فقہ اسلامی شریعت کا ایک اہم شعبہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ فقہ کی تدوین ایک عظیم علمی کارنامہ ہے جس نے امت مسلمہ کو ایک ضابطۂ حیات فراہم کیا۔ آج بھی فقہ کے اصول مدارس دینیہ میں پڑھائے جاتے ہیں اور جدید مسائل میں اجتہادی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔
سوال نمبر 2:
آئمہ اربعہ اور ان کے فقہی مذاہب پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔
آئمہ اربعہ سے مراد وہ چار عظیم المرتبہ مجتہد فقہاء ہیں جنہوں نے اسلامی فقہ کی بنیاد رکھی اور اپنے اپنے فقہی مذاہب کی تشکیل کی۔ ان کی خدمات نے امت مسلمہ کو شرعی معاملات میں رہنمائی فراہم کی۔ ان کے نام درج ذیل ہیں:
- امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ
- امام مالک بن انسؒ
- امام محمد بن ادریس الشافعیؒ
- امام احمد بن حنبلؒ
1. امام ابو حنیفہؒ (80ھ – 150ھ):
امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ کو “امام اعظم” کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق کوفہ (عراق) سے تھا۔ آپ نے فقہ میں قیاس، استحسان، عرف اور اجماع کو اصولی حیثیت دی۔ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے آپ کے علم کو مدون کیا۔ آپ کی فقہ کو “فقہ حنفی” کہا جاتا ہے جو برصغیر، ترکی، افغانستان، وسطی ایشیا اور دیگر ممالک میں رائج ہے۔
فقہ حنفی کی خصوصیات:
- قیاس اور استحسان کا بھرپور استعمال۔
- عام انسانوں کی سہولت اور مصلحت کو مدنظر رکھنا۔
- قرآن و حدیث کے بعد رائے اور اجتہاد کو اہمیت دینا۔
- تفصیلی اصولِ فقہ کی تشکیل۔
2. امام مالک بن انسؒ (93ھ – 179ھ):
آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہیں علوم حاصل کیے۔ آپ نے “موطا امام مالک” کے نام سے مشہور حدیث و فقہ کی کتاب لکھی۔ آپ کے نزدیک اہلِ مدینہ کا عمل حجت کی حیثیت رکھتا تھا کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ کے زمانے کی عملی سنت کے سب سے قریبی گواہ تھے۔ آپ کے فقہی مکتب کو “فقہ مالکی” کہا جاتا ہے جو شمالی افریقہ، مراکش، الجزائر، لیبیا، سوڈان اور خلیج کے بعض حصوں میں رائج ہے۔
فقہ مالکی کی خصوصیات:
- عمل اہل مدینہ کو شرعی دلیل کی حیثیت دینا۔
- مصالح مرسلہ (عوامی فلاح) کو اختیار کرنا۔
- حدیث اور سنت کو بنیاد بنانا۔
- روایات پر گہری تحقیق اور احتیاط۔
3. امام محمد بن ادریس الشافعیؒ (150ھ – 204ھ):
امام شافعی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور بغداد و مصر میں علوم حاصل کیے۔ آپ نے اصول فقہ کو ایک مستقل علم کی حیثیت سے مرتب کیا۔ ان کی مشہور کتاب “الرسالہ” اصول فقہ کی اولین کتاب ہے۔ ان کا فقہی مکتب “فقہ شافعی” کہلاتا ہے جو انڈونیشیا، ملائیشیا، یمن، مصر اور شامی علاقوں میں مقبول ہے۔
فقہ شافعی کی خصوصیات:
- قرآن و سنت کو بنیادی مصدر قرار دینا۔
- حدیث کی صحت پر سخت معیار قائم کرنا۔
- اجماع اور قیاس کو اصولی حیثیت دینا۔
- دلائل کی ترتیب: قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔
4. امام احمد بن حنبلؒ (164ھ – 241ھ):
امام احمد کا تعلق بغداد سے تھا۔ آپ حدیث کے عظیم حافظ و محدث تھے۔ آپ کی مشہور کتاب “مسند احمد بن حنبل” میں ہزاروں احادیث جمع ہیں۔ آپ نے فقہی مسائل میں حدیث کو سب سے مقدم رکھا اور قیاس و رائے کو کم استعمال کیا۔ ان کے مکتب کو “فقہ حنبلی” کہا جاتا ہے، جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں غالب ہے۔
فقہ حنبلی کی خصوصیات:
- حدیث پر سختی سے عمل۔
- قیاس، مصالح مرسلہ اور استحسان سے احتراز۔
- محدثانہ اسلوب میں فتویٰ دینا۔
- سنت پر عمل میں سختی اور تقلید میں احتیاط۔
آئمہ اربعہ کی خدمات:
- فقہ اسلامی کی بنیادیں مضبوط کرنا۔
- عوام و خواص کے لیے شریعت کی رہنمائی فراہم کرنا۔
- امت کو انتشار سے بچا کر ایک منظم فکری نظام دینا۔
- اسلامی شریعت کو محفوظ رکھنا اور نئے مسائل کے حل کے اصول مرتب کرنا۔
نتیجہ:
آئمہ اربعہ نے اسلامی فقہ کی تدوین میں جو خدمات سرانجام دیں وہ رہتی دنیا تک قابل قدر رہیں گی۔ ان کے فقہی مکاتبِ فکر امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں۔ اگرچہ ان کے اجتہادی آراء میں فرق ہے، مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: قرآن و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی۔ آج بھی یہ فقہی مذاہب دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ان کے پیروکار موجود ہیں۔
سوال نمبر 3:
نکاح کی تعریف، ارکان اور شرائط تحریر کریں۔ نیز نکاح کے مستحبات پر روشنی ڈالیں۔
لغوی طور پر نکاح کا مطلب ہے “ملاپ” یا “جمع ہونا”۔ اصطلاحی طور پر نکاح ایک ایسا شرعی معاہدہ ہے جس کے ذریعے ایک مرد اور عورت آپس میں میاں بیوی کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تاکہ وہ ایک پاکیزہ زندگی گزار سکیں اور نسل انسانی کو مشروع طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
ترجمہ: اور اپنے میں سے جو مرد و عورت نکاح کے قابل ہوں ان کا نکاح کر دو۔ (سورۃ النور: 32)
نکاح کے ارکان:
نکاح کے تین بنیادی ارکان ہوتے ہیں:
- ایجاب (پیش کش): یعنی ایک فریق کی طرف سے نکاح کی پیش کش، جیسے “میں نے تم سے نکاح کیا۔”
- قبول (رضامندی): یعنی دوسرے فریق کی طرف سے قبول کرنا، جیسے “میں نے قبول کیا۔”
- عاقدین (مرد اور عورت): یعنی وہ دو افراد جن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہو۔
نکاح کی شرائط:
نکاح کے درست ہونے کے لیے درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:
- رضامندی: دونوں فریقوں (مرد و عورت) کی مکمل رضامندی ضروری ہے۔ زبردستی کیا گیا نکاح باطل یا فاسد ہو سکتا ہے۔
- دو گواہوں کی موجودگی: نکاح میں دو عاقل، بالغ اور مسلمان مرد گواہوں کی موجودگی لازمی ہے، یا ایک مرد اور دو عورتیں۔
- مہر کا تعین: مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔
- ولی کی اجازت: عورت کے لیے (بالخصوص کنواری کے لیے) ولی کی اجازت کا پایا جانا اکثر فقہی مکاتب میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔
- شرعی موانع کا نہ ہونا: مثلاً محرم رشتہ، عدت میں ہونا، یا کسی اور کے نکاح میں ہونا۔
نکاح کے مستحبات:
نکاح کے وہ امور جو مسنون اور مستحب ہیں، درج ذیل ہیں:
- نکاح کو سادگی سے انجام دینا: اسراف اور غیر شرعی رسومات سے اجتناب۔
- جمعہ یا شوال میں نکاح کرنا: یہ دن یا مہینہ مبارک سمجھے جاتے ہیں۔
- خطبة النکاح کا پڑھا جانا: نکاح سے پہلے خطبہ دینا سنت ہے جس میں قرآن کی آیات اور تقویٰ کی تلقین شامل ہوتی ہے۔
- دعائے خیر: نکاح کے بعد دلہا اور دلہن کے لیے دعائے خیر کرنا، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
“بارَكَ اللَّهُ لَك، وَبارَكَ عَلَيك، وَجَمَعَ بَينَكُما في خَيرٍ”
(ترجمہ: اللہ تمہارے لیے برکت دے، تم پر برکت نازل فرمائے، اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع کرے۔) - نکاح کا اعلان: نکاح کو خفیہ نہ رکھا جائے بلکہ اعلان کے ساتھ کیا جائے تاکہ فتنہ نہ ہو۔
- ولیمہ: نکاح کے بعد کھانے کا اہتمام کرنا سنت ہے۔
نتیجہ:
نکاح اسلام کا ایک اہم اور بابرکت عمل ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنانے، خاندان قائم رکھنے اور معاشرے کو مستحکم کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ارکان، شرائط اور مستحبات کو جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے تاکہ نکاح شریعت کے مطابق ہو اور زندگی خوشگوار بنے۔
سوال نمبر 4:
رضاعت کا مفہوم تحریر کریں۔ نیز عدت رضاعت فقہاء کی آراء کی روشنی میں بیان کریں۔
رضاعت لغوی طور پر دودھ پینے کے عمل کو کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں “رضاعت” اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں ایک بچہ کسی عورت کا دودھ (ماں کے علاوہ) مقررہ مدت کے اندر پی لے تو اس عورت کے ساتھ اور اس کے بعض رشتہ داروں کے ساتھ وہ بچہ حرمتِ نکاح میں آ جاتا ہے، یعنی وہ رضاعی رشتہ دار بن جاتے ہیں۔
قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
“وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ”
ترجمہ: “تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں۔” (سورۃ النساء: 23)
رضاعت کی شرعی مدت:
رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب بچہ دو سال (ہجری) کی عمر کے اندر اندر دودھ پیے۔
قرآن میں فرمایا گیا:
“وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ”
ترجمہ: “مائیں اپنے بچوں کو دو مکمل سال دودھ پلائیں۔” (سورۃ البقرہ: 233)
فقہاء کی آراء کے مطابق عدتِ رضاعت:
- امام ابو حنیفہ (رح): آپ کے نزدیک اگر بچہ دو سال کی عمر کے اندر پانچ مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں رضاعی ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، بیٹی وغیرہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔
- امام مالک (رح): آپ کے نزدیک بھی رضاعت کی مدت دو سال ہے، لیکن آپ کے نزدیک یہ شرط نہیں کہ پانچ مرتبہ ہو، بلکہ تھوڑی مقدار میں دودھ پینا بھی رضاعت کا سبب بن سکتا ہے، بشرطیکہ دو سال کے اندر ہو۔
- امام شافعی (رح): آپ کے مطابق کم از کم پانچ بار الگ الگ دفعہ دودھ پینا رضاعت ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ہر بار دودھ پینے کے درمیان وقفہ ہو۔
- امام احمد بن حنبل (رح): آپ بھی امام شافعی کی رائے کے قائل ہیں کہ پانچ مرتبہ مکمل دودھ پینا، جس کے درمیان وقفہ ہو، شرط ہے۔
عدتِ رضاعت کا مفہوم:
“عدتِ رضاعت” دراصل اس مدت کو کہا جاتا ہے جس میں بچہ دودھ پینے کے قابل ہو اور رضاعت کے احکام لاگو ہوتے ہوں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت شریعت میں دو سال ہے۔ اس مدت کے بعد اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو وہ رضاعی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔
رضاعت کے اثرات:
رضاعت کے بعد بعض شرعی اثرات مرتب ہوتے ہیں:
- رضاعی ماں، رضاعی بہن، رضاعی خالہ، رضاعی پھوپھی وغیرہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔
- وراثت، نفقہ، اور ولایت کے احکام ثابت نہیں ہوتے۔
- محرمیت قائم ہو جاتی ہے، یعنی پردہ نہیں اور سفر جائز ہے۔
نتیجہ:
رضاعت ایک نہایت اہم شرعی معاملہ ہے جس کا تعلق حرمتِ نکاح اور خاندانی نظام سے ہے۔ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ رضاعت سے محرمیت پیدا ہوتی ہے، البتہ رضاعت کی مقدار اور اس کے اثرات میں فقہی اختلاف موجود ہے۔ لہٰذا رضاعت کے احکام کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا معاشرتی پاکیزگی اور شرعی رہنمائی کے لیے نہایت ضروری ہے۔
سوال نمبر 5:
طلاق کی لغوی و اصطلاحی تعریف بیان کریں نیز طلاقِ سنت، طلاقِ احسن، طلاقِ حسن، طلاقِ رجعی اور طلاقِ بائن کی تعریف اور احکام بیان کریں۔
طلاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ “ط ل ق” ہے، جس کے لغوی معنی “چھوڑنے”، “آزاد کرنے” یا “رشتہ ختم کرنے” کے ہیں۔
طلاق کی اصطلاحی تعریف:
شرعی اصطلاح میں طلاق اُس عقدِ نکاح کو مخصوص الفاظ کے ذریعے ختم کرنے کو کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت میں ایک ناپسندیدہ مگر جائز عمل ہے، جب زوجین کے درمیان نباہ ممکن نہ رہے۔
طلاق کی اقسام اور ان کے احکام:
1. طلاقِ سنت:
یہ وہ طلاق ہے جو سنتِ نبوی اور شریعت کے مطابق دی جاتی ہے۔ اس میں شوہر اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں (جس میں ہمبستری نہ کی ہو) ایک طلاق دیتا ہے اور عدت گزرنے دیتا ہے۔
- صرف ایک طلاق دی جاتی ہے۔
- عدت میں رجوع کا حق ہوتا ہے۔
- یہ طلاق شریعت کے مطابق اور پسندیدہ طریقہ ہے۔
2. طلاقِ احسن:
طلاقِ احسن سنت طلاق ہی کی ایک قسم ہے جسے فقہاء نے سب سے بہتر اور بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔
- بیوی کو ایک طہر (پاکی) میں طلاق دی جاتی ہے اور پھر عدت کے ختم ہونے تک کوئی رجوع یا طلاق نہیں دی جاتی۔
- عدت میں رجوع کی اجازت ہوتی ہے۔
- اگر عدت گزر جائے اور رجوع نہ کیا جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔
3. طلاقِ حسن:
طلاقِ حسن بھی سنت طلاق میں شمار ہوتی ہے مگر احسن سے کم درجے کی ہے۔
- بیوی کو تین طہورات (پاکی کے اوقات) میں تین مرتبہ طلاق دی جاتی ہے، ہر طہر میں ایک طلاق۔
- ہر طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تینوں طلاقیں مکمل ہو جائیں تو رجوع ممکن نہیں۔
4. طلاقِ رجعی:
رجعی طلاق وہ ہے جس میں شوہر نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہوں اور عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہو۔
- عدت کے دوران شوہر زبانی یا عملی رجوع کر سکتا ہے۔
- اگر رجوع کر لیا جائے تو نکاح قائم رہتا ہے۔
- رجعی طلاق کے بعد عدت ختم ہونے پر بھی نیا نکاح کر کے دوبارہ زوجیت قائم کی جا سکتی ہے۔
5. طلاقِ بائن:
بائن کا مطلب ہے “منقطع ہونا”۔ طلاقِ بائن وہ ہے جس کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہوتی، جب تک نیا نکاح نہ ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں: صغریٰ اور کبریٰ۔
- اگر شوہر بیوی کو ایک طلاقِ بائن دے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، مگر دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔
- اگر تین طلاقیں دی جائیں (طلاقِ مغلظہ) تو رجوع یا نکاح دونوں اس وقت تک جائز نہیں جب تک عورت کسی اور مرد سے نکاح کر کے طلاق یافتہ نہ ہو (حلالہ کی شرط)۔
نتیجہ:
طلاق ایک حساس اور سنگین عمل ہے جس کا تعلق خاندان، معاشرت اور دین کے اصولوں سے ہے۔ شریعتِ اسلامیہ نے طلاق کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا تاکہ ناحق ظلم، زیادتی اور جذباتی فیصلے سے بچا جا سکے۔ احسن طریقہ وہی ہے جو سنت اور حکمت کے مطابق ہو، تاکہ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو ضرورتاً اور شائستہ انداز میں ختم کیا جا سکے۔
سوال نمبر 6:
ضلع کا لغوی و اصطلاحی مفہوم تحریر کریں۔ نیز خلع کی شرعی حیثیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔
لفظ “ضِلع” عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی “پہلو، طرف یا کنارہ” کے ہیں۔ اردو میں اس کا استعمال کسی مقام، حد بندی یا انتظامی یونٹ کے لیے ہوتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں “ضلع” کا استعمال کم ہوتا ہے، مگر سوال کا سیاق و سباق دیکھتے ہوئے یہاں اصل مطلوب “خلع” پر توجہ دی گئی ہے۔
خلع کا مفہوم:
لغوی تعریف:
خلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ “خ ل ع” ہے، جس کے معنی “اتارنے” یا “الگ کرنے” کے ہیں۔ جیسے کہ کوئی لباس اتارا جائے۔
اصطلاحی تعریف:
شریعتِ اسلامیہ میں خلع اس نکاح کو کہتے ہیں جو عورت اپنے شوہر سے کسی مالی عوض کے بدلے میں ختم کرواتی ہے۔ یعنی عورت اگر شوہر کی زوجیت سے نکلنا چاہے اور شوہر بغیر طلاق دیے راضی نہ ہو، تو وہ مہر یا کوئی اور مال دے کر نکاح سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔
خلع کی شرعی حیثیت:
خلع شریعتِ محمدی ﷺ میں جائز، معتبر اور معتبر فقہی اصولوں پر مبنی نکاح ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، جسے قرآن و حدیث اور اجماعِ امت سے ثبوت حاصل ہے۔
قرآن سے دلیل:
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (سورۃ البقرہ: 229)
ترجمہ: “پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں (میاں بیوی) اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ معاوضہ دے کر طلاق حاصل کرے۔”
حدیث سے دلیل:
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے نبی کریم ﷺ سے خلع کی درخواست کی، اور فرمایا کہ وہ دینی طور پر کوئی شکایت نہیں رکھتیں، مگر شوہر کو پسند نہیں کرتیں۔ آپ ﷺ نے خلع کی اجازت دی اور فرمایا کہ مہر واپس کر دو۔
فقہاء کے نزدیک خلع:
تمام آئمہ اربعہ (امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ) کے نزدیک خلع جائز ہے، مگر شرائط و احکام میں کچھ جزوی اختلاف پایا جاتا ہے۔
خلع کے اہم نکات:
- خلع میں عورت شوہر سے نکاح ختم کروانے کی درخواست کرتی ہے۔
- یہ علیحدگی عورت کی مرضی سے ہوتی ہے۔
- عورت مہر یا کوئی اور مال دے کر آزادی حاصل کرتی ہے۔
- عدت طلاق کی عدت کے برابر ہوتی ہے (تین حیض یا تین ماہ)۔
- اگر خلع کے بعد رجوع ہو تو نیا نکاح اور مہر لازم ہوگا۔
خلع اور طلاق کا فرق:
- طلاق شوہر دیتا ہے، جبکہ خلع عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔
- طلاق میں شوہر یکطرفہ طور پر نکاح ختم کرتا ہے، جبکہ خلع میں عورت عوض دے کر شوہر سے نکاح ختم کرواتی ہے۔
- خلع میں عدالتی یا باہمی اجازت ضروری ہوتی ہے۔
نتیجہ:
خلع عورت کو وہ حق فراہم کرتا ہے جس سے وہ زبردستی یا غیر موزوں رشتے سے علیحدگی حاصل کر سکے۔ اسلام نے نہ صرف مرد کو طلاق کا اختیار دیا بلکہ عورت کو بھی خلع کے ذریعے اپنی آزادی کا حق دیا، جس سے دینِ اسلام کی عدل و مساوات پر مبنی تعلیمات ظاہر ہوتی ہیں۔
سوال نمبر 7:
عدت کے احکام فقہ اسلامی کی روشنی میں تفصیل تحریر کریں۔ عدت کی اقسام بیان کیجئے۔
عدت عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی “گنتی، شمار، انتظار اور مدت” کے ہیں۔
اصطلاحی تعریف:
فقہ اسلامی کی اصطلاح میں “عدت” اس مخصوص مدت کو کہتے ہیں جو کسی عورت پر شوہر کی وفات یا طلاق کے بعد نکاحِ ثانی سے پہلے انتظار کرنے کے لیے فرض ہوتی ہے، تاکہ حمل کی صورت میں وضاحت ہو جائے اور نسب میں اختلاط نہ ہو۔
عدت کا شرعی حکم:
عدت ایک واجب عمل ہے اور قرآن و سنت سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ عدت کا مقصد نسب کی حفاظت، خاندانی نظام کی بقاء، عورت کے وقار، اور فطری و معاشرتی مصلحتوں کا تحفظ ہے۔
قرآن سے دلیل:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (سورۃ البقرہ: 228)
ترجمہ: “طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں۔”
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (سورۃ البقرہ: 234)
ترجمہ: “اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار مہینے دس دن عدت گزاریں۔”
حدیث سے دلیل:
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہیں طلاقِ بائن ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے عدت پوری کرنے کا حکم فرمایا۔ (صحیح مسلم)
عدت کی اقسام:
عدت مختلف اسباب اور حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے:
- طلاق کی عدت:
اگر عورت کو طلاق ہوئی ہو اور وہ حیض والی ہو:- عدت: تین حیض (اگر حمل نہ ہو)
- اگر حاملہ ہو: بچہ جننے تک
- اگر حیض نہ آتا ہو (مثلاً بہت کم عمر یا عمر رسیدہ ہو): تین مہینے
- وفات کی عدت:
اگر شوہر فوت ہو جائے:- عدت: چار مہینے دس دن
- اگر عورت حاملہ ہو: بچے کی پیدائش تک (چاہے وقت کم یا زیادہ ہو)
- خلع یا فسخ نکاح کی عدت:
- خلع کے بعد عدت: ایک حیض
- فسخ نکاح (مثلاً ولی کا انکار، شرطِ نکاح کی خلاف ورزی وغیرہ) میں بھی ایک حیض
- نکاح کے بعد رخصتی یا ہمبستری نہ ہونے کی صورت میں:
- طلاق یا وفات پر عدت لازم نہیں
عدت کے دوران پابندیاں:
- نکاح کرنا یا نکاح کی بات چیت کرنا حرام ہے۔
- وفات کی عدت میں عورت زیب و زینت، خوشبو، میک اپ، سیر و تفریح، شوہر کے گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنا منع ہے۔
- طلاق کی عدت میں نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے (سوائے طلاقِ بائن کے بعض صورتوں میں)۔
نتیجہ:
عدت نہ صرف ایک شرعی فریضہ ہے بلکہ ایک حکیمانہ نظام کا حصہ ہے جو خاندانی نظام کی بنیادوں کو مستحکم کرتا ہے۔ فقہ اسلامی نے عدت کے احکام میں عورت، بچے اور معاشرے کے حقوق و مفادات کو مد نظر رکھا ہے، جو دین اسلام کے عدل و توازن پر مبنی ہونے کی علامت ہے۔
سوال نمبر 8:
لعان کی تعریف کریں، شرائط اور اس کے تفصیلی احکام تحریر کریں۔ نیز فقہاء کی آرا بھی تحریر کریں۔
لغوی معنی: لعان “لَعْن” سے ماخوذ ہے، جس کے معنی “لعنت کرنا” کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا۔
اصطلاحی تعریف: لعان فقہ اسلامی میں ایک خاص قسم کا حلف ہے جو میاں بیوی کے درمیان اس وقت کیا جاتا ہے جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اس الزام کے ثبوت میں چار گواہ پیش نہ کر سکے۔ اس صورت میں وہ عدالت میں پانچ بار قسم کھاتا ہے اور بیوی بھی پانچ بار جواب میں قسم کھاتی ہے، جس کے بعد ان کے درمیان جدائی (تفریق) ہو جاتی ہے۔
لعان کا شرعی حکم:
لعان قرآن مجید سے ثابت ہے:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ…﴾ (سورۃ النور: 6-9)
ترجمہ: “اور جو لوگ اپنی بیویوں پر (زنا کا) الزام لگائیں اور ان کے پاس (ثبوت کے لیے) گواہ نہ ہوں، سوائے اپنے آپ کے، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہو کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ وہ سچوں میں سے ہے…”
لعان کی شرائط:
لعان کے صحیح ہونے کے لیے درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:
- نکاح صحیح ہو، محض نکاح یا عقد موجود ہو۔
- شوہر بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا حمل کو اپنا نہ مانے۔
- چار گواہ موجود نہ ہوں۔
- عدالت کے روبرو لعان کا عمل مکمل کیا جائے۔
- لعان کرنے والے دونوں عاقل و بالغ ہوں۔
لعان کا طریقہ:
لعان عدالت میں انجام پاتا ہے۔ اس کا طریقہ درج ذیل ہے:
- شوہر چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے: “اللہ کی قسم! میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے۔”
- پانچویں بار کہتا ہے: “اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔”
- بیوی چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہے: “اللہ کی قسم! میرا شوہر جھوٹا ہے۔”
- پانچویں بار کہتی ہے: “اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔”
لعان کے اثرات و احکام:
لعان کے بعد درج ذیل نتائج مرتب ہوتے ہیں:
- شوہر پر حدِ قذف (زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی سزا) نہیں لگتی۔
- شوہر اور بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے (تفریق ابدی ہو جاتی ہے)۔
- دوبارہ نکاح ممکن نہیں رہتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔
- اگر لعان حمل کی نفی کے لیے تھا، تو بچہ شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔
فقہاء کی آراء:
مختلف فقہی مکاتب فکر میں لعان کے متعلق معمولی اختلافات پائے جاتے ہیں:
- امام ابوحنیفہؒ: لعان کے بعد نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، خواہ عورت سچی ہو یا جھوٹی۔ عدت گزارنا لازم ہے۔
- امام مالکؒ: لعان کے بعد تفریق حتمی ہوتی ہے، اور عورت کو مہر نہیں دیا جائے گا اگر لعان کی بنیاد زنا پر ہو۔
- امام شافعیؒ: لعان کے بعد طلاق کے بجائے تفریق ہوگی، اور دوبارہ نکاح ممکن نہیں۔
- امام احمد بن حنبلؒ: لعان کو نکاح کی حرمت کا مستقل ذریعہ مانتے ہیں۔
نتیجہ:
لعان ایک ایسا شرعی نظام ہے جو میاں بیوی کے درمیان شدید الزام کی صورت میں انصاف اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ فقہ اسلامی میں لعان کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے اور فقہاء نے اس کے تمام پہلوؤں کو وضاحت سے بیان کیا ہے تاکہ کسی فریق پر ظلم نہ ہو۔
سوال نمبر 9:
مندرجہ ذیل کی مختصر وضاحت کریں۔ 1۔ ایلا و یا ایلاء کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ 2۔ ظہار یا ظہار کسے کہتے ہیں؟
ایلا ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے “کسی چیز سے باز رہنا” یا “کسی چیز کا ترک کرنا”۔ شرعی طور پر ایلا اس حالت کو کہتے ہیں جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کے دوران جنس سے چار ماہ یا زیادہ کے لیے تعلق قائم کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہ عمل عموماً شوہر کی طرف سے طلاق دینے سے پہلے بیوی سے دوری کے لیے ہوتا ہے تاکہ شوہر بیوی سے مکمل دوری اختیار کر کے طلاق کی مدت کو پورا کرے یا اس حوالے سے فیصلہ کرے۔
فقہ میں ایلا کے احکام:
– ایلا کا عمل صرف وہی شوہر کر سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نکاح میں ہو۔
– اگر شوہر چار مہینے تک ایلا کرتا رہے تو بیوی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں درخواست دے کر شوہر کو ایلا سے روکنے کا حکم دلائے یا نکاح ختم کرے۔
– ایلا کے دوران شوہر کی جانب سے بیوی کو نکاح کا حق تسلیم کرنا باقی رہتا ہے۔
2۔ ظہار یا ظہار کی تعریف:
ظہار ایک ایسا عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں “ظاہر کرنا” یا “ظاہر کر دینا”۔ شرعی اصطلاح میں ظہار وہ حالت ہے جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں یا کسی قریبی رشتہ دار سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے حرام ہے، جیسے کہ ماں۔ یہ ایک قسم کا طلاق کے بغیر بیوی سے نفرت یا دوری کا اظہار ہوتا ہے جو اسلام میں ناجائز اور ممنوع ہے۔
ظہار کے شرعی احکام:
– ظہار ایک قسم کی گناہ اور ظلم ہے، جسے قرآن نے سختی سے ممنوع قرار دیا ہے (سورۃ المجادلہ، آیت 2-4)۔
– ظہار کے بعد شوہر پر کفارہ فرض ہوتا ہے، جو کہ ایک غلام کی آزادگی، یا روزے رکھنے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔
– اگر شوہر کفارہ ادا کیے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے تو وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔
– ظہار کے باعث نکاح ختم نہیں ہوتا بلکہ شوہر کو کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنی بیوی سے رابطہ قائم کر سکے۔
نتیجہ:
ایلا اور ظہار دونوں شرعی اصطلاحات ہیں جو شوہر اور بیوی کے تعلقات میں مسائل اور حدود کے تعین کے لیے ہیں۔ ایلا طلاق سے قبل تعلق سے باز رہنے کا عمل ہے جبکہ ظہار ایک ناجائز تشبیہ ہے جس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔
سوال نمبر 10:
ایلاء کی تعریف، شرائط اور اس کے تفصیلی احکام تحریر کریں۔ نیز فقہاء کی فقہی آراء بھی تحریر کریں۔
ایلاء ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے “کسی چیز سے باز رہنا” یا “مخالفت کرنا”۔ شرعی اصطلاح میں ایلاء کا مطلب ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق سے چار ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے باز رہے، یعنی نکاح کے دوران اپنی بیوی سے مباشرت سے انکار کرے۔ یہ ایک شرعی حق ہے جو شوہر کو دیا گیا ہے تاکہ وہ طلاق دینے سے قبل بیوی سے فاصلہ اختیار کر سکے۔
ایلاء کی شرائط:
1. شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح شرعی طور پر قائم ہو۔
2. شوہر چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت تک مباشرت سے باز رہے۔
3. ایلاء جان بوجھ کر اور ارادی طور پر کیا جائے، نہ کہ کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے۔
4. ایلاء کا مقصد بیوی کو تکلیف دینا یا طلاق کی تیاری کرنا ہو۔
ایلاء کے فقہی احکام:
– اگر شوہر چار ماہ تک اپنی بیوی سے مباشرت سے باز رہے تو بیوی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں درخواست دے کر شوہر کو مباشرت کرنے پر مجبور کرے یا نکاح کو ختم کروائے۔
– اگر شوہر ایلاء کے بعد طلاق دے تو اسے “طلاق ایلاء” کہا جاتا ہے اور یہ طلاق رجعی شمار ہوتی ہے، یعنی شوہر عدت کے دوران بیوی کو واپس بلا سکتا ہے۔
– ایلاء کے دوران بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ اپنی نفقہ، رہائش، اور دیگر شرعی حقوق کی مستحق رہتی ہے۔
– اگر ایلاء غیر ارادی ہو، مثلاً شوہر بیمار ہو یا دور ہو، تو اس کا شرعی اثر مختلف ہو سکتا ہے اور عدالت کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے۔
فقہاء کی آراء:
– امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایلاء کا عمل جائز ہے لیکن بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور بیوی کو چار ماہ سے زیادہ بلا وجہ ایلا کرنا ناجائز ہے۔
– امام مالک رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ ایلاء جائز ہے لیکن اگر چار ماہ مکمل ہو جائیں تو بیوی کو قانونی مدد حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔
– امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ایلاء کو محدود مدت کے لیے جائز قرار دیا ہے تاکہ شوہر اور بیوی کے درمیان مسائل کو حل کیا جا سکے۔
– امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایلاء کو جائز تسلیم کیا لیکن اس کی زیادتی اور بیوی کو نقصان پہنچانے پر سختی سے منع کیا۔
نتیجہ:
ایلاء ایک شرعی حق ہے جو شوہر کو دیا گیا ہے تاکہ وہ نکاح کے دوران بیوی سے جنسی تعلق سے عارضی طور پر باز رہ سکے۔ اس کا مقصد طلاق یا تعلق کی صورت حال کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ فقہاء نے اس کا جائزہ لیا ہے اور چار ماہ کی حد مقرر کی ہے تاکہ بیوی کے حقوق محفوظ رہیں۔ اگر ایلاء کا دورانیہ چار ماہ سے تجاوز کرے تو بیوی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے تاکہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے۔
سوال نمبر 11:
قضاء کی ضرورت و اہمیت اور فراہمی عدل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک جامع مضمون تحریر کریں۔
قضاء کی ضرورت و اہمیت:
قضاء کا لفظ عربی زبان سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے “فیصلہ کرنا” یا “حکم صادر کرنا”۔ شرعی اصطلاح میں قضاء کا مطلب ہے عدالتی نظام جو معاشرے میں انصاف فراہم کرتا ہے اور اختلافات کو حل کرتا ہے۔ قضاء ایک ایسا نظام ہے جو انسانی معاشرے کی بقا، امن اور استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بغیر قضاء کے معاشرہ قانون، انصاف، اور حق و باطل کے درمیان تمیز کھو دیتا ہے جس سے ظلم و ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔
قضاء کی ضرورت:
- انسانی فطرت میں اختلاف رائے اور تنازعات کا وجود ہمیشہ رہتا ہے، جنہیں حل کرنے کے لیے ایک منصفانہ نظام قضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔
- قضاء معاشرتی انصاف کا ضامن ہوتا ہے جو حقوق الناس کی حفاظت کرتا ہے اور ظلم کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔
- قضاء کے ذریعے قانون کی حکمرانی قائم ہوتی ہے اور ہر فرد کو اس کا حق ملتا ہے۔
- قضاء انسانوں کے درمیان امن قائم رکھنے اور عدل کی فراہمی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔
قرآن و حدیث میں قضاء کی اہمیت:
قرآن و حدیث میں قضاء اور عدل کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے:
-
قرآن: اللہ تعالیٰ نے قضاء کو عدل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
“إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ الْأَمَانٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ…”
(سورۃ النساء: 58)
یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حق داروں کو دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ -
حدیث: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
“میں قاضی ہوں، اور میں عدالت کا حق ادا کروں گا۔”
یہ حدیث عدل و انصاف کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور قاضی کی ذمہ داری کو بیان کرتی ہے۔ -
نبی ﷺ نے فرمایا:
“الْقَاضِي الْعَدْلُ عِنْدَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ مِثْلُ النَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ.”
یعنی عدل کرنے والا قاضی اللہ کے ہاں منبر پر نبی کی مانند مقام رکھتا ہے۔
قضاء کی فراہمی میں عدل:
عدل قضاء کا بنیادی جزو ہے۔ قاضی کا کام صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ عدل کا مطلب ہے ہر شخص کو اس کا حق دینا، بغض و عناد کے بغیر فیصلے کرنا، اور ہر قسم کے تعصب سے پاک ہونا۔ اسلام نے عدل کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ اسے خدا کے قریب ترین عمل قرار دیا ہے۔
نتیجہ:
قضاء ایک ایسا نظام ہے جو انسانی معاشرے کو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ قضاء کی فراہمی اور عدل کے قیام سے ہی معاشرہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عدل کا مظاہرہ کرے تاکہ معاشرہ ظلم و ناانصافی سے محفوظ رہے اور امن قائم ہو۔
سوال نمبر 12:
راہزنی کی تعریف اور اقسام بیان کریں۔ نیز جرم حرابہ کی اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔
راہزنی کی تعریف:
راہزنی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے راستے میں لوٹ مار کرنا یا مسافروں کو ڈرانا دھمکانا اور ان سے مال و اسباب چھیننا۔ فقہ اسلامی میں راہزنی کو ‘حرابہ’ کا نام دیا گیا ہے جو ایک سنگین جرم ہے۔ حرابہ سے مراد وہ جرم ہے جس میں کوئی شخص یا گروہ مسلح ہو کر دوسرے لوگوں کے مال و جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، راستے میں روکتا ہے، لوٹتا ہے، اور معاشرتی امن کو نقصان پہنچاتا ہے۔
راہزنی کی اقسام:
- مسافر کی راہزنی: مسافروں کو راستے میں روک کر ان کے مال و اسباب لوٹنا۔
- کاروباری مال کی چوری: تجارتی سامان یا قافلوں کو مسلح افراد کا نشانہ بنانا۔
- گاؤں یا بستی پر حملہ: کسی آبادی یا بستی کو لوٹنا، جلانا یا برباد کرنا۔
- ذاتی حملہ: افراد کو زخمی یا قتل کرنا تاکہ ان کے مال کو قبضہ میں لیا جا سکے۔
جرم حرابہ کی اسلام میں اہمیت:
اسلام میں حرابہ کو انتہائی سنگین جرم تصور کیا گیا ہے کیونکہ یہ معاشرتی امن اور سلامتی کو شدید خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ حرابہ کا ارتکاب نہ صرف فرد کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنا ہے بلکہ پورے معاشرے میں خوف و دہشت پھیلانا ہے۔ اس لیے اسلام نے حرابہ کے مجرمین کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر کی ہیں تاکہ معاشرہ محفوظ اور پرامن رہے۔
حرابہ کی سزائیں:
حرابہ کے مجرمین کے لیے قرآن و حدیث میں متعدد سزائیں بیان کی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں:
- قتل: اگر حرابہ کرنے والا قتل کرتا ہے یا جان کا خطرہ پہنچاتا ہے تو اسے سخت سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے۔
- کٹائی (ہاتھ پاؤں کاٹنا): اگر مجرم لوٹ مار کرتا ہے مگر قتل نہیں کرتا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا حکم ہے۔
- بستی یا علاقے سے نکالنا: بعض صورتوں میں مجرم کو معاشرت سے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید نقصان نہ پہنچا سکے۔
- سزا کا امتزاج: بعض حالات میں یہ سزائیں مل کر دی جاتی ہیں، مثلاً قتل کے ساتھ ساتھ اعضا کاٹنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔
قرآنی آیات میں حرابہ کی سزا:
اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا:
“إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…”
یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا صلیب پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف کاٹے جائیں یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ سخت سزائیں حرابہ کے مجرمین کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔
فقہاء کے نظریات:
فقہاء کرام نے حرابہ کی سزاؤں پر مختلف تفصیلات بیان کی ہیں:
- امام ابو حنیفہ: حرابہ کی سزا قتل، ہاتھ پاؤں کاٹنا، یا معزول کرنا سمجھتے ہیں، مجرم کی حالت اور جرم کی شدت کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔
- امام مالک: سخت سزا کے حق میں تھے تاکہ معاشرت میں امن قائم رہے اور مجرم کو عبرت دی جا سکے۔
- امام شافعی: سزاؤں کے اطلاق میں سختی رکھتے تھے لیکن حالت مجرم، نیت، اور جرائم کی نوعیت کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔
- امام احمد بن حنبل: مجرمین کو سخت سزائیں دینے کے حامی تھے تاکہ حرابہ کا خاتمہ ہو اور معاشرہ محفوظ رہے۔
نتیجہ:
حرابہ یعنی راہزنی ایک سنگین جرم ہے جو معاشرتی امن کو تباہ کرتا ہے۔ اسلام نے اس جرم کی روک تھام کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر کی ہیں تاکہ نہ صرف مجرموں کو عبرت ملے بلکہ دوسروں میں بھی خوف پیدا ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حرابہ کی سزا قتل، اعضا کاٹنا، معزول کرنا یا معاشرت سے نکالنا ہے۔ فقہاء نے بھی اس میں اتفاق کیا ہے کہ یہ سزائیں معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں۔ اس طرح اسلام نے اپنے معاشرتی نظام کو محفوظ اور منظم رکھنے کی بھرپور تدابیر اختیار کی ہیں۔
سوال نمبر 13:
قصاص سے کیا مراد ہے؟ قتل کی اقسام پر فقہ اسلامی کے احکامات کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔
قصاص کی تعریف:
قصاص عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے “ایسا ہی بدلہ لینا” یا “مثل کا بدلہ”۔ فقہ اسلامی میں قصاص کا مفہوم ہے جان یا عضو کے قصاص کا حق، یعنی کسی قتل یا جسمانی نقصان کی صورت میں مجرم کو اسی قسم کی سزا دینا جسے اس نے انجام دیا ہو۔ قصاص کا مقصد معاشرتی انصاف کا قیام اور مظلوم کے حقوق کی حفاظت ہے۔
قتل کی اقسام اور فقہ اسلامی کے احکامات:
-
قتل عمد (سوچا سمجھا قتل):
یہ وہ قتل ہے جو جان بوجھ کر اور ارادے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں قصاص کا حق مقتول کے ورثاء کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے:
“وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” (البقرة: 179)
ایسے قتل میں مقتول کے وارث قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا معافی دے سکتے ہیں جس پر دیت کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے۔ - قتل خطاء (غلطی سے قتل): یہ قتل غیر ارادی ہوتا ہے، جیسے حادثاتی قتل۔ اس میں قصاص کا حق نہیں ہوتا بلکہ مقتول کے وارثوں کو دیہ یا معافی کی پیشکش کی جاتی ہے۔
- قتل شبه عمد (غیر ارادی لیکن لاپرواہی کے ساتھ): یہ قتل ایسے ہوتا ہے جس میں کوئی شخص کسی کی جان لیتا ہے مگر اس کا ارادہ قتل کا نہیں ہوتا، جیسے لاپرواہی یا غفلت سے۔ اس میں بھی دیت یا معافی کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔
فقہ اسلامی کے احکامات:
- قصاص کا فیصلہ عدالت کے ذریعے ہوتا ہے جہاں ثبوت اور شواہد کی روشنی میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔
- مقتول کے ورثاء قصاص سے معافی دے کر دیت لے سکتے ہیں، جس سے خون کی لڑائی اور فساد سے بچا جا سکتا ہے۔
- دیت کی رقم معاشرت اور وقت کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس کی ایک معیاری حد مقرر ہے۔
- قصاص کا مقصد انتقام نہیں بلکہ عدل اور مساوات کا قیام ہے تاکہ معاشرہ منظم اور پرامن رہے۔
- اسلام میں جان لینا بہت سنجیدہ جرم ہے، اور قصاص کی سزا اسے روکنے کا ذریعہ ہے۔
نتیجہ:
قصاص اسلام میں عدل و انصاف کا اہم جزو ہے جو قاتل کو اس کے جرم کے مطابق سزا دیتا ہے۔ قتل کی مختلف اقسام کے مطابق فقہ اسلامی نے مناسب احکامات دیے ہیں تاکہ معاشرتی امن قائم رہے اور مظلوم کے حقوق محفوظ ہوں۔
سوال نمبر 14:
جرم زنا کی تعریف کریں اور اس کے ارتکاب کی صورت میں فقہ اسلامی میں موجود اس کی سزا بیان کریں۔
زنا کی تعریف:
زنا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غیر شرعی جنسی تعلق قائم کرنا، یعنی نکاح کے بغیر یا نکاح کے بعد ممنوعہ طریقے سے جنسی فعل انجام دینا۔ فقہ اسلامی میں زنا کو ایک سنگین گناہ اور جرم تصور کیا جاتا ہے جو اسلام کی اخلاقی اور معاشرتی حدود کی خلاف ورزی ہے۔
زنا کے ارتکاب کی صورتیں:
- نکاح کے بغیر جنسی تعلق قائم کرنا۔
- ممنوعہ رشتہ داروں کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا۔
- میاں بیوی میں سے کسی کا دوسرے سے زنا کرنا۔
فقہ اسلامی میں زنا کی سزائیں:
اسلام نے زنا کے مرتکب افراد کے لیے سخت سزائیں مقرر کی ہیں تاکہ معاشرت میں پاکیزگی اور امن قائم رہے۔
- سزا حد: اگر زنا ثابت ہو جائے تو اسلام میں درج ذیل سزائیں دی جاتی ہیں:
- لڑکی یا غیر شادی شدہ عورت کا زنا: سو کوڑے مارے جائیں۔ (سورۃ النور، آیت ۲)
- شادی شدہ مرد و عورت کا زنا: سنگسار کیا جائے۔
- سزا تعزیر: اگر ثبوت مکمل نہ ہو یا شک کی صورت ہو تو قاضی تعزیر کی سزا دے سکتا ہے جو قیدی کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔
زنا کے ثبوت:
زنا کے ثبوت کے لیے چار عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو ایک وقت میں عینی شاہد ہوں کہ انہوں نے زنا کی حالت دیکھی ہو۔ یا متاثرہ فریق خود زنا کا اعتراف کرے۔ بغیر ثبوت کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔
زنا کی سماجی اور دینی اہمیت:
زنا نہ صرف فرد کا گناہ ہے بلکہ یہ معاشرتی اخلاقیات اور خاندانی نظام کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے زنا کی سخت ممانعت کر کے معاشرہ کو فساد اور بے حیائی سے بچانے کی کوشش کی ہے۔
نتیجہ:
زنا ایک سنگین جرم ہے جس کی اسلام میں سخت سزائیں مقرر ہیں تاکہ معاشرتی پاکیزگی قائم رہے اور لوگ اخلاقی دائرے میں رہیں۔ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی نے واضح اصول بنائے ہیں جو اس جرم کے ارتکاب کو روکنے کے لیے ہیں۔
سوال نمبر 15:
سرقہ کا مفہوم اور نصاب، سرقہ کی اقسام اور سزائیں تفصیل سے تحریر کریں۔
سرقہ کا مفہوم:
سرقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چوری۔ فقہ اسلامی میں سرقہ سے مراد غیر اجازت کے کسی دوسرے کی ملکیت میں موجود چیز کو چھپ کر یا زبردستی لے لینا ہے، جس سے مالک کو نقصان پہنچے۔ سرقہ ایک بڑا گناہ اور جرم سمجھا جاتا ہے جو معاشرتی امن و امان کو خراب کرتا ہے۔
سرقہ کا نصاب:
سرقہ کی حد کی سزا کے لیے جو چیز چوری کی جائے اس کا نصاب مقرر ہے۔ نصاب سے مراد وہ مخصوص مقدار اور قیمت ہے جس کے نیچے چوری پر حد کی سزا نہیں ہوتی۔ نصاب کی شرائط مختلف فقہی مذاہب میں قدرے فرق رکھتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ درج ذیل ہیں:
- چوری کی گئی چیز قابلِ خرید و فروخت ہو۔
- چوری کی گئی چیز کی قیمت نصاب یعنی حدود کی مقدار سے زیادہ ہو۔
- چوری کی گئی چیز بغیر مالک کی اجازت لی گئی ہو۔
- چوری کے وقت چور بالغ، عاقل، اور مجنون نہ ہو۔
مثلاً، مالِ سرقہ اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو نصاب تقریباً ساڑھے سات تولے سونا (یا اس کی قیمت) ہوتا ہے اور اگر غیر کھانے پینے کی چیز ہے تو نصاب کچھ کم ہو سکتا ہے۔
سرقہ کی اقسام:
- سرقہ جلی: چوری کھلے عام اور زور زبردستی سے کی جائے، جیسے دھمکی دے کر مال لینا۔
- سرقہ خفی: چوری چپکے سے کی جائے، بغیر کسی کو معلوم ہوئے۔
- سرقہ نقل: چوری کرتے ہوئے کسی اور کے مال کو بھی بغیر اجازت لے جانا۔
سرقہ کی سزائیں:
فقہ اسلامی میں سرقہ کے لیے سخت اور واضح سزائیں مقرر کی گئی ہیں تاکہ چوری کو روک کر معاشرتی امن و عدل قائم رکھا جا سکے۔
- حد کی سزا: اگر سرقہ کی تمام شرائط پورے ہوں تو سرقہ کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ سزا قرآن مجید میں واضح ہے:
“وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ…” (المائدة: 38) - تعزیر کی سزا: اگر نصاب پورا نہ ہو یا کوئی شرط پوری نہ ہو تو قاضی سرقہ کرنے والے کو تعزیر کی سزا دے سکتا ہے جو قید یا جرمانہ ہو سکتی ہے۔
- معافی اور توبہ: اگر سرقہ کرنے والا معافی مانگے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور توبہ کی صورت میں سزا سے چھوٹ ممکن ہے۔
نتیجہ:
سرقہ اسلام میں ایک سنگین جرم ہے جس سے معاشرتی نظام بگڑتا ہے۔ نصاب اور شرائط کے تحت مقرر کردہ سخت سزائیں چوری کی روک تھام کے لیے ہیں۔ فقہ اسلامی میں اس پر مکمل غور و فکر کے بعد حدود اور تعزیرات مقرر کی گئی ہیں تاکہ معاشرہ محفوظ اور منظم رہے۔
سوال نمبر 16:
قومی سلامتی کیخلاف جرائم کی نشاندہی اور ان کی سزائیں تحریر کریں۔
قومی سلامتی کیخلاف جرائم کی تعریف:
قومی سلامتی کیخلاف جرائم سے مراد وہ تمام ایسے جرائم ہیں جو کسی ملک کی خودمختاری، سالمیت، یا داخلی امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ جرائم ملک کے خلاف سازش، دہشت گردی، جاسوسی، بغاوت اور دیگر ایسے افعال شامل ہیں جو قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں۔
قومی سلامتی کیخلاف اہم جرائم کی نشاندہی:
- دہشت گردی: عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، دھماکے، ہتھیاروں کا استعمال، سیاسی یا مذہبی تنظیموں کی طرف سے ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانا۔
- جاسوسی: دشمن ملکوں کے لیے خفیہ معلومات حاصل کرنا یا ملک کی سکیورٹی سے متعلق راز دشمن کے سپرد کرنا۔
- بغاوت و فوجی بغاوت: مسلح افواج یا عوام کی جانب سے حکومت کو غیر قانونی طریقے سے بدلنے کی کوشش۔
- سازش برائے ریاست کا تختہ الٹنا: حکومت کی قانونی کارکردگی کو ختم کرنے کے لیے خفیہ یا کھلی سازش کرنا۔
- ملکی حدود کی خلاف ورزی: سرحدوں کی خلاف ورزی یا ملک کی سرزمین پر غیر قانونی قبضہ یا تجاوزات۔
- غداری: ملک کے خلاف دشمن کی مدد کرنا یا وطن کے خلاف کام کرنا۔
قومی سلامتی کیخلاف جرائم کی سزائیں:
ان جرائم کے لیے مختلف قوانین میں سخت سزائیں مقرر ہیں تاکہ ملک کی سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے:
- موت کی سزا: دہشت گردی، غداری، یا بغاوت کے مرتکب افراد کو قانونی طور پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔
- قید کی سزائیں: ان جرائم میں ملوث افراد کو عمر قید یا مقررہ مدت کی قید بھی ہو سکتی ہے۔
- جرمانے: مالی جرمانے اور دیگر مالی پابندیاں بھی عائد کی جاتی ہیں۔
- ملک بدری: بعض صورتوں میں مجرم کو ملک سے نکالنے کی سزا بھی دی جاتی ہے۔
- دیگر تعزیری سزائیں: جیسے قید کی مدت میں کمی یا اضافے، حفاظتی اقدامات اور نگرانی۔
قومی قوانین اور قوانینِ دہشت گردی:
پاکستان میں مختلف قوانین جیسے “Anti-Terrorism Act” اور “Official Secrets Act” کے تحت ان جرائم کو سختی سے روکا اور سزا دی جاتی ہے۔ عدالتیں اور خصوصی ٹربیونلز بھی ان کیسز میں کام کرتے ہیں تاکہ قومی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
نتیجہ:
قومی سلامتی کیخلاف جرائم نہ صرف ملک بلکہ اس کے عوام کی فلاح و بہبود کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ ان جرائم کی روک تھام کے لیے سخت قوانین اور سزائیں ناگزیر ہیں تاکہ پاکستان میں امن، استحکام اور ترقی ممکن ہو سکے۔
سوال نمبر 17:
قاضی کے اوصاف کے بارے میں فقہاء کرام کی آراء بیان کریں۔
قاضی کے اوصاف کی اہمیت:
اسلامی فقہ میں قاضی کا کردار عدل و انصاف قائم کرنے اور شرعی احکام کے مطابق مسائل کو حل کرنے کا ہے۔ ایک قاضی کی صلاحیت اور کردار معاشرتی نظام کی درستگی اور عدلیہ کی ساکھ کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے قاضی کے لئے خاص اوصاف وضع کیے ہیں جو عدل، علم، اور تقویٰ پر مبنی ہوں۔
فقہاء کی آراء اور قاضی کے بنیادی اوصاف:
- علم اور فہم: قاضی کو فقہ و شرعی علوم پر مکمل عبور حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مسائل کا درست اور منصفانہ حل نکال سکے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے اس پر زور دیا کہ قاضی کو شریعت کا ماہر ہونا چاہیے۔
- عدل و انصاف: قاضی کو مکمل عدل و انصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ اس کا فیصلہ بغیر کسی تعصب یا ذاتی مفاد کے ہونا چاہیے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ عدل قاضی کی بنیادی صفت ہے۔
- تقویٰ اور پرہیزگاری: قاضی کو اللہ سے خوف رکھنے والا، گناہوں سے بچنے والا اور تقویٰ والا ہونا چاہیے تاکہ اس کے فیصلے اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ امام مالک اور دیگر فقہاء نے تقویٰ کو قاضی کی شرط قرار دیا ہے۔
- دیانتداری اور امانت: قاضی کو ہر لحاظ سے دیانتدار، سچا اور امانت دار ہونا چاہیے تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے اور فیصلے میں جھوٹ یا غلط بیانی شامل نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ نے دیانت کو بہت اہم قرار دیا ہے۔
- صبر و تحمل: قاضی کو صبر کرنے والا اور تحمل سے کام لینے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ معاملہ کو جلد بازی کے بغیر سمجھ کر فیصلہ کرے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی صبر کو قاضی کی اہم صفت بتایا ہے۔
- عصمت: قاضی کی زندگی میں بدعنوانی، فحاشی یا ایسے اعمال سے پاکیزگی ضروری ہے تاکہ اس کی شخصیت پر کوئی سوال نہ اٹھے۔
- ذہانت اور حکمت: قاضی کو معاملات کو سمجھنے اور ان میں حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے۔
فقہاء کی تفصیلی آراء:
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی زندگی میں دینی اور دنیوی دونوں طرح کی صلاحیتیں ہونی چاہئیں تاکہ وہ عدالت میں مناسب انداز میں کام کر سکے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ قاضی کی تقویٰ اور ایمان کو کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی نے کہا کہ اگر قاضی میں عدل نہ ہو تو عدالت کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی قاضی کی تقویٰ اور عدل کو عدالت کی بنیاد قرار دیا ہے۔
نتیجہ:
قاضی کے اوصاف کی تکمیل سے ہی ایک منصفانہ اور موثر نظام عدل قائم ہو سکتا ہے جو معاشرہ میں امن، انصاف اور شریعت کی حکمرانی کو یقینی بنائے گا۔ فقہاء کی آراء کے مطابق قاضی کا علم، عدل، تقویٰ، دیانتداری اور صبر وہ ستون ہیں جن پر اس کا کردار استوار ہوتا ہے۔