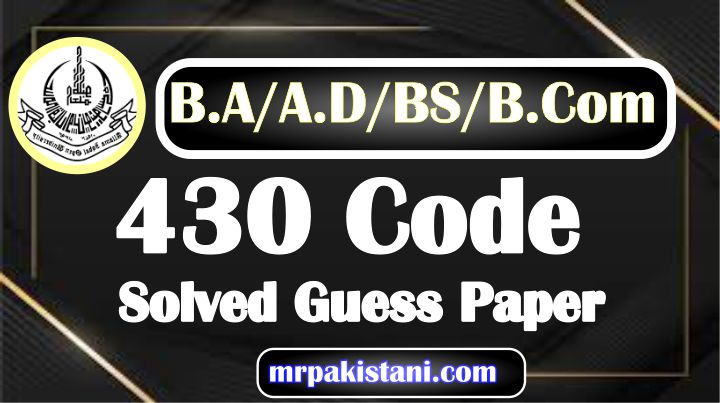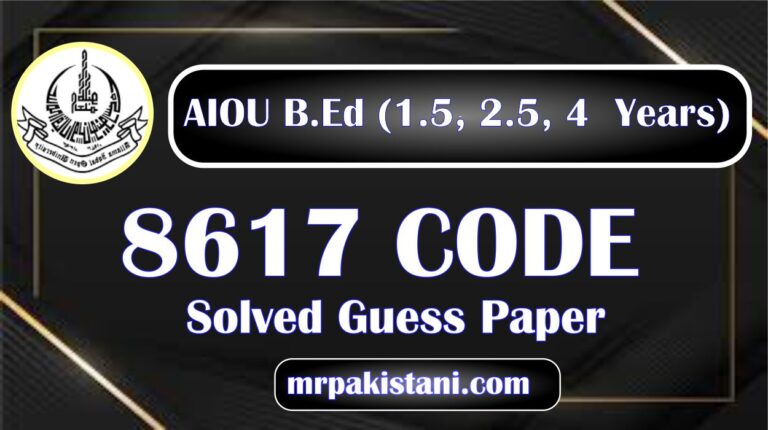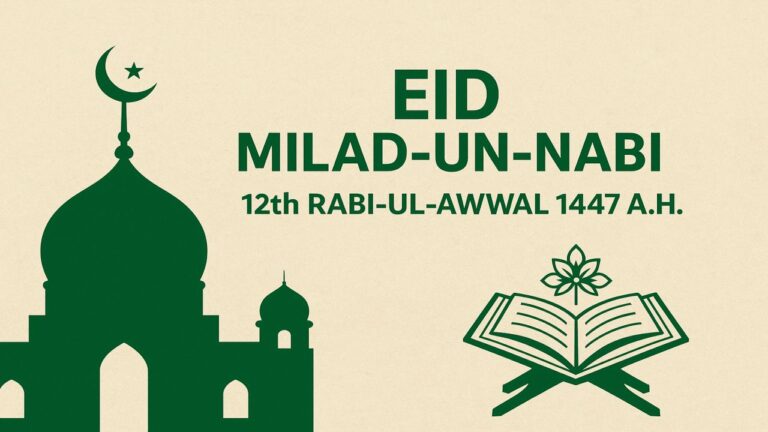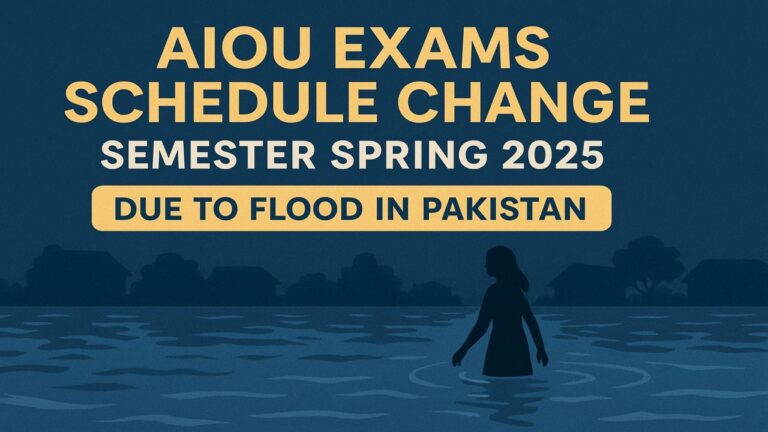AIOU 430 Code Solved Guess Paper – Principle of Journalism
If you are enrolled in AIOU Course Code 430 (Principle of Journalism), our solved guess paper is the perfect study aid for your exam preparation. It includes the most important solved questions, summaries, and exam-focused material carefully selected from past papers and the syllabus. This guess paper will not only save your time but also help you concentrate on the essential topics of journalism. You can easily get the AIOU 430 Solved Guess Paper from our website mrpakistani.com and watch related video lectures on our YouTube channel Asif Brain Academy
430 Code Principle of Journalism Solved Guess Paper
سوال نمبر 1:
صحافت سے کیا مراد ہے؟ صحافت کے مختلف نظریات کی روشنی میں اس کے فرائض و مقاصد پر بحث کریں۔
صحافت سے مراد:
صحافت ایک ایسا سماجی اور فکری عمل ہے جس کے ذریعے معلومات، خبروں، تجزیات اور تبصروں کو عوام تک منظم انداز میں
پہنچایا جاتا ہے۔ یہ معاشرتی شعور بیدار کرنے، عوامی رائے قائم کرنے اور سچائی کو عام کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔
صحافت دراصل “خبر کی تلاش اور ترسیل” کا نام ہے، مگر جدید دور میں یہ صرف خبر تک محدود نہیں بلکہ تعلیم، تربیت،
رہنمائی اور تفریح کا بھی موثر ذریعہ ہے۔
صحافت کے مختلف نظریات:
- آمرانہ نظریہ:
اس نظریے کے مطابق صحافت ریاست کے تابع ہوتی ہے۔ اخبارات و ذرائع ابلاغ حکومت کے مقاصد کے مطابق چلائے جاتے ہیں اور آزادانہ رائے کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ - آزاد صحافت کا نظریہ:
یہ نظریہ آزادی اظہار پر مبنی ہے۔ اس کے مطابق صحافی حقائق کو کھلے انداز میں پیش کرتے ہیں اور ریاستی دباؤ سے آزاد رہ کر عوام کو سچائی پہنچاتے ہیں۔ - سماجی ذمہ داری کا نظریہ:
اس نظریے میں صحافت کو نہ صرف آزاد بلکہ ذمہ دار بھی ہونا چاہیے۔ خبر نشر کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اقدار اور اخلاقی پہلوؤں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ - ترقیاتی نظریہ:
اس نظریے کے مطابق صحافت کا مقصد پسماندہ معاشروں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ اخبارات و ذرائع ابلاغ تعلیمی و معاشی ترقی کے فروغ میں کردار ادا کرتے ہیں۔ - انقلابی نظریہ:
اس کے مطابق صحافت کا مقصد کسی معاشرے میں تبدیلی، انقلاب اور جدوجہد کو فروغ دینا ہے تاکہ عوامی مسائل کو اجاگر کیا جا سکے۔
صحافت کے فرائض و مقاصد:
- حقائق کی درست اور بروقت ترسیل۔
- عوامی شعور کو بیدار کرنا اور تعلیم و تربیت فراہم کرنا۔
- معاشرتی برائیوں کو بے نقاب کرنا اور اصلاحی کردار ادا کرنا۔
- ریاست اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ بننا۔
- تفریح اور ذوقی تسکین کا سامان فراہم کرنا۔
- قومی وحدت اور یکجہتی کو فروغ دینا۔
- معاشرتی انصاف، آزادی اظہار اور جمہوری اقدار کو مضبوط بنانا۔
نتیجہ:
صحافت ایک ذمہ دارانہ فریضہ ہے جو محض خبروں کی ترسیل تک محدود نہیں بلکہ سماجی شعور، قومی ترقی اور عوامی رائے کی
تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مختلف نظریات کی روشنی میں صحافت کے بنیادی فرائض سچائی کی ترویج، عوامی خدمت اور
معاشرتی اصلاح ہیں۔
سوال نمبر 2:
انٹرویو سے کیا مراد ہے؟ اس کے مقاصد، طریقہ کار اور اقسام بیان کریں۔
انٹرویو سے مراد:
انٹرویو ایک ایسا باقاعدہ اور منظم عمل ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان بالمشافہ گفتگو ہوتی ہے تاکہ
مخصوص معلومات حاصل کی جا سکیں۔ صحافت کے میدان میں انٹرویو خبر کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کسی شخصیت
کے خیالات، نظریات اور تجربات براہِ راست عوام تک پہنچائے جاتے ہیں۔ انٹرویو تحقیق، ابلاغ اور صحافتی مقاصد کے لیے
سب سے زیادہ قابلِ اعتماد طریقہ سمجھا جاتا ہے۔
انٹرویو کے مقاصد:
- حقیقی اور براہِ راست معلومات حاصل کرنا۔
- کسی شخصیت کے خیالات، احساسات اور نظریات کو عوام تک پہنچانا۔
- خبروں اور رپورٹس میں صداقت اور توازن قائم رکھنا۔
- کسی موضوع پر مختلف نقطۂ نظر پیش کرنا۔
- عوامی رائے کو متاثر کرنا اور رہنمائی فراہم کرنا۔
- کسی خاص مسئلے پر تحقیق اور گہرائی سے تجزیہ کرنا۔
انٹرویو کا طریقہ کار:
- منصوبہ بندی:
انٹرویو سے پہلے موضوع کا انتخاب، سوالات کی تیاری اور وقت کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ - رابطہ اور تیاری:
انٹرویو دینے والے شخص سے وقت لینا اور گفتگو کے لیے موزوں ماحول کا انتخاب کرنا۔ - انٹرویو کا آغاز:
خوشگوار انداز میں تعارف اور ماحول کو دوستانہ بنانا تاکہ فرد آسانی سے بات کر سکے۔ - سوال و جواب:
سوالات ترتیب سے پوچھے جائیں، غیر ضروری طوالت یا دباؤ سے گریز کیا جائے اور گفتگو کو موضوع تک محدود رکھا جائے۔ - اختتام:
انٹرویو مکمل ہونے پر شکریہ ادا کیا جائے اور اہم نکات کی تصدیق کر لی جائے۔ - تحریر و اشاعت:
حاصل شدہ معلومات کو ترتیب دے کر صحافتی اصولوں کے مطابق شائع کیا جائے۔
انٹرویو کی اقسام:
- خبری انٹرویو:
کسی فوری خبر یا واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ - تحقیقی انٹرویو:
کسی اہم موضوع پر گہرائی سے تحقیق کے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ - تاثراتی انٹرویو:
کسی واقعہ یا مسئلے پر عوام یا کسی شخصیت کے تاثرات جاننے کے لیے کیا جاتا ہے۔ - شخصی انٹرویو:
کسی فرد کی زندگی، کارناموں اور خیالات کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ - رہنمائی انٹرویو:
کسی ماہر یا اسکالر سے کسی مسئلے پر رائے اور رہنمائی لینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ - ادارتی یا رائے عامہ انٹرویو:
عوامی مسائل اور رجحانات پر مختلف لوگوں کی رائے حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
نتیجہ:
انٹرویو صحافت کا نہایت اہم ذریعہ ہے جو کسی موضوع یا شخصیت کے بارے میں براہِ راست اور مستند معلومات فراہم کرتا
ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف عوام کو سچائی سے آگاہ کیا جاتا ہے بلکہ معاشرتی مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل میں بھی مدد
ملتی ہے۔ انٹرویو کے مقاصد، طریقہ کار اور اقسام اسے ایک جامع اور قابلِ اعتماد صحافتی فن بناتے ہیں۔
سوال نمبر 3:
پروپیگینڈہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت، مقاصد اور مختلف ذرائع پر روشنی ڈالیں۔
پروپیگینڈہ سے مراد:
پروپیگینڈہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے منصوبہ بندی کے ساتھ مخصوص خیالات، نظریات یا پیغامات کو عوام تک اس انداز
میں پہنچایا جاتا ہے کہ ان کے جذبات اور رویے متاثر ہوں۔ یہ دراصل ابلاغِ عامہ کی ایک حکمتِ عملی ہے جس کا مقصد کسی
خاص ایجنڈے کو فروغ دینا یا مخالف نقطۂ نظر کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ پروپیگینڈہ مثبت بھی ہو سکتا ہے (جیسے تعلیم اور
اصلاح کے لیے) اور منفی بھی (جیسے غلط معلومات یا نفرت پھیلانے کے لیے)۔
پروپیگینڈہ کی اہمیت:
- عوامی رائے کو مخصوص سمت دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- سیاست، معاشرت اور معیشت میں اثرانداز ہو کر پالیسی سازی پر اثر ڈالتا ہے۔
- قومی اتحاد یا انتشار پیدا کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔
- جنگوں اور بین الاقوامی تعلقات میں ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- جدید میڈیا کے دور میں عوام کے خیالات اور رویوں کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
پروپیگینڈہ کے مقاصد:
- عوام کو کسی خاص نظریے یا ایجنڈے کی طرف مائل کرنا۔
- سیاسی جماعتوں یا حکومت کی حمایت حاصل کرنا۔
- مخالفین کو کمزور یا بدنام کرنا۔
- قومی یا مذہبی جذبات کو ابھارنا۔
- تعلیمی اور سماجی اصلاحات کو فروغ دینا۔
- جنگی حالات میں فوج اور عوام کا حوصلہ بلند رکھنا۔
پروپیگینڈہ کے ذرائع:
- اخبارات و رسائل:
مضامین، اداریے اور خبریں پروپیگینڈہ پھیلانے کا اہم ذریعہ ہیں۔ - ریڈیو اور ٹیلی وژن:
آواز اور تصویر کے ذریعے بڑے پیمانے پر اثر ڈالنے کا سب سے تیز ذریعہ۔ - سوشل میڈیا:
موجودہ دور میں سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے جہاں پیغامات فوری طور پر لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ - پمفلٹ اور پوسٹر:
سیاسی، مذہبی اور تجارتی پروپیگینڈہ کے لیے عام استعمال ہوتے ہیں۔ - جلسے اور تقاریر:
عوامی اجتماعات میں براہِ راست پروپیگینڈہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے جذبات کو ابھارا جا سکے۔ - فلم اور ڈرامہ:
تفریح کے ساتھ ساتھ نظریات اور پیغامات پہنچانے کے مؤثر ذرائع ہیں۔
نتیجہ:
پروپیگینڈہ ایک دو دھاری تلوار ہے جو مثبت یا منفی دونوں پہلوؤں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسے قومی ترقی،
تعلیم اور اصلاح کے لیے بروئے کار لایا جائے تو یہ معاشرتی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر اسے نفرت، جھوٹ یا
فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے پروپیگینڈہ کی ذمہ دارانہ اور مثبت
استعمال ہی معاشرے کے حق میں بہتر ہے۔
سوال نمبر 4:
سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی جمانے کے اصول اور اقسام بیان کریں۔
سرخی سے مراد:
صحافت میں “سرخی” ایک خبر یا مضمون کا وہ مختصر اور جامع عنوان ہوتا ہے جو قارئین کی فوری توجہ اپنی طرف مبذول
کرواتا ہے۔ سرخی دراصل خبر کا چہرہ اور پہچان ہوتی ہے جو مضمون یا خبر کے مرکزی خیال کو چند الفاظ میں سمو کر پیش
کرتی ہے۔ اچھی سرخی نہ صرف دلچسپی پیدا کرتی ہے بلکہ قاری کو خبر پڑھنے پر بھی آمادہ کرتی ہے۔
سرخی جمانے کے اصول:
- جامع اور مختصر ہونا:
سرخی میں زیادہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں بلکہ کم سے کم الفاظ میں خبر کا مرکزی نکتہ پیش کیا جائے۔ - دلچسپ اور توجہ خیز ہونا:
سرخی ایسی ہو جو قاری کی فوری دلچسپی پیدا کرے۔ - حقائق پر مبنی ہونا:
سرخی ہمیشہ درست اور حقیقت پر مبنی ہو، مبالغہ آرائی یا جھوٹ سے گریز کیا جائے۔ - سادہ اور عام فہم زبان:
سرخی ایسی زبان میں ہو جو ہر سطح کے قاری کو سمجھ آ سکے۔ - مرکزی خیال کی عکاسی:
سرخی خبر یا مضمون کے اصل نقطۂ نظر کو اجاگر کرے۔ - وقت کی مناسبت:
فوری اور تازہ ترین حالات کے مطابق سرخی ترتیب دی جائے۔ - قواعدِ زبان کی پابندی:
سرخی میں املا اور زبان کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے۔
سرخی کی اقسام:
- خبری سرخی:
ایسی سرخی جو کسی واقعہ یا حادثے کی خبر کو ظاہر کرتی ہے، جیسے “زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی”۔ - تاثراتی سرخی:
وہ سرخی جو جذبات ابھارنے اور اثر ڈالنے کے لیے استعمال کی جائے۔ - سوالیہ سرخی:
ایسی سرخی جو سوالیہ انداز میں ہو تاکہ قاری کی دلچسپی بڑھ سکے، جیسے “کیا مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا؟” - ادارتی سرخی:
وہ سرخی جو کسی اداریے یا رائے پر مبنی مضمون کے لیے جمی جاتی ہے۔ - تجزیاتی سرخی:
کسی اہم مسئلے پر تفصیلی تجزیہ یا تبصرے کو ظاہر کرنے والی سرخی۔ - مزاحیہ یا دلچسپ سرخی:
وہ سرخی جو قاری کو مسکرانے یا دلچسپی لینے پر مجبور کرے۔ - اشتہاری سرخی:
کسی پروڈکٹ یا سروس کی تشہیر کے لیے دلکش اور پرکشش الفاظ پر مبنی سرخی۔
نتیجہ:
سرخی کسی بھی خبر یا مضمون کا سب سے اہم اور نمایاں حصہ ہے۔ اچھی سرخی قاری کی توجہ حاصل کرنے، مواد کی جھلک پیش
کرنے اور خبر کی افادیت بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ سرخی جمانے کے اصول اور اقسام کو مدِنظر رکھتے ہوئے ہی
صحافت میں مؤثر اور کامیاب انداز اختیار کیا جا سکتا ہے۔
سوال نمبر 5:
فیچر کا مفہوم اور اقسام بیان کریں۔ قیام پاکستان کے بعد فیچر نگاری کا جائزہ لیں نیز فیچر نویسی اور کالم نویسی کا موازنہ کریں۔
فیچر کا مفہوم:
فیچر صحافت کی ایک اہم صنف ہے جو خبر اور ادب کا حسین امتزاج کہلاتی ہے۔ یہ محض کسی واقعے کی اطلاع دینے کے بجائے اس
کے پس منظر، اثرات، وجوہات اور انسانی پہلوؤں کو خوبصورت اور دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ فیچر کی زبان عام خبر سے
زیادہ دلکش، بامحاورہ اور بامعنی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو محض اطلاع دینا نہیں بلکہ تفریح، معلومات اور فکری
تسکین فراہم کرنا ہوتا ہے۔
فیچر کی اقسام:
- خبری فیچر:
کسی بڑی خبر یا واقعے کے گرد لکھا جانے والا فیچر جو اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ - تاثراتی فیچر:
کسی منظر، شخصیت یا موقع پر مبنی ایسا فیچر جس میں مصنف کے تاثرات اور جذبات جھلکتے ہوں۔ - تاریخی فیچر:
تاریخ کے اہم واقعات یا شخصیات پر معلوماتی اور تحقیقی فیچر۔ - شخصی فیچر:
کسی شخصیت کی زندگی، کارناموں اور خدمات پر مبنی فیچر۔ - سفر نامہ نما فیچر:
کسی جگہ یا علاقے کے حالات، مناظر اور ثقافت پر مبنی فیچر۔ - معاشرتی و ثقافتی فیچر:
کسی معاشرتی مسئلے یا ثقافتی موضوع پر مبنی تحریر۔ - ادبی فیچر:
ادبی میلوں، ادیبوں اور شعری و ادبی سرگرمیوں پر مبنی فیچر۔
قیام پاکستان کے بعد فیچر نگاری کا جائزہ:
قیام پاکستان کے بعد فیچر نگاری نے تیزی سے ترقی کی۔ ابتدا میں فیچر زیادہ تر قومی مسائل، آزادی کی جدوجہد اور
تعمیرِ وطن سے متعلق ہوتے تھے۔ بعد ازاں یہ میدان وسعت اختیار کر گیا اور صحافیوں نے سماجی برائیوں، ادبی و ثقافتی
سرگرمیوں، کھیلوں، سیاست اور معیشت پر بھی فیچر لکھنے شروع کیے۔ پاکستان کے معروف صحافیوں اور ادیبوں نے فیچر نگاری
کو ایک فن کی حیثیت دی، جس کے نتیجے میں یہ صنف نہ صرف عوامی شعور کی بیداری کا ذریعہ بنی بلکہ قومی مسائل کو اجاگر
کرنے میں بھی نمایاں کردار ادا کرنے لگی۔
فیچر نویسی اور کالم نویسی کا موازنہ:
- اندازِ تحریر: فیچر عام طور پر تحقیقی اور تفصیلی ہوتا ہے جبکہ کالم زیادہ مختصر، براہِ راست اور تجزیاتی انداز میں لکھا جاتا ہے۔
- مواد: فیچر معلوماتی اور وضاحتی ہوتا ہے، جب کہ کالم رائے اور تجزیہ پیش کرتا ہے۔
- زبان و اسلوب: فیچر کی زبان ادبی اور دلکش ہوتی ہے، کالم کی زبان عام طور پر سادہ، طنزیہ یا تنقیدی ہوتی ہے۔
- مقاصد: فیچر قاری کو معلومات اور تفریح فراہم کرتا ہے، کالم قاری کو قائل کرنے یا رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔
- موضوعات: فیچر زیادہ تر معاشرتی، ثقافتی اور عمومی موضوعات پر لکھا جاتا ہے جبکہ کالم زیادہ تر سیاسی اور موجودہ حالات سے متعلق ہوتا ہے۔
نتیجہ:
فیچر نگاری صحافت کی ایک دلکش اور بامقصد صنف ہے جو قارئین کو محض معلومات فراہم نہیں کرتی بلکہ ان کی دلچسپی اور
ذوق کو بھی بڑھاتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد فیچر نگاری نے صحافت کو ایک نئی جہت دی۔ فیچر اور کالم دونوں اہم صحافتی
اصناف ہیں، تاہم فیچر زیادہ تخلیقی اور معلوماتی جبکہ کالم زیادہ تنقیدی اور تجزیاتی نوعیت رکھتا ہے۔
سوال نمبر 6:
سب ایڈیٹر کی ذمہ داریاں اور اوصاف تحریر کریں۔
سب ایڈیٹر کا تعارف:
سب ایڈیٹر (Sub-Editor) اخبار یا رسالے کے ایڈیٹوریل شعبے کا ایک اہم رکن ہوتا ہے۔ اسے اخبار کا ’’پردے کے پیچھے کا
معمار‘‘ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ خبریں اور مضامین براہِ راست عوام کے سامنے پیش نہیں کرتا بلکہ ان کو درست، جامع
اور بامعنی بنا کر اشاعت کے لیے تیار کرتا ہے۔ خبر کی سرخی جمانا، زبان و بیان کی اصلاح کرنا اور مواد کو قاری کے
لیے پرکشش اور قابلِ فہم بنانا سب ایڈیٹر کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔
سب ایڈیٹر کی ذمہ داریاں:
- خبروں کی چھان بین، جانچ اور تصدیق کرنا۔
- خبروں کے لیے جامع اور جاذبِ نظر سرخیاں جمانا۔
- خبری مواد کو اخباری اصولوں اور ادارتی پالیسی کے مطابق ترتیب دینا۔
- غلطیوں، تضادات اور غیر ضروری تفصیلات کو دور کرنا۔
- زبان، گرامر اور اسلوب کو درست کرنا تاکہ خبر عام فہم اور رواں ہو۔
- خبر کی اہمیت کے مطابق اسے مناسب جگہ دینا۔
- تصاویر، کیپشنز اور گرافکس کا انتخاب اور خبر کے ساتھ ان کی مطابقت کو یقینی بنانا۔
- خبروں کے تسلسل اور توازن کو برقرار رکھنا تاکہ پورے اخبار میں یکسانیت قائم رہے۔
- ڈیڈ لائن کے اندر کام مکمل کر کے پرنٹنگ کے عمل کو ممکن بنانا۔
سب ایڈیٹر کے اوصاف:
- علم و مطالعہ:
سب ایڈیٹر کو ملکی و بین الاقوامی حالات، زبان اور صحافتی تقاضوں کا وسیع علم ہونا چاہیے۔ - باریک بینی:
خبر میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی تلاش کرنے اور درست کرنے کی صلاحیت۔ - زبان پر عبور:
رواں، سادہ اور بامحاورہ زبان لکھنے اور درست کرنے کی مہارت۔ - تخلیقی صلاحیت:
سرخی جمانے اور خبر کو دلچسپ انداز دینے کی خوبی۔ - فیصلہ سازی کی قوت:
یہ طے کرنا کہ کون سی خبر اہم ہے اور کس زاویے سے پیش کی جائے۔ - رفتار اور وقت کی پابندی:
سخت ڈیڈ لائن میں بھی درست اور معیاری کام کرنے کی صلاحیت۔ - غیر جانب داری:
خبر کی ادارت میں ذاتی رائے یا تعصب شامل نہ کرنا۔ - تنظیمی صلاحیت:
خبری مواد کو متوازن اور منظم انداز میں ترتیب دینا۔
نتیجہ:
سب ایڈیٹر اخبار کا وہ پوشیدہ معمار ہے جو خبروں کو محض ’’کچا مواد‘‘ سے نکال کر ایک مکمل اور معیاری شکل دیتا ہے۔
اس کی ذمہ داریاں خبر کی درستی، جامعیت اور دلکشی کو یقینی بنانا ہیں جبکہ اس کے اوصاف میں باریک بینی، زبان پر عبور
اور فیصلہ سازی کی قوت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح سب ایڈیٹر اخباری ادارے کی ساکھ اور قارئین کے اعتماد کو
مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
سوال نمبر 7:
تبصرہ نویسی کیا ہے؟ تبصرہ نویس کے فرائض اور اوصاف بیان کریں۔
تبصرہ نویسی کا مفہوم:
تبصرہ نویسی صحافت کی ایک اہم اور سنجیدہ صنف ہے جس میں کسی واقعے، کتاب، فلم، ڈرامے، قانون، پالیسی یا کسی بھی اہم
موضوع پر رائے اور تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ تبصرہ نویسی محض خبر کی تکرار نہیں بلکہ اس کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی اور
تجزیاتی جائزہ لینا ہے۔ اس کا مقصد قاری کو خبر کے پس منظر، اثرات اور نتائج سے آگاہ کرنا اور اس کی رہنمائی کرنا
ہوتا ہے۔
تبصرہ نویس کے فرائض:
- خبروں اور واقعات کا گہرائی سے مطالعہ اور تجزیہ کرنا۔
- کسی کتاب، ڈرامے، پالیسی یا فلم کے مثبت و منفی پہلو اجاگر کرنا۔
- قاری کو محض معلومات نہیں بلکہ رہنمائی فراہم کرنا۔
- موضوع کے تاریخی، سماجی اور ثقافتی پس منظر کو واضح کرنا۔
- واقعات کو غیر جانبداری سے پرکھنا اور درست نتائج اخذ کرنا۔
- قاری کو یہ سمجھنے میں مدد دینا کہ واقعہ یا مسئلہ معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔
- مثبت اور تعمیری تنقید کے ذریعے اصلاحی پہلو سامنے لانا۔
- عوامی رائے کو بیدار اور درست سمت میں ہموار کرنا۔
تبصرہ نویس کے اوصاف:
- علم و بصیرت:
تبصرہ نویس کو وسیع مطالعہ اور گہری بصیرت حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ موضوع کا مختلف زاویوں سے جائزہ لے سکے۔ - غیر جانبداری:
ذاتی پسند، ناپسند یا تعصب کو تبصرے میں شامل نہ کیا جائے۔ - تنقیدی نظر:
موضوع کے خامیوں اور خوبیوں کو حقیقت پسندانہ طور پر سامنے لانے کی صلاحیت۔ - تحلیلی و تحقیقی صلاحیت:
صرف رائے دینے کے بجائے ٹھوس دلائل اور حقائق پر مبنی تجزیہ پیش کرنا۔ - واضح اور بامحاورہ زبان:
تبصرہ ایسی زبان میں ہونا چاہیے جو عام قاری کے لیے قابلِ فہم اور بامعنی ہو۔ - دیانت داری:
حقائق کو مسخ کیے بغیر، امانت داری سے پیش کرنا۔ - اختصار و جامعیت:
تبصرہ نہ تو غیر ضروری طوالت کا شکار ہو اور نہ ہی اتنا مختصر کہ اہم پہلو تشنہ رہ جائیں۔
نتیجہ:
تبصرہ نویسی صحافت کا ایک سنجیدہ اور ذمہ دارانہ فن ہے جس کے ذریعے نہ صرف قاری کو خبر کے باطن تک رسائی ملتی ہے
بلکہ اس کی رائے بھی تشکیل پاتی ہے۔ ایک اچھا تبصرہ نویس غیر جانبداری، علمیت، بصیرت اور تنقیدی صلاحیت کے ذریعے
معاشرے کی فکری اور اصلاحی رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح تبصرہ نویسی محض معلوماتی نہیں بلکہ تعمیری اور اصلاحی پہلو بھی
اپنے اندر سموئے ہوتی ہے۔
سوال نمبر 8:
بادشاہت اور جمہوریت میں فرق بیان کریں نیز جمہوریت کی مروجہ اقسام پر روشنی ڈالیں۔
بادشاہت کا مفہوم:
بادشاہت ایک ایسا طرزِ حکومت ہے جس میں ریاست کی تمام تر طاقت اور اقتدار ایک ہی شخص یعنی بادشاہ کے ہاتھ میں مرتکز
ہوتا ہے۔ بادشاہ اکثر موروثی بنیادوں پر منتخب ہوتا ہے اور اس کی حکمرانی کو عوامی رائے یا ووٹ کی بجائے وراثت،
روایات یا قوت کی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کو مطلق العنان بھی کہا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے
کرتا ہے۔ اس نظام میں عوامی رائے کی اہمیت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔
جمہوریت کا مفہوم:
جمہوریت ایک ایسا نظامِ حکومت ہے جس میں اقتدار عوام کے پاس ہوتا ہے اور عوام اپنے نمائندے آزادانہ ووٹ کے ذریعے
منتخب کرتے ہیں۔ جمہوریت میں قانون، آئین اور عوامی رائے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ
“حکومت عوام کے ذریعے، عوام کے لیے اور عوام کی مرضی سے قائم ہوتی ہے”۔ اس میں عوام کو اظہارِ رائے، مساوات اور
بنیادی حقوق کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔
بادشاہت اور جمہوریت میں فرق:
- اقتدار کا منبع: بادشاہت میں اقتدار ایک فرد کے پاس ہوتا ہے جبکہ جمہوریت میں اقتدار عوام کے پاس ہوتا ہے۔
- فیصلہ سازی: بادشاہ اپنے فیصلے ذاتی مرضی یا مفاد کے مطابق کرتا ہے جبکہ جمہوریت میں فیصلے عوامی نمائندوں اور پارلیمنٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔
- انتخابی نظام: بادشاہت میں حکمران وراثتی طور پر بنتا ہے جبکہ جمہوریت میں حکمران عوامی ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔
- عوامی شمولیت: بادشاہت میں عوام کا سیاسی کردار محدود یا غیر موجود ہوتا ہے جبکہ جمہوریت میں عوام فعال کردار ادا کرتے ہیں۔
- حقوق و آزادی: بادشاہت میں عوام کے حقوق اکثر محدود ہوتے ہیں جبکہ جمہوریت میں آزادیِ اظہار، مساوات اور بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کیا جاتا ہے۔
جمہوریت کی مروجہ اقسام:
- براہِ راست جمہوریت:
اس میں عوام براہِ راست اپنے فیصلے کرتے ہیں اور قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں۔ قدیم یونان میں اس طرزِ جمہوریت کی مثال ملتی ہے۔ - بالواسطہ جمہوریت (نمائندہ جمہوریت):
اس میں عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو ان کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر ممالک میں یہی جمہوریت رائج ہے۔ - پارلیمانی جمہوریت:
اس میں وزیراَعظم اور کابینہ پارلیمنٹ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں اور عوامی نمائندوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ مثال: پاکستان، برطانیہ۔ - صدارتی جمہوریت:
اس میں صدر براہِ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے اور وسیع اختیارات رکھتا ہے۔ مثال: امریکہ۔ - اسلامی جمہوریت:
اس میں عوام کو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں لیکن قانون سازی قرآن و سنت کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ مثال: پاکستان کا آئین۔ - سوشلسٹ جمہوریت:
اس میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ وسائل کی تقسیم اور معاشی مساوات پر زور دیا جاتا ہے۔ مثال: چین (اپنے مخصوص انداز میں)۔
نتیجہ:
بادشاہت اور جمہوریت دو بالکل مختلف طرزِ حکومت ہیں۔ بادشاہت فردِ واحد کے اقتدار پر مبنی ہے جبکہ جمہوریت عوامی
اقتدار کی عکاس ہے۔ آج کی دنیا میں زیادہ تر ممالک جمہوری نظام کو اپنائے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں عوامی شمولیت،
مساوات اور آزادی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ جمہوریت ہی وہ نظام ہے جو عوام کو سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کی ضمانت
فراہم کرتا ہے۔
سوال نمبر 9:
صحافتی زبان کی خصوصیات اور اہمیت بیان کریں نیز اس کا دیگر اسالیب زبان سے موازنہ کریں۔
صحافتی زبان کا مفہوم:
صحافتی زبان سے مراد وہ اسلوبِ بیان ہے جو اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دیگر صحافتی ذرائع ابلاغ میں استعمال ہوتا
ہے۔ اس زبان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام فہم، براہِ راست، جامع اور مؤثر ہو تاکہ کم تعلیم یافتہ قاری یا سامع
بھی اسے بآسانی سمجھ سکے۔ صحافتی زبان میں غیر ضروری پیچیدگی، مشکل محاورات اور ثقیل الفاظ سے اجتناب کیا جاتا ہے۔
صحافتی زبان کی خصوصیات:
- سادگی: صحافتی زبان سادہ اور رواں ہوتی ہے تاکہ ہر شخص اسے سمجھ سکے۔
- جامعیت: کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔
- براہِ راست پن: اس میں ابہام یا گھما پھرا کر بات کرنے کی بجائے واضح اور سیدھی بات کی جاتی ہے۔
- دلکشی: اسلوب ایسا ہوتا ہے جو قاری کی توجہ کھینچ لے اور دلچسپی پیدا کرے۔
- غیر جانب داری: خبر اور رپورٹنگ میں غیر جانبدار زبان استعمال کی جاتی ہے تاکہ حقائق ویسے ہی سامنے آئیں جیسے ہیں۔
- اختصار: وقت اور جگہ کی کمی کے باعث بات کو مختصر مگر مکمل انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔
- جدت: صحافتی زبان میں نئے الفاظ، اصطلاحات اور بدلتے حالات کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔
صحافتی زبان کی اہمیت:
- یہ عوام تک خبروں اور معلومات کی تیز ترین ترسیل کا ذریعہ ہے۔
- قومی شعور اور عوامی رائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
- سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی معاملات کو عام فہم انداز میں عوام تک پہنچاتی ہے۔
- اخلاقی اور سماجی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔
- بین الاقوامی حالات و واقعات کو سمجھنے میں عوام کی رہنمائی کرتی ہے۔
دیگر اسالیبِ زبان سے موازنہ:
- ادبی زبان اور صحافتی زبان:
ادبی زبان میں تشبیہات، استعارے اور تخیل کا عنصر زیادہ ہوتا ہے جبکہ صحافتی زبان زیادہ سادہ، واضح اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ - علمی زبان اور صحافتی زبان:
علمی زبان مشکل اصطلاحات اور تفصیلی وضاحت پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ صحافتی زبان مختصر، عام فہم اور سہل انداز میں لکھی جاتی ہے۔ - تجارتی زبان اور صحافتی زبان:
تجارتی زبان کا مقصد خرید و فروخت اور کاروبار کی تشہیر ہوتا ہے، جب کہ صحافتی زبان کا مقصد خبر، معلومات اور عوامی شعور بیدار کرنا ہے۔ - مذہبی زبان اور صحافتی زبان:
مذہبی زبان میں وعظ، نصیحت اور روحانیت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، جب کہ صحافتی زبان غیر جانب دار اور حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔
نتیجہ:
صحافتی زبان دراصل عوامی ابلاغ کا سب سے اہم وسیلہ ہے جو پیچیدہ ترین موضوعات کو بھی عام فہم اور مختصر انداز میں
بیان کرتی ہے۔ یہ زبان دیگر اسالیب سے مختلف اس لیے ہے کہ اس کا مقصد محض اظہارِ خیال نہیں بلکہ بروقت معلومات اور
سچائی کو عوام تک پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے صحافتی زبان صحافت کی روح اور اس کے مؤثر ابلاغ کی ضامن ہے۔
سوال نمبر 10:
اخبار کی تیاری کے مختلف مراحل تحریر کریں نیز خبر کی کاپی کو دلکش بنانے کے طریقے بیان کریں۔
اخبار کی تیاری کے مراحل:
ایک اخبار کی تیاری ایک منظم اور مربوط عمل ہے جس میں مختلف شعبے مل کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مراحل درج ذیل
ہیں:
- خبر کی تلاش اور جمع آوری:
رپورٹرز مختلف ذرائع، پریس کانفرنسز، سرکاری و غیر سرکاری اداروں، ایجنسیوں اور عوامی نمائندوں سے خبریں اکٹھی کرتے ہیں۔ - خبر کی جانچ اور تصدیق:
ایڈیٹوریل ڈیسک پر موصول ہونے والی خبروں کو حقائق، حوالہ جات اور ذرائع کے مطابق پرکھا اور تصدیق کیا جاتا ہے تاکہ غلط یا جھوٹی خبر شائع نہ ہو۔ - خبر کی تدوین و تحریر:
ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر خبر کو صحافتی اصولوں کے مطابق مختصر، جامع اور دلکش انداز میں مرتب کرتا ہے۔ اس دوران زبان، سرخی اور اسلوب پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ - صفحات کی ترتیب:
نیوز ایڈیٹر اور پیج میکرز خبروں کو اہمیت اور نوعیت کے مطابق مختلف صفحات پر تقسیم کرتے ہیں۔ نمایاں خبریں پہلے صفحے پر جبکہ دیگر خبریں متعلقہ صفحات پر شائع کی جاتی ہیں۔ - پروف ریڈنگ:
خبروں میں زبان، املا اور اعداد و شمار کی درستی کے لیے پروف ریڈنگ کی جاتی ہے تاکہ کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ - چھپائی اور اشاعت:
صفحات کی کمپوزنگ اور ڈیزائننگ کے بعد اخبار پرنٹنگ پریس میں بھیجا جاتا ہے، جہاں جدید مشینوں کے ذریعے بڑی تعداد میں پرنٹ کیا جاتا ہے۔ - تقسیم:
چھپنے کے بعد اخبار کو مختلف شہروں، دکانوں اور ہاکرز کے ذریعے قارئین تک پہنچایا جاتا ہے۔
خبر کی کاپی کو دلکش بنانے کے طریقے:
- جامع اور پرکشش سرخی: اچھی سرخی قاری کو فوراً متوجہ کرتی ہے، لہٰذا یہ مختصر، جامع اور پراثر ہونی چاہیے۔
- ابتدائی جملہ: خبر کا پہلا جملہ واضح اور اہم ترین معلومات پر مبنی ہونا چاہیے تاکہ قاری خبر کو آگے پڑھنے پر مجبور ہو۔
- سادہ اور رواں زبان: مشکل اصطلاحات اور ثقیل الفاظ کے بجائے آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے۔
- اہمیت کے مطابق ترتیب: خبر میں سب سے اہم بات پہلے اور کم اہم باتیں بعد میں شامل کی جائیں۔
- اعداد و شمار کا درست استعمال: حقائق اور اعداد و شمار کو درست انداز میں شامل کرنے سے خبر کی وقعت بڑھتی ہے۔
- تصاویر اور گرافکس: مناسب تصاویر اور خاکے خبر کو زیادہ جاندار اور دلکش بنا دیتے ہیں۔
- اختصار اور جامعیت: غیر ضروری تفصیلات سے گریز کیا جائے اور کم الفاظ میں زیادہ معلومات فراہم کی جائیں۔
نتیجہ:
اخبار کی تیاری ایک منظم اور کثیر الجہتی عمل ہے جو رپورٹر سے لے کر ایڈیٹر اور پرنٹنگ تک کئی مراحل میں مکمل ہوتا
ہے۔ خبر کو دلکش بنانے کے لیے جامع سرخی، واضح زبان، درست اعداد و شمار اور مؤثر اسلوب بنیادی عوامل ہیں۔ ایک دلکش
اور معیاری خبر ہی اخبار کی کامیابی اور عوامی مقبولیت کی ضمانت بنتی ہے۔
سوال نمبر 11:
صحافت کو ملک کا کون سا ستون سمجھا جاتا ہے؟ مختلف نظریات کی روشنی میں وضاحت کریں۔
صحافت کا ستون کی حیثیت:
صحافت کو عموماً ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ ریاست کے تین بنیادی ستون مقننہ (Legislature)،
عدلیہ (Judiciary) اور انتظامیہ (Executive) ہیں، لیکن صحافت کو اس لیے چوتھا ستون کہا جاتا ہے کہ یہ باقی تینوں پر
نظر رکھتی ہے اور عوام تک صحیح اور بروقت معلومات پہنچا کر رائے عامہ تشکیل دیتی ہے۔
مختلف نظریات کی روشنی میں وضاحت:
- جمہوری نظریہ:
جمہوری ریاست میں صحافت کو عوام کی آواز تصور کیا جاتا ہے۔ یہ حکومت اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ جمہوری معاشروں میں آزادیٔ صحافت کو بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے تاکہ عوام اپنی حکومت کے فیصلوں پر نظر رکھ سکیں۔ - نظریۂ نگرانی:
اس نظریے کے مطابق صحافت “واچ ڈاگ” (Watchdog) کا کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی یہ حکومت اور ریاستی اداروں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتی ہے اور کسی بھی زیادتی یا بے ضابطگی کو بے نقاب کرتی ہے۔ - نظریۂ رائے عامہ:
صحافت عوامی مسائل کو اجاگر کر کے رائے عامہ ہموار کرتی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ایک باشعور عوام ہی اچھی ریاست اور منصفانہ نظام قائم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے صحافت بنیادی ذریعہ ہے۔ - سماجی نظریہ:
اس نظریے کے مطابق صحافت معاشرتی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہ سماجی برائیوں، ناانصافیوں اور جرائم کو سامنے لاتی ہے اور مثبت رویوں کو فروغ دیتی ہے۔ - اسلامی نقطۂ نظر:
اسلامی تناظر میں صحافت کو “امر بالمعروف اور نہی عن المنکر” کے اصول پر پرکھا جاتا ہے۔ صحافت کا مقصد صرف خبر دینا نہیں بلکہ سچائی کو اجاگر کرنا، عدل و انصاف کو فروغ دینا اور جھوٹ و فریب کو بے نقاب کرنا ہے۔
صحافت کی اہمیت بطور چوتھا ستون:
- حکومت کے اقدامات پر عوام کو باخبر رکھنا۔
- ریاستی اداروں کی کارکردگی پر نظر رکھنا۔
- عوامی مسائل اور آواز کو حکمرانوں تک پہنچانا۔
- رائے عامہ تشکیل دینا اور بیداری پیدا کرنا۔
- سچائی، انصاف اور شفافیت کو فروغ دینا۔
نتیجہ:
صحافت کو بجا طور پر ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف حکومت اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا
کرتی ہے بلکہ ایک نگہبان، ایک مصلح اور ایک رہنما کی حیثیت سے بھی سامنے آتی ہے۔ مختلف نظریات کی روشنی میں اس کی
اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے کہ بغیر آزاد صحافت کے کوئی بھی معاشرہ حقیقی جمہوریت، عدل اور شفافیت حاصل نہیں کر سکتا۔
سوال نمبر 12:
اشاعت و طباعت میں جدید رجحانات کا جائزہ لیں نیز صحافت میں جدید ایجادات کے استعمال پر نوٹ تحریر کریں۔
اشاعت و طباعت میں جدید رجحانات:
صحافت میں اشاعت و طباعت ہمیشہ سے اہم حیثیت رکھتی رہی ہے۔ ماضی میں اخبارات اور رسائل کی طباعت محض ہاتھ کی مشینوں
یا محدود سہولیات تک محدود تھی، لیکن دورِ جدید میں پرنٹنگ ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا ہوا ہے۔ آج اخبارات زیادہ تیز
رفتاری، معیار اور دلکش انداز میں چھپتے ہیں۔ چند اہم جدید رجحانات درج ذیل ہیں:
- ڈیجیٹل پرنٹنگ:
اب اخبارات اور رسائل میں روایتی پرنٹنگ کی بجائے جدید ڈیجیٹل پرنٹنگ استعمال ہو رہی ہے جس سے اشاعت کا معیار بہتر اور لاگت کم ہو گئی ہے۔ - کلر پرنٹنگ:
پہلے اخبارات زیادہ تر سیاہ و سفید ہوا کرتے تھے، مگر آج کل رنگین پرنٹنگ عام ہو گئی ہے جو قارئین کی دلچسپی میں اضافہ کرتی ہے۔ - کمپیوٹر کمپوزنگ:
ہینڈ کمپوزنگ کی جگہ کمپیوٹر کمپوزنگ نے لے لی ہے جس سے وقت کی بچت اور تحریر کا معیار بہتر ہوا ہے۔ - تیز رفتار پرنٹنگ مشینیں:
جدید آٹومیٹک مشینوں نے بڑی تعداد میں اخبارات کی فوری اشاعت کو ممکن بنا دیا ہے۔ - آن لائن اشاعت:
طباعت کے ساتھ ساتھ اشاعت اب صرف کاغذ پر محدود نہیں رہی بلکہ اخبارات اور رسائل اپنی ویب سائٹس اور ای پیپر کے ذریعے بھی شائع ہوتے ہیں۔
صحافت میں جدید ایجادات کا استعمال:
صحافت کا دائرہ طباعت تک محدود نہیں رہا بلکہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے اسے مزید وسعت دی ہے۔ آج کا صحافی
جدید ایجادات کے بغیر اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ چند نمایاں ایجادات اور ان کا کردار درج ذیل ہے:
- انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا: خبروں کی فوری ترسیل اور رائے عامہ ہموار کرنے میں انٹرنیٹ بنیادی ذریعہ ہے۔ فیس بک، ٹوئٹر، یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز نے صحافت کو ایک نئی جہت دی ہے۔
- اسمارٹ فونز: رپورٹرز اب کسی بھی خبر کو موقع پر ہی تصویر، ویڈیو اور متن کی صورت میں دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔
- ٹیلی ویژن اور لائیو براڈکاسٹ: براہِ راست نشریات نے خبروں کو مزید مستند اور بروقت بنا دیا ہے۔
- آن لائن جرنلزم: بلاگز، ویب نیوز پورٹلز اور ای پیپرز نے روایتی صحافت کو ڈیجیٹل صحافت میں بدل دیا ہے۔
- ایڈیٹنگ سافٹ ویئر: جدید سافٹ ویئر جیسے Adobe Photoshop، Premiere وغیرہ خبر کو پیشہ ورانہ انداز میں تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
نتیجہ:
اشاعت و طباعت میں جدید رجحانات نے اخبارات کو نہ صرف معیاری اور دلکش بنایا بلکہ کم وقت میں بڑی مقدار میں اشاعت
بھی ممکن بنا دی۔ اسی طرح جدید ایجادات نے صحافت کو عالمی سطح پر ایک تیز رفتار اور ہمہ گیر قوت بنا دیا ہے۔ آج
صحافت پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل تینوں صورتوں میں ایک طاقتور ادارہ بن چکی ہے جو لمحہ بہ لمحہ دنیا کو بدل رہی ہے۔
سوال نمبر 13:
سرد جنگ اور نفسیاتی جنگ میں فرق واضح کریں۔ افواہ سازی کیسے اور کس طرح پروپیگنڈا کا موثر ذریعہ بنتی ہے؟
سرد جنگ کا مفہوم:
سرد جنگ سے مراد وہ جنگی کیفیت ہے جس میں طاقتور ممالک براہِ راست عسکری تصادم سے گریز کرتے ہیں لیکن سیاسی، سفارتی،
معاشی اور عسکری دباؤ کے ذریعے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرد جنگ کا نمایاں دور دوسری جنگِ عظیم کے
بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان دیکھا گیا۔ اس جنگ میں ہتھیاروں کا استعمال براہِ راست نہیں کیا جاتا بلکہ
پراکسی وارز، اتحادی بلاکس اور پروپیگنڈا مہمات کے ذریعے ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔
نفسیاتی جنگ کا مفہوم:
نفسیاتی جنگ انسانی ذہن اور سوچ پر اثر انداز ہونے کا نام ہے۔ اس میں دشمن کی حوصلہ شکنی، اپنی طاقت کی تشہیر،
افواہوں کا پھیلاؤ، جھوٹے دعوے، جذباتی نعرے اور میڈیا کے ذریعے رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنا شامل ہے۔ اس
جنگ میں دشمن کے ہتھیاروں پر نہیں بلکہ اس کے ذہن و حوصلے پر حملہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو
جائے۔
سرد جنگ اور نفسیاتی جنگ میں فرق:
- نوعیت: سرد جنگ زیادہ تر سیاسی اور عسکری حکمتِ عملی پر مبنی ہوتی ہے جبکہ نفسیاتی جنگ ذہنی اور جذباتی محاذ پر لڑی جاتی ہے۔
- طریقۂ کار: سرد جنگ میں فوجی طاقت کے مظاہرے، اتحادیوں کا قیام اور معاشی دباؤ شامل ہوتے ہیں جبکہ نفسیاتی جنگ میں افواہیں، پروپیگنڈا، اشتہارات اور میڈیا کا استعمال ہوتا ہے۔
- نتائج: سرد جنگ کا نتیجہ طویل المدت عالمی کشمکش کی صورت میں نکلتا ہے جبکہ نفسیاتی جنگ فوری طور پر عوام یا فوج کے حوصلے توڑنے میں مدد دیتی ہے۔
- میدانِ عمل: سرد جنگ کا میدان عالمی سیاست اور معیشت ہوتی ہے جبکہ نفسیاتی جنگ کا میدان انسانی ذہن اور سوچ ہے۔
افواہ سازی اور پروپیگنڈا:
افواہ سازی نفسیاتی جنگ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک جھوٹی خبر، مبالغہ آمیز اطلاع یا گمراہ کن بیانیہ عوام کے
ذہنوں کو متاثر کر کے پورے معاشرے میں بے چینی، خوف اور انتشار پیدا کر سکتا ہے۔ پروپیگنڈا میں افواہیں کچھ اس انداز
سے پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ انہیں سچ مان لیتے ہیں اور ان کے مطابق ردِعمل ظاہر کرتے ہیں۔
افواہ سازی کے اثرات:
- عوام کے اعتماد کو متزلزل کرتی ہے۔
- حکومت یا اداروں کے خلاف بدگمانی پیدا کرتی ہے۔
- دشمن کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر اور اپنی طاقت کو کمزور ظاہر کرتی ہے۔
- فوج یا عوام کے حوصلے پست کرتی ہے۔
- غیر یقینی کی فضا پیدا کر کے سیاسی و سماجی استحکام کو نقصان پہنچاتی ہے۔
نتیجہ:
سرد جنگ اور نفسیاتی جنگ دونوں جدید دنیا میں طاقتور ممالک کے اہم ہتھیار ہیں۔ سرد جنگ جہاں سیاسی و عسکری توازن کی
کشمکش کا نام ہے، وہیں نفسیاتی جنگ انسانی ذہن کو غلام بنانے کی کوشش ہے۔ افواہ سازی نفسیاتی جنگ میں پروپیگنڈا کا
سب سے موثر ذریعہ ہے جو عوام کے ذہنوں کو بدل کر دشمن کو اندر سے کمزور کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔
سوال نمبر 14:
سرسید احمد خان کی صحافتی خدمات بیان کریں نیز مثالی ضابطہ اخلاق کے خدوخال تحریر کریں۔
سرسید احمد خان کی صحافتی خدمات:
سرسید احمد خان برصغیر کے عظیم مصلح، مفکر اور صحافی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی فکری، تعلیمی اور سماجی ترقی کے لیے
صحافت کو مؤثر ترین ذریعہ بنایا۔ انہوں نے اخبارات و رسائل کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کو جدید تعلیم کی اہمیت سے آگاہ
کیا بلکہ انہیں انگریز حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ترغیب دی۔ ان کی صحافتی خدمات درج ذیل ہیں:
- رسالہ “سائینٹیفک سوسائٹی” (1864ء):
سرسید نے اس رسالے کے ذریعے سائنسی، تعلیمی اور فکری مضامین شائع کیے تاکہ مسلمان مغرب کی جدید سائنس و ٹیکنالوجی سے روشناس ہو سکیں۔ - رسالہ “تہذیب الاخلاق” (1870ء):
یہ سرسید کی صحافت کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح، اخلاقی تربیت، مذہبی رواداری، جدید علوم کی اہمیت اور سماجی بیداری کا پیغام عام کیا۔ - مغربی افکار کا تعارف:
سرسید نے یورپی علوم و نظریات کو مسلمانوں تک پہنچایا تاکہ وہ عالمی ترقی کے ساتھ قدم سے قدم ملا سکیں۔ - قومی یکجہتی کا فروغ:
ان کی تحریروں میں ہندو مسلم اتحاد، بین المذاہب ہم آہنگی اور برصغیر کی ترقی کا جذبہ نمایاں تھا۔ - اخلاقی و سماجی اصلاح:
سرسید نے توہم پرستی، جہالت اور فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کی اور مسلمانوں کو سچائی، دیانتداری اور محنت کی تلقین کی۔
مثالی ضابطہ اخلاق کے خدوخال:
صحافت کی آزادی کے ساتھ ساتھ اس پر اخلاقی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ایک مثالی ضابطہ اخلاق درج ذیل پہلوؤں پر
مشتمل ہونا چاہیے:
- سچائی اور دیانتداری: خبر میں جھوٹ، مبالغہ اور جانبداری شامل نہ ہو۔ صحافی کو ہمیشہ سچ اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنی چاہیے۔
- غیر جانب داری: کسی سیاسی، مذہبی یا معاشرتی دباؤ کے تحت خبر یا رائے کو مسخ نہ کیا جائے۔
- قومی مفاد: ایسی خبریں شائع نہ کی جائیں جو قومی سلامتی یا یکجہتی کو نقصان پہنچائیں۔
- شخصی وقار کا احترام: افراد کی ذاتی زندگی اور عزتِ نفس کو مجروح کرنے والی رپورٹنگ سے گریز کیا جائے۔
- معاشرتی ہم آہنگی: ایسی تحریریں شائع نہ ہوں جو مذہبی منافرت، فرقہ واریت یا تعصبات کو ہوا دیں۔
- حقائق کی تصدیق: ہر خبر یا فیچر کو شائع کرنے سے پہلے اس کی مکمل چھان بین اور تصدیق ضروری ہے۔
- مثبت رویہ: صحافت کا مقصد صرف تنقید نہیں بلکہ اصلاح اور رہنمائی بھی ہونا چاہیے۔
نتیجہ:
سرسید احمد خان کی صحافتی خدمات نے مسلمانوں کو نئی فکری اور تعلیمی روشنی عطا کی اور انہیں جدید دنیا کے تقاضوں سے
ہم آہنگ کیا۔ ان کا “تہذیب الاخلاق” آج بھی صحافتی تاریخ کا روشن باب ہے۔ مثالی ضابطہ اخلاق یہ تقاضا کرتا ہے کہ
صحافت صرف خبر رسانی تک محدود نہ رہے بلکہ معاشرتی اصلاح، قومی اتحاد اور فکری بیداری کا ذریعہ بنے۔
سوال نمبر 15:
صدارتی طرزِ حکومت پر نوٹ تحریر کریں۔
صدارتی طرز حکومت کا تعارف:
دنیا کے مختلف ممالک میں جمہوری نظام کو مختلف شکلوں میں اپنایا گیا ہے۔ ان میں ایک اہم اور مؤثر طرزِ حکومت
صدارتی نظام ہے جو بنیادی طور پر امریکہ میں رائج ہے۔ صدارتی نظام میں اقتدار کا مرکز صدر ہوتا ہے،
جو ریاست کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ بھی۔ اس نظام میں اختیارات کی واضح تقسیم ہوتی ہے اور صدر کو
وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں تاکہ وہ ملک کے نظم و نسق کو مؤثر انداز میں چلا سکے۔
صدارتی طرزِ حکومت کی خصوصیات:
- صدر کا انتخاب:
صدر کا براہِ راست یا بالواسطہ طور پر عوام کے ووٹوں سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مخصوص مدت کے لیے منتخب ہوتا ہے اور اسے عوامی نمائندگی کا مکمل حق حاصل ہوتا ہے۔ - اختیارات کی تقسیم:
صدارتی نظام میں اختیارات تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: مقننہ (قانون ساز ادارہ)، عدلیہ اور انتظامیہ۔ ان اداروں کے درمیان اختیارات کی علیحدگی واضح ہوتی ہے۔ - صدر کے اختیارات:
صدر کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے، وزراء کا تقرر کرتا ہے، مسلح افواج کا کمانڈر انچیف ہوتا ہے اور خارجہ پالیسی تشکیل دینے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ - قانون سازی میں کردار:
اگرچہ قانون سازی کا بنیادی اختیار پارلیمان کے پاس ہوتا ہے، لیکن صدر کے پاس ویٹو پاور موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ کسی بل کو روک سکتا ہے۔ - مقررہ مدت:
صدر کو ایک مخصوص مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، عموماً چار یا پانچ سال کے لیے۔ اس مدت کے دوران اسے پارلیمان کے عدم اعتماد کے ووٹ سے نہیں ہٹایا جا سکتا، سوائے مواخذے (Impeachment) کے عمل کے ذریعے۔ - مضبوط اور مستحکم حکومت:
صدارتی نظام میں حکومت ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس لیے فیصلے تیز اور مؤثر طریقے سے لیے جاتے ہیں۔
صدارتی طرزِ حکومت کے فوائد:
- سیاسی استحکام: صدر اپنی مدت پوری کرتا ہے، پارلیمان کے عدم اعتماد کے خدشات نہیں ہوتے۔
- مضبوط قیادت: صدر چونکہ براہِ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے، اس لیے اسے عوامی حمایت حاصل ہوتی ہے اور وہ مضبوط قیادت فراہم کرتا ہے۔
- فیصلہ سازی میں تیزی: ایک فرد کے پاس اختیارات مرکوز ہونے کی وجہ سے فیصلے جلد اور مؤثر انداز میں کیے جاتے ہیں۔
- اختیارات کی علیحدگی: عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ آزاد حیثیت میں کام کرتے ہیں، اس لیے طاقت کا توازن قائم رہتا ہے۔
- قومی سطح پر یکجہتی: صدر پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے اور علاقائی یا لسانی تعصبات سے بالاتر ہو کر فیصلے کرتا ہے۔
صدارتی طرزِ حکومت کے نقصانات:
- آمریت کا خطرہ: چونکہ صدر کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں، اس لیے اس نظام میں آمرانہ رجحانات پروان چڑھ سکتے ہیں۔
- عدم تعاون: اگر پارلیمان اور صدر مختلف جماعتوں سے ہوں تو قانون سازی اور پالیسیوں میں ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے۔
- اکثریت کی نظر اندازی: صدر براہِ راست عوام سے منتخب ہونے کے بعد خود کو سب سے بڑا نمائندہ سمجھتا ہے اور بعض اوقات عوامی رائے یا پارلیمانی قوتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔
- کابینہ کی غیر ذمہ داری: صدارتی نظام میں کابینہ صدر کی مشیر ہوتی ہے اور براہِ راست عوام یا پارلیمان کے سامنے جوابدہ نہیں ہوتی۔
پاکستان اور صدارتی نظام:
پاکستان میں صدارتی نظام پر کئی بار غور کیا گیا اور مختلف ادوار میں اس کو رائج بھی کیا گیا۔ ایوب خان نے 1962ء کا
آئین نافذ کرکے صدارتی نظام اپنایا، جس میں صدر کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے۔ لیکن اس کے نتیجے میں عوامی شمولیت
محدود ہوگئی اور آمرانہ رجحانات بڑھ گئے۔ پاکستان جیسے کثیرالسانی اور وفاقی اکائیوں پر مشتمل ملک میں صدارتی نظام
کے بجائے پارلیمانی نظام کو زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ عوامی نمائندگی کو وسیع مواقع فراہم کرتا ہے۔
نتیجہ:
صدارتی طرز حکومت ایک مستحکم، مؤثر اور تیز تر فیصلہ سازی کا نظام ہے جو ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ میں کامیابی
سے چل رہا ہے۔ تاہم، ایسے ممالک میں جہاں جمہوری ادارے کمزور اور معاشرتی تقسیم زیادہ ہو، وہاں اس نظام کے نقصانات
بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں پارلیمانی نظام زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے، لیکن صدارتی نظام کی خصوصیات
جیسے مضبوط قیادت اور تیز فیصلہ سازی کو نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔
سوال نمبر 16:
اسلام کا معاشی نظام بیان کریں۔
اسلامی معاشی نظام کا تعارف:
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرنے کے اصول فراہم کرتا ہے۔ معیشت انسانی زندگی کا ایک
بنیادی شعبہ ہے، اس لیے اسلام نے اس کے لیے ایسے سنہری اصول وضع کیے جو عدل، مساوات، فلاحِ عامہ اور باہمی تعاون پر
مبنی ہیں۔ اسلام کا معاشی نظام محض دولت کے ارتکاز کو ختم نہیں کرتا بلکہ دولت کی عادلانہ تقسیم، محنت کی قدر اور
غربت کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔
اسلامی معاشی نظام کی بنیادیں:
- حلال و حرام کی تمیز:
اسلام معاشی سرگرمیوں میں حلال طریقوں کو اپنانے اور حرام ذرائع (جیسے سود، جوا، رشوت، ذخیرہ اندوزی) سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ - ملکیت کا تصور:
اسلام انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان محض خلیفہ اور امین ہے۔ - زکوٰۃ اور صدقات:
اسلام نے دولت کی گردش کو یقینی بنانے کے لیے زکوٰۃ کو لازمی قرار دیا تاکہ امیروں کی دولت کا ایک حصہ غریبوں تک پہنچ سکے۔ - محنت کی اہمیت:
اسلام کے نزدیک محنت عبادت کے مترادف ہے۔ کسی کو بغیر محنت کے دولت کمانے کی اجازت نہیں۔ - باہمی تعاون:
اسلامی معیشت میں افراد ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہیں تاکہ معاشرے میں کوئی بھوکا یا بے سہارا نہ رہے۔
اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات:
- عدل و انصاف: اسلام کے معاشی نظام میں کسی کو استحصال کا شکار نہیں بنایا جاتا۔ ہر فرد کو اس کے حق کے مطابق حصہ ملتا ہے۔
- سود کی ممانعت: سود کو معاشرتی ناہمواری اور استحصال کی جڑ قرار دے کر مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا۔
- دولت کی منصفانہ تقسیم: دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں رہتی بلکہ زکوٰۃ، صدقہ اور وراثت کے اصولوں کے ذریعے سب میں تقسیم ہوتی ہے۔
- فلاحی ریاست کا قیام: اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور نادار افراد کی کفالت کرے۔
- بچت اور اعتدال: فضول خرچی اور بخل دونوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلام اعتدال اور میانہ روی پر زور دیتا ہے۔
اسلامی معاشی ادارے:
- بیت المال: یہ ایک مرکزی خزانہ ہے جہاں ریاستی محصولات، زکوٰۃ، جزیہ اور دیگر مالی وسائل جمع کیے جاتے ہیں اور عوامی فلاح پر خرچ ہوتے ہیں۔
- وقف کا نظام: اسلام میں وقف کو اہمیت دی گئی ہے تاکہ تعلیم، صحت اور فلاحی سرگرمیوں میں تسلسل کے ساتھ سرمایہ کاری ہو۔
- مزارعت و مضاربت: اسلام نے محنت اور سرمایہ کو یکجا کرنے کے لیے شراکت کے ایسے اصول وضع کیے ہیں جن سے دونوں فریق نفع میں شریک ہوتے ہیں۔
اسلامی معاشی نظام کے فوائد:
- دولت کا ارتکاز ختم ہوتا ہے اور سماجی انصاف قائم ہوتا ہے۔
- معاشرے میں غربت اور بے روزگاری کم ہوتی ہے۔
- سود کی ممانعت سے استحصالی معاشی ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے۔
- باہمی تعاون اور فلاحی اداروں کے ذریعے ایک فلاحی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔
- انفرادی محنت اور اجتماعی خوشحالی دونوں کو توازن کے ساتھ فروغ ملتا ہے۔
اسلامی معاشی نظام اور جدید دنیا:
موجودہ دنیا کے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظاموں نے معاشی انصاف فراہم کرنے میں ناکامی دکھائی ہے۔ سرمایہ دارانہ
نظام میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، جبکہ اشتراکی نظام انفرادی آزادی
سلب کر لیتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام ان دونوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہے جو انفرادی ملکیت کو تسلیم بھی کرتا ہے
اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بھی بناتا ہے۔
نتیجہ:
اسلام کا معاشی نظام ایک متوازن، منصفانہ اور فلاحی نظام ہے جو دولت کی عادلانہ تقسیم، سود کی ممانعت، محنت کی قدر
اور ضرورت مندوں کی کفالت کو یقینی بناتا ہے۔ یہ نظام نہ صرف دنیاوی سکون و خوشحالی کا ضامن ہے بلکہ اخروی فلاح کا
ذریعہ بھی ہے۔ آج کی دنیا کو حقیقی معاشی انصاف اور پائیدار ترقی کے لیے اسلامی معاشی اصولوں کو اپنانا ہوگا۔
سوال نمبر 17:
ابتدائیہ کیا ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔
ابتدائیہ کا مفہوم:
ابتدائیہ ہر تحریر، مضمون، فیچر، خبر یا ادبی تحریر کا پہلا اور سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل وہ حصہ ہے جو قاری
کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتا ہے اور اسے مکمل تحریر پڑھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ کسی بھی تحریر کا معیار اور اثر انگیزی
بڑی حد تک اس کے ابتدائیے پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک مؤثر ابتدائیہ نہ صرف موضوع کو واضح کرتا ہے بلکہ قاری کو ذہنی طور
پر تحریر کے اگلے حصے کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔
ابتدائیہ کی اہمیت:
- ابتدائیہ تحریر کے مرکزی خیال کی جھلک پیش کرتا ہے۔
- یہ قاری کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنے پر آمادہ کرتا ہے۔
- یہ تحریر کے اسلوب، مقصد اور سمت کا تعین کرتا ہے۔
- اچھا ابتدائیہ تحریر کو یادگار اور مؤثر بنا دیتا ہے۔
ابتدائیہ کی خصوصیات:
- اختصار: ابتدائیہ لمبا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جامع اور مختصر انداز میں تحریر کے مقصد کو واضح کرنا چاہیے۔
- دلچسپی: ابتدائیہ میں ایسی بات ہونی چاہیے جو قاری کی دلچسپی بڑھا دے۔
- وضاحت: ابتدائیہ تحریر کے موضوع کو واضح کرے اور قاری کو ابہام میں مبتلا نہ کرے۔
- ربط: ابتدائیہ ایسا ہو جو تحریر کے باقی حصے کے ساتھ مربوط ہو اور اچانک یا غیر متعلق نہ لگے۔
- ادبی حسن: زبان و بیان کی دلکشی ابتدائیے کو مزید جاذبِ نظر بنا دیتی ہے۔
ابتدائیہ کی اقسام:
- سوالیہ ابتدائیہ: قاری کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سوال کے انداز میں تحریر کا آغاز کیا جاتا ہے۔
- اقتباسی ابتدائیہ: مشہور قول یا آیت و حدیث کے ذریعے تحریر کا آغاز کیا جاتا ہے۔
- قصہ نما ابتدائیہ: دلچسپ واقعے یا کہانی سے ابتدا کی جاتی ہے۔
- تاثراتی ابتدائیہ: مصنف اپنے ذاتی جذبات یا تاثرات سے تحریر کا آغاز کرتا ہے۔
- خبری ابتدائیہ: کسی اہم واقعے یا خبر کو شروع میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ قاری متوجہ ہو۔
ابتدائیہ کی مثال:
مثال کے طور پر اگر موضوع “تعلیم کی اہمیت” ہو تو ابتدائیہ یوں دیا جا سکتا ہے:
“دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام نے تعلیم کو اپنی کامیابی کی بنیاد بنایا ہے۔ تعلیم نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتی
ہے بلکہ ایک قوم کی اجتماعی ترقی کی ضامن بھی ہے۔”
نتیجہ:
ابتدائیہ تحریر کی جان ہوتا ہے۔ یہ قاری کو تحریر سے جوڑتا ہے اور موضوع میں دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ مؤثر ابتدائیہ
تحریر کو وقار بخشتا ہے اور قاری پر دیرپا اثر چھوڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ابتدا اچھی ہو تو تحریر آدھی
کامیاب ہو جاتی ہے۔
سوال نمبر 18:
قانون ہتک عزت (Law of Defamation) پر نوٹ تحریر کریں۔
ہتک عزت کا مفہوم:
ہتک عزت سے مراد کسی فرد، ادارے یا جماعت کی ساکھ، وقار یا شہرت کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے نتیجے
میں متاثرہ شخص کی عزت مجروح ہوتی ہے اور اسے معاشرتی یا پیشہ ورانہ سطح پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہتک عزت
الفاظ، تحریر، اشاروں یا کسی اور طریقے سے کی جا سکتی ہے۔
قانون ہتک عزت کی ضرورت:
انسانی معاشرہ عزت، وقار اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص کو دوسرے کی عزت پامال کرنے کی آزادی دے
دی جائے تو معاشرتی امن و سکون باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے دنیا بھر میں ہتک عزت کے خلاف قوانین بنائے گئے تاکہ افراد
کو اپنی عزت و وقار کے تحفظ کا حق دیا جا سکے۔
ہتک عزت کی اقسام:
- تحریری ہتک عزت (Libel):
کسی شخص یا ادارے کے خلاف جھوٹی یا نقصان دہ بات تحریری طور پر شائع کرنا، جیسے اخبار، کتاب، ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر۔ - زبانی ہتک عزت (Slander):
کسی شخص کے بارے میں جھوٹے یا نقصان دہ بیانات زبانی طور پر پھیلانا، جیسے تقاریر یا ذاتی گفتگو میں۔
پاکستان میں قانون ہتک عزت:
پاکستان میں ہتک عزت کے متعلق قوانین مختلف قانونی دفعات میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں اہم درج ذیل ہیں:
- پاکستان پینل کوڈ (PPC) کی دفعات: دفعات 499 تا 502 میں ہتک عزت کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کرے تو اسے سزا دی جا سکتی ہے۔
- Defamation Ordinance 2002: اس آرڈیننس کے تحت ہتک عزت کرنے والے شخص پر ہرجانہ اور جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔
- الیکٹرانک جرائم ایکٹ: سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ہتک عزت کے معاملات کو اس قانون کے تحت بھی دیکھا جاتا ہے۔
سزا اور تادیبی اقدامات:
ہتک عزت ثابت ہونے پر مجرم کو جرمانے، ہرجانے یا قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کا مقصد متاثرہ شخص کی عزت کا تحفظ
اور معاشرے میں قانون کی بالادستی قائم رکھنا ہے۔
اہمیت:
- یہ قانون معاشرتی امن قائم رکھنے میں مددگار ہے۔
- افراد کی ساکھ اور عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے۔
- صحافت اور اظہارِ رائے کو ذمے داری کے ساتھ استعمال کرنے کی تلقین کرتا ہے۔
- جھوٹے پروپیگنڈے اور بہتان تراشی کو روکنے میں معاون ہے۔
نتیجہ:
قانون ہتک عزت معاشرتی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ قانون افراد کی عزت و وقار کا ضامن ہے اور دوسروں کو بلاوجہ
بدنام کرنے سے روکتا ہے۔ اگر اس قانون پر سختی سے عمل کیا جائے تو معاشرے میں نہ صرف انصاف قائم ہوگا بلکہ لوگوں کے
درمیان باہمی اعتماد اور عزت و احترام بھی فروغ پائے گا۔
سوال نمبر 19:
کاپی رائٹ کیا ہے؟ اس کی اہمیت بیان کریں۔
کاپی رائٹ کا مفہوم:
کاپی رائٹ سے مراد وہ قانونی حق ہے جو کسی تخلیق کار (مصنف، شاعر، محقق، مصور، موسیقار، فلم ساز یا سافٹ ویئر ڈیولپر
وغیرہ) کو اس کی تخلیقات پر حاصل ہوتا ہے۔ یہ حق اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کام کو نقل،
شائع، تقسیم یا تجارتی استعمال نہ کیا جا سکے۔ کاپی رائٹ بنیادی طور پر ذہنی محنت اور تخلیقی صلاحیت کے تحفظ کا نام
ہے۔
کاپی رائٹ کی اہم خصوصیات:
- یہ صرف اصل اور تخلیقی کام پر لاگو ہوتا ہے۔
- کاپی رائٹ عموماً ایک مخصوص مدت (مثلاً 50 یا 70 سال) کے لیے دیا جاتا ہے۔
- کاپی رائٹ کے تحت مصنف کو اپنے کام کو فروخت کرنے، لائسنس دینے یا کسی اور کو منتقل کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔
- اس کا اطلاق ادب، موسیقی، ڈرامہ، پینٹنگ، فوٹوگرافی، فلم، کمپیوٹر پروگرام اور تحقیقی کام پر ہوتا ہے۔
پاکستان میں کاپی رائٹ قانون:
پاکستان میں کاپی رائٹ کا تحفظ Copyright Ordinance 1962 کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق کسی بھی
شخص کی تخلیق اس کی ملکیت تصور کی جاتی ہے اور اس کے حقوق کا احترام نہ کرنے والے کو جرمانہ اور سزا دی جا سکتی ہے۔
ساتھ ہی، پاکستان نے مختلف بین الاقوامی معاہدوں (مثلاً Berne Convention) پر بھی دستخط کر رکھے ہیں تاکہ عالمی سطح
پر تخلیقات کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔
کاپی رائٹ کی اہمیت:
- تخلیق کار کا تحفظ:
یہ قانون تخلیق کار کو اس کے کام پر قانونی حق دیتا ہے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس کی محنت کو ناجائز طور پر استعمال نہ کر سکے۔ - علمی و ادبی ترقی:
جب مصنفین اور فنکار یہ جانتے ہیں کہ ان کی تخلیقات محفوظ ہیں تو وہ مزید جوش و جذبے کے ساتھ نئے کام تخلیق کرتے ہیں۔ - معاشی فائدہ:
کاپی رائٹ کے ذریعے تخلیق کار اپنی محنت سے آمدنی حاصل کرتا ہے، جو اسے مزید تحقیقی یا فنی سرگرمیوں میں مدد دیتی ہے۔ - جدت و اختراع کا فروغ:
یہ قانون معاشرے میں نئی سوچ اور اختراع کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کیونکہ لوگ اپنی کاوشوں کے چوری ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ - بین الاقوامی تعاون:
کاپی رائٹ عالمی سطح پر بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے مصنفین اور فنکاروں کی تخلیقات دنیا بھر میں محفوظ رہتی ہیں۔
نتیجہ:
کاپی رائٹ دراصل انسانی ذہنی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کے تحفظ کا دوسرا نام ہے۔ یہ نہ صرف مصنف یا فنکار کے حقوق کا
ضامن ہے بلکہ معاشرے میں علم، فن اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ اس کے ذریعے افراد کو اعتماد حاصل
ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا صلہ انہیں ملے گا اور کوئی دوسرا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لہٰذا، کاپی رائٹ کا
احترام کرنا ہر فرد اور ادارے کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔
سوال نمبر 20:
اداریہ (Editorial) کیا ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔
اداریہ کا مفہوم:
اداریہ صحافت کا ایک اہم اور سنجیدہ حصہ ہے جو کسی اخبار یا رسالے کی پالیسی، نقطہ نظر اور رائے کا عکاس ہوتا ہے۔ یہ
دراصل ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جو کسی اہم قومی، سماجی، سیاسی، اقتصادی یا بین الاقوامی مسئلے پر ادارتی کمیٹی یا
ادارہ خود اپنی رائے کی صورت میں شائع کرتا ہے۔ اداریہ کو اخبار کی اجتماعی آواز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ
ادارے کے موقف اور سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔
اداریہ کی خصوصیات:
- رائے کی عکاسی: اداریہ میں خبر کی طرح صرف اطلاع نہیں دی جاتی بلکہ ادارے کا نقطہ نظر اور تجزیہ بھی شامل ہوتا ہے۔
- اہم مسائل پر روشنی: یہ قومی یا بین الاقوامی مسائل پر عوامی شعور اجاگر کرتا ہے۔
- علمی و تحقیقی پہلو: اداریہ عام طور پر تحقیقی، مدلل اور سنجیدہ اسلوب میں لکھا جاتا ہے۔
- رائے عامہ کی تشکیل: یہ عوام کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور بعض اوقات کسی مسئلے پر قوم کی رائے ہموار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔
- غیر شخصی اسلوب: اداریہ میں مصنف کا نام شائع نہیں ہوتا بلکہ یہ ادارے کے اجتماعی موقف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
اداریہ کی اہمیت:
- رہنمائی کا ذریعہ:
اداریہ عوام کو پیچیدہ مسائل پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ - قومی شعور کی بیداری:
یہ قوم کو ملکی اور عالمی حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ - سیاست و معیشت پر اثر:
کئی بار اداریے حکومتی پالیسیوں یا عوامی فیصلوں پر اثرانداز ہوتے ہیں۔ - صحافتی وقار:
کسی اخبار یا رسالے کی سنجیدگی اور معیار کا اندازہ اس کے اداریے سے لگایا جاتا ہے۔
نتیجہ:
اداریہ صحافت کی ایک سنجیدہ اور معتبر صنف ہے جو خبر سے بڑھ کر تجزیہ اور رائے فراہم کرتی ہے۔ یہ کسی اخبار یا جریدے
کا دماغ اور دل ہوتا ہے جو قارئین کو صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ انہیں سوچنے اور اپنی رائے بنانے کی صلاحیت بھی عطا
کرتا ہے۔ یوں اداریہ نہ صرف صحافت کی روح ہے بلکہ رائے عامہ کی تشکیل اور قومی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
سوال نمبر 21:
اخباری کالم کیا ہے؟ اس کی اہمیت بیان کریں۔
اخباری کالم کا مفہوم:
اخباری کالم صحافت کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے جو کسی فرد کی ذاتی رائے، تجزیے اور مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ عام
طور پر اخبار یا رسالے میں ایک خاص جگہ (کالم) پر مستقل شائع ہوتا ہے۔ کالم نگار کسی مخصوص موضوع، مسئلے یا واقعے پر
اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور قاری کے ساتھ براہِ راست مکالمہ قائم کرتا ہے۔ کالم محض خبر یا اطلاع نہیں ہوتا بلکہ
یہ مصنف کی سوچ، طرزِ بیان اور تجزیے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔
اخباری کالم کی خصوصیات:
- رائے پر مبنی: کالم میں مصنف اپنی ذاتی رائے، تجزیہ یا تنقید پیش کرتا ہے۔
- اختصار کے ساتھ جامعیت: کالم عام طور پر مختصر ہوتا ہے مگر اس میں گہری بات اور موثر پیغام شامل ہوتا ہے۔
- دلچسپ اور عام فہم اسلوب: کالم کی زبان زیادہ سادہ، رواں اور قاری کے مزاج کے قریب ہوتی ہے۔ بعض اوقات مزاحیہ یا طنزیہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے۔
- موضوعات کا تنوع: کالم سیاست، سماج، معیشت، کھیل، ادب، مذہب یا روزمرہ زندگی کے کسی بھی پہلو پر لکھا جا سکتا ہے۔
- مسلسل اشاعت: کالم عام طور پر ایک ہی کالم نگار کا کسی خاص عنوان یا جگہ پر باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے، جیسے “گوشۂ خیال” یا “حرفِ آخر”۔
اخباری کالم کی اہمیت:
- رائے عامہ کی تشکیل:
کالم عوام کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے اور ان کی رائے کو کسی خاص سمت میں ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ - مسائل کا اجاگر ہونا:
کالم نگار معاشرتی، سیاسی یا انتظامی مسائل کو سامنے لا کر اربابِ اختیار کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ - عوامی ترجمانی:
اکثر کالم عوام کے جذبات، احساسات اور مسائل کی زبان بن جاتے ہیں۔ - علمی و فکری رہنمائی:
کئی کالم قاری کو نہ صرف حالاتِ حاضرہ پر آگاہی دیتے ہیں بلکہ علمی و فکری سطح پر بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ - تفریح اور ذوق:
بعض کالم مزاحیہ یا طنزیہ ہوتے ہیں جو قارئین کو ہنسی اور تفریح فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی اصلاحی پہلو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ - صحافت کا چہرہ:
ایک اخبار کی مقبولیت اور سنجیدگی کا بڑا دارومدار اس کے کالم نگاروں اور ان کے اسلوب پر ہوتا ہے۔
پاکستان میں اخباری کالم کی اہمیت:
پاکستان میں کالم نگاری نے صحافت کو ایک نیا رخ دیا۔ فیض احمد فیض، چراغ حسن حسرت، مولانا صلاح الدین احمد، اور بعد
ازاں رشید احمد صدیقی، عطاء الحق قاسمی، جاوید چوہدری، حسن نثار اور دیگر کالم نگاروں نے کالم کو ایک باوقار صنف
بنایا۔ سیاسی اور سماجی مسائل پر ان کے کالم نہ صرف عوامی شعور کی بیداری کا سبب بنے بلکہ حکومتی پالیسیوں پر بھی
اثرانداز ہوئے۔
نتیجہ:
اخباری کالم صحافت کی ایک دلکش، موثر اور بامقصد صنف ہے جو قاری کو محض اطلاع فراہم کرنے کے بجائے اس کی سوچ کو جلا
بخشتا ہے۔ یہ عوامی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، حکومتی و سماجی مسائل پر روشنی ڈالتا ہے اور رائے عامہ کی تشکیل میں
بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کالم اخبارات کی روح اور قاری کے دل کی آواز ہے۔
سوال نمبر 22:
پرنٹ لائن (Print Line) کیا ہے؟ وضاحت کریں۔
پرنٹ لائن کا مفہوم:
پرنٹ لائن سے مراد وہ مختصر تحریری عبارت ہے جو ہر اخبار، رسالے یا کتاب کے آخری یا ابتدائی حصے میں درج کی جاتی ہے۔
اس میں اس مطبوعہ مواد سے متعلق بنیادی معلومات درج ہوتی ہیں، جیسے ادارہ یا ادارتی بورڈ کا نام، مدیر اور ناشر کا
تعارف، مطبع (پریس) کا پتا، اشاعت کی تاریخ اور دیگر متعلقہ تفصیلات۔ پرنٹ لائن کو بعض اوقات “اشاعتی سوانح” بھی کہا
جاتا ہے کیونکہ اس میں مطبوعہ مواد کی شناخت اور قانونی حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔
پرنٹ لائن میں شامل بنیادی عناصر:
- ادارہ یا اخبار/رسالے کا نام:
جس کے تحت مطبوعہ مواد جاری کیا گیا ہو۔ - مدیر اور ناشر کا نام:
یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اشاعت کے ذمہ دار کون ہیں۔ - پریس یا مطبع کی معلومات:
وہ پریس جہاں اشاعت ہوئی ہو اس کا نام اور پتا درج کیا جاتا ہے۔ - اشاعت کی تاریخ:
اخبار یا رسالے کی اشاعت کی صحیح تاریخ پرنٹ لائن میں لازمی درج کی جاتی ہے۔ - کاپی رائٹ اور قانونی حیثیت:
بعض اوقات پرنٹ لائن میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مواد کاپی رائٹ کے تحت ہے اور بغیر اجازت نقل یا اشاعت نہیں کی جا سکتی۔
پرنٹ لائن کی اہمیت:
- قانونی پہچان: پرنٹ لائن کسی بھی اخبار یا رسالے کی قانونی حیثیت ثابت کرتی ہے اور متعلقہ اداروں کے ریکارڈ کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔
- شفافیت اور اعتماد: اس کے ذریعے قاری کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ مطبوعہ مواد کس ادارے یا شخص کی ذمہ داری پر شائع کیا گیا ہے۔
- ادارہ جاتی ذمہ داری: پرنٹ لائن میں موجود نام اور پتے ادارتی اور قانونی ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہیں۔
- تحقیقی اور حوالہ جاتی اہمیت: محققین اور قارئین کے لیے یہ معلومات اہم ہوتی ہیں کیونکہ اس سے اشاعت کی اصل تاریخ اور ماخذ کی تصدیق ممکن ہوتی ہے۔
- اشاعتی معیار: پرنٹ لائن کسی مطبوعہ مواد کے معیار اور پیشہ ورانہ اہتمام کی علامت سمجھی جاتی ہے۔
پاکستانی صحافت میں پرنٹ لائن کا کردار:
پاکستان میں اخبارات اور جرائد کے اجرا کے بعد سے پرنٹ لائن لازمی قرار دی گئی۔ ضابطۂ اخلاق کے تحت کوئی بھی اخبار
یا رسالہ پرنٹ لائن کے بغیر شائع نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قانونی تقاضہ ہے۔ اس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شائع شدہ
مواد کے پیچھے کون سا ادارہ یا شخصیت موجود ہے اور اگر کسی خبر یا مواد پر قانونی کارروائی کی ضرورت پیش آئے تو ذمہ
دار کون ہوگا۔
نتیجہ:
پرنٹ لائن صحافت اور اشاعت کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ محض ایک رسمی عبارت نہیں بلکہ اخبار، رسالے یا کتاب کی شناخت،
قانونی حیثیت اور ادارتی ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی مطبوعہ مواد غیر معتبر اور نامکمل تصور کیا جاتا
ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پرنٹ لائن اشاعت کی شناختی کارڈ اور قانونی پاسپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔
سوال نمبر 23:
ادارت سے کیا مراد ہے؟ سب ایڈیٹر کا کردار بیان کریں۔
ادارت کا مفہوم:
ادارت سے مراد وہ عمل اور فن ہے جس کے ذریعے کسی بھی اخبار، رسالے یا مطبوعہ مواد کو قارئین تک منظم اور ذمہ دارانہ
طریقے سے پہنچایا جاتا ہے۔ صحافت میں ادارت بنیادی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ خبر کی ترتیب، جانچ پڑتال، زبان و بیان
کی درستگی، سرخیوں کی تیاری اور مواد کی اشاعت سے قبل آخری فیصلہ سازی کا عمل ہے۔ سادہ الفاظ میں ادارت ایک ایسا
فلٹر ہے جو غیر مصدقہ، غیر معیاری اور غیر موزوں مواد کو روک کر صرف معتبر اور معیاری مواد قارئین کے سامنے پیش کرتا
ہے۔
ادارت کے بنیادی مقاصد:
- خبروں کی جانچ پڑتال: مواد کی صداقت اور درستگی کی تصدیق۔
- زبان اور اسلوب کی درستی: گرامر، املا اور جملوں کے بہاؤ کو بہتر بنانا۔
- خبروں کی درجہ بندی: اہم ترین خبریں نمایاں اور کم اہم خبریں پیچھے شائع کرنا۔
- اخلاقی ذمہ داری: غیر اخلاقی، غیر سنجیدہ یا متنازعہ مواد سے اجتناب۔
- قاری کی دلچسپی: مواد کو اس انداز میں پیش کرنا کہ قارئین کی توجہ قائم رہے۔
سب ایڈیٹر کا کردار:
سب ایڈیٹر اخبار یا رسالے کی ادارت کا نہایت اہم ستون ہے۔ اگر ایڈیٹر کسی ادارتی ٹیم کا سربراہ ہے تو سب ایڈیٹر اس
کے عملی مددگار اور خبر کی تکنیکی و ادبی نکھار دینے والے کاریگر ہیں۔ ان کا کام بظاہر پردے کے پیچھے ہوتا ہے لیکن
اخباری معیار اور وقار کا بڑا انحصار انہی کی محنت پر ہوتا ہے۔
سب ایڈیٹر کے فرائض:
- خبر کی ایڈیٹنگ:
رپورٹر کی فراہم کردہ خبر کو قاری کے لیے زیادہ جامع، واضح اور دلچسپ انداز میں ترتیب دینا۔ - سرخیاں بنانا:
ہر خبر کی جاذب نظر اور بامعنی سرخی تیار کرنا تاکہ قاری فوراً متوجہ ہو۔ - حقائق کی جانچ:
خبر کے اعداد و شمار، نام، تاریخ اور واقعات کی درستگی کی تصدیق کرنا۔ - زبان و بیان کی درستی:
املا، گرامر اور محاورات کو درست کر کے خبر کو معیاری زبان میں ڈھالنا۔ - اخلاقی نگرانی:
کسی بھی ایسی عبارت کو حذف کرنا جو غیر اخلاقی یا تعصبات پر مبنی ہو۔ - اخبار کی ترتیب میں معاونت:
یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی خبر کس جگہ اور کس نمایاں انداز میں شائع کی جائے۔
سب ایڈیٹر کی اہمیت:
- اخبار کی پیشہ ورانہ وقعت بڑھاتا ہے۔
- خبروں کو قاری کے لیے قابلِ فہم اور دلچسپ بناتا ہے۔
- ادارتی معیار قائم رکھتا ہے۔
- رپورٹر اور ایڈیٹر کے درمیان ایک اہم کڑی کا کردار ادا کرتا ہے۔
- اخبار کو غیر ضروری تنازعات اور غلطیوں سے بچاتا ہے۔
نتیجہ:
ادارت دراصل صحافت کا دل ہے اور سب ایڈیٹر اس دل کی دھڑکن کی مانند ہے۔ اگر ایڈیٹر پالیسی سازی اور بڑے فیصلوں میں
مصروف رہتا ہے تو سب ایڈیٹر روزمرہ خبروں کو سنوار کر ادارتی پالیسی کے مطابق ڈھالتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب
ایڈیٹر کے بغیر ادارت نامکمل ہے۔ اس کا کردار ہی کسی بھی اخبار یا رسالے کو معیاری، معتبر اور دلکش بناتا ہے۔