Students of AIOU Course Code 414 (Demography) can now prepare effectively with our specially designed solved guess paper. This paper includes the most important questions, solved answers, and exam-focused material selected from past trends and the course outline. It is an excellent resource for quick revision and helps you focus on the key areas of demography to perform well in exams. You can easily access the AIOU 414 Solved Guess Paper on our website mrpakistani.com and also watch supportive lectures on our YouTube channel Asif Brain Academy.
414 Code Demograph Solved Guess Paper
سوال نمبر 1:
ڈیموگرافی کی اہمیت و ضرورت پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ نیز ڈیموگرافی کی تاریخ بیان کریں۔
تعارف:
ڈیموگرافی آبادی کے سائنسی مطالعہ کو کہا جاتا ہے جس میں پیدائش، اموات، عمر، جنس، ہجرت، ازدواجی حیثیت، تعلیم اور
معاشی عوامل جیسے پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ علم سوسائٹی کے ڈھانچے اور مستقبل کے رجحانات کو سمجھنے میں
بنیادی
اہمیت رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں ڈیموگرافی ایک سماجی سائنس کے طور پر نہ صرف پالیسی سازی بلکہ تعلیم، صحت، معیشت،
اور ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے ناگزیر حیثیت اختیار کر چکی ہے۔
ڈیموگرافی کی اہمیت و ضرورت:
- قومی منصوبہ بندی: حکومتیں ڈیموگرافی کے اعداد و شمار کی مدد سے مستقبل کے لیے تعلیمی ادارے، اسپتال، رہائشی کالونیاں اور ٹرانسپورٹ کے نظام کی منصوبہ بندی کرتی ہیں۔
- معاشی ترقی: کسی ملک کی افرادی قوت کی صحیح تعداد اور عمر کے ڈھانچے کو جان کر صنعت، زراعت اور سروس سیکٹر کے لیے بہتر حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے۔
- آبادی کا دباؤ: ڈیموگرافی یہ وضاحت کرتی ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی وسائل پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور کن پالیسیوں سے اس دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔
- صحت اور فلاحی منصوبے: پیدائش اور اموات کی شرح جان کر حکومت بہتر ہیلتھ سروسز فراہم کر سکتی ہے، جیسے ویکسینیشن پروگرام یا زچہ و بچہ کی صحت کے منصوبے۔
- ہجرت اور شہری ترقی: دیہی سے شہری ہجرت کے رجحانات کو سمجھنے سے شہروں میں رہائش، پانی، روزگار اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں بہتر کی جا سکتی ہیں۔
- تعلیم: ڈیموگرافی کی مدد سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس عمر کے کتنے بچے اسکول جانے کی عمر میں ہیں، تاکہ تعلیمی اداروں کی منصوبہ بندی درست انداز میں ہو۔
- بین الاقوامی تعلقات: ڈیموگرافی سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار اقوام متحدہ، عالمی بینک اور دیگر اداروں کو ترقی پذیر ممالک کی ضروریات سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔
ڈیموگرافی کی تاریخ:
ڈیموگرافی کا تعلق قدیم زمانے سے ہے۔ قدیم تہذیبوں مثلاً مصر، یونان اور روم میں آبادی کی گنتی اور مردم شماری کے
ریکارڈ پائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ٹیکس وصول کرنا اور فوجی خدمات کے لیے افراد کی تعداد جاننا ہوتا تھا۔
جدید سائنسی انداز میں ڈیموگرافی کی بنیاد 17ویں صدی میں رکھی گئی۔ انگلینڈ کے جان گرونٹ (John Graunt) کو ڈیموگرافی
کا بانی مانا جاتا ہے، جنہوں نے 1662ء میں “Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality”
کے نام سے کتاب لکھی۔ انہوں نے اموات اور بیماریوں کے اعداد و شمار سے اہم نتائج اخذ کیے۔
بعد ازاں تھامس مالتھس (Thomas Malthus) نے 1798ء میں اپنی مشہور تصنیف “Essay on the Principle of Population”
میں آبادی اور وسائل کے درمیان تعلق کو بیان کیا۔ ان کا خیال تھا کہ آبادی تیزی سے بڑھتی ہے جبکہ وسائل محدود ہوتے
ہیں، جس کے نتیجے میں معاشی اور سماجی مسائل جنم لیتے ہیں۔
19ویں اور 20ویں صدی میں اعداد و شمار جمع کرنے کے جدید طریقے متعارف ہوئے اور مردم شماری کو منظم شکل دی گئی۔
آج ڈیموگرافی کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور سوشیو اکنامک ریسرچ کے ساتھ ایک بین الاقوامی اہمیت رکھنے والا علم ہے، جو اقوام
کے مستقبل کے فیصلوں میں رہنمائی کرتا ہے۔
نتیجہ:
ڈیموگرافی نہ صرف آبادی کی ساخت اور تبدیلیوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ یہ حکومتوں، ماہرینِ معیشت، ماہرینِ
تعلیم اور سوسائٹی کے ہر طبقے کے لیے پالیسی سازی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ڈیموگرافی کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس
طرح
انسان نے ابتدا میں محض اعداد و شمار اکٹھے کیے اور وقت گزرنے کے ساتھ اسے ایک مکمل سائنسی علم کی شکل دے دی۔ آج کے
دور میں ڈیموگرافی کے بغیر ترقی اور منصوبہ بندی کا تصور بھی ممکن نہیں۔
سوال نمبر 2:
مردم شماری سے کیا مراد ہے؟ مردم شماری کے مختلف طریقے بیان کریں۔ نیز ماتھس کے نظریہ آبادی کی وضاحت کریں۔
تعارف:
مردم شماری (Census) سے مراد ایک منظم اور جامع عمل ہے جس میں کسی مخصوص حدودِ ارضی کے اندر رہنے والی تمام افراد کی
تعداد
اور اُن کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی خصوصیات کے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ مردم شماری کا مقصد حکومتوں،
اداروں
اور محققین کو آبادی کی ساخت، پھیلاؤ اور تبدیلیوں کے بارے میں درست، قابلِ بھروسہ اور معیاری ڈیٹا فراہم کرنا ہوتا
ہے تاکہ
موثر پالیسی سازی اور منصوبہ بندی کی جا سکے۔
مردم شماری کا مفہوم اور بنیادی خصوصیات:
- جامعیت: مردم شماری کا ہدف پورے آبادی کا احاطہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی نمونے تک محدود رہنا۔
- نظامت اور ترتیب: یہ ایک منظم طریقۂ کار کے تحت مخصوص وقت یا مدت میں انجام پاتی ہے۔
- انفرادی سطح پر معلومات: ہر فرد کے بارے میں علیحدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے — عمر، جنس، ازدواجی حیثیت، تعلیم، پیشہ وغیرہ۔
- دورانیہ: عام طور پر مردم شماری ہر دس سال بعد کی جاتی ہے مگر بعض ممالک میں وقفہ مختلف ہو سکتا ہے۔
مردم شماری کے مقاصد:
- قومی سطح پر آبادی کا درست شمار معلوم کرنا۔
- تعلیم، صحت، رہائش اور انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی کے لیے ضروری اعداد و شمار فراہم کرنا۔
- انتظامی حدود میں آبادی کی تقسیم اور شہروں و دیہات کی ترقیاتی ضروریات کا تخمینہ لگانا۔
- انتخابی حلقہ بندی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور سماجی خدمات کی فراہمی میں مدد کرنا۔
مردم شماری کے مختلف طریقے (تفصیلی بیان):
-
جامع مردم شماری (Complete or Traditional Census):
یہ وہ روایتی طریقہ ہے جس میں شمار کنندگان ہر رہائشی یونٹ یا گھرانوں تک جا کر براہِ راست سوالنامے بھروا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ زیادہ تفصیلی اور مکمل ہوتا ہے۔
فوائد: تفصیلی ڈیٹا، تمام افراد کا احاطہ، مقامی سطح تک قابلِ اعتبار اعداد و شمار۔
نقصانات: مہنگا، وقت طلب، بسا اوقات سخت جغرافیائی یا سیکیورٹی مسائل کے باعث مشکل۔ -
نمونہ جاتی مردم شماری یا سروے (Sample Surveys):
اس میں پوری آبادی کا مطالعہ کرنے کے بجائے نمائندہ نمونے کا انتخاب کر کے اعداد و شمار حاصل کیے جاتے ہیں۔ بڑے پیمانے کے سرویز اقتصادی یا سماجی معلومات کے لیے مؤثر ہوتے ہیں۔
فوائد: کم قیمت، کم وقت، بار بار اپ ڈیٹ ممکن۔
نقصانات: مکمل مردم شماری جتنا تفصیلی یا مقامی سطح تک قابلِ اعتبار نہیں ہوتا؛ نمونے کی غلطی ممکن ہے۔ -
رجسٹر پر مبنی مردم شماری (Register-based Census):
اس طریقے میں سرکاری رجسٹروں مثلاً پیدائش و اموات کے ریکارڈ، رہائش کے پراپرٹی ریکارڈ، ٹیکس یا سماجی تحفظ کے ڈیٹا بیس کو یکجا کرکے مردم شماری کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ بہت سے یورپی ممالک میں یہ طریقہ رائج ہے۔
فوائد: معیاری، کم لاگت، مستقل اپ ڈیٹ، پیپر لیس۔
نقصانات: اگر رجسٹروں میں خامیاں ہوں تو ڈیٹا ناقص ہوگا؛ رازداری اور ڈیٹا انضمام کے اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ -
ڈی جیوٹ (de jure) بمقابلہ ڈی فیکٹو (de facto) مردم شماری:
de jure وہ شمار جہاں افراد کو اُن کے معمول کے رہائش گاہ کی بنیاد پر گنا جاتا ہے؛ جبکہ de facto اُس وقت شمار ہوتا ہے جب گنتی کسی مقام پر موجود افراد کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ دونوں طریقوں کے استعمال کے مختلف عملی اور پالیسیاتی نتائج ہوتے ہیں۔ -
الیکٹرانک اور موبائل مردم شماری (CAPI / Mobile & Web-based):
جدید مردم شماری میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے ٹیبلٹ یا موبائل فونز استعمال کیے جاتے ہیں؛ یا آن لائن فارم کے ذریعے خودشمارش (self-enumeration) بھی کی جا سکتی ہے۔
فوائد: فوری ویلیڈیشن، ڈیٹا انٹری میں غلطی کم، تیز اپڈیٹ۔
نقصانات: ڈیجیٹل ڈیویائسس کی کمی، تربیت کی ضرورت، ڈیجیٹل امتیاز (digital divide) کے مسائل۔ -
سیٹلائٹ اور جی آئی ایس پر مبنی طریقے (Remote Sensing & GIS):
سیٹلائٹ امیجز اور جغرافیائی نظام (GIS) کے ذریعے آبادکاری کے پیٹرن، غیرقانونی بستیاں اور آبادی کے کلسٹرز کا اندازہ لگایا جاتا ہے؛ خاص کر ایسی جگہوں پر جہاں زمینی رسائی مشکل ہو۔
فوائد: مقاماتی نقشہ سازی، رئل ٹائم نگرانی، روایتی گنتی کے متبادل یا تکمیلی ذریعہ۔
نقصانات: افراد کی خصوصیات معلوم نہیں ہوتیں؛ محض مقاماتی یا کثافت کا اندازہ ہوتا ہے۔ -
مخلوط یا ہائبرڈ طریقے (Hybrid Approaches):
رجسٹر، نمونہ جاتی سروے، سیٹلائٹ ڈیٹا اور الیکٹرونک انٹری کو ملا کر جدید ممالک ہائبرڈ مردم شماری اپناتے ہیں تاکہ لاگت کم اور درستگی زیادہ ہو۔ -
گھریلو سرویلنس اور کوہورٹ بیسڈ مشاہدہ (Demographic Surveillance / Cohort Studies):
مخصوص چھوٹے علاقوں میں مستقل بنیاد پر خاندانوں یا افراد کا مشاہدہ کر کے پیدائش، اموات، نقل مکانی کے رجحانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ تحقیقی مقاصد کے لیے اہم ہے مگر قومی مردم شماری کا نعم البدل نہیں۔
ڈیٹا جمع کرنے کے طریقۂ کار (Data Collection Modes):
- مقابلِ رو در رو انٹرویو (Face-to-face interviews)
- خود اندراجی (Self-enumeration) — آن لائن یا کاغذی فارم
- پراکسی انٹرویو (Proxy interviews) — گھر کا اک اور فرد معلومات دے دے
- الیکٹرونک ڈیٹا کلیکشن (CAPI) — ٹیبلٹ/موبائل کے ذریعے
- انتظامی ذرائع کا انضمام (Administrative data linkage)
معیار، رازداری اور اخلاقی پہلو:
مردم شماری کے دوران ڈیٹا کے معیار (accuracy)، رازداری (confidentiality) اور رضا مندی (consent) کو یقینی بنانا
ضروری ہے۔ اعداد و شمار کا غلط استعمال سماجی یا سیاسی مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے سخت قانونی اور تکنیکی حفاظتی
اقدامات ضروری ہیں۔
تعارفی ماثُس (مالتھس) کا نظریہ آبادی:
تھامس مالتھس (Thomas Malthus) نے 1798ء میں اپنی مشہور تصنیف “نسل کے اصول” میں آبادی اور وسائل کے تعلق پر ایک
بنیادی تھیس پیش کی۔ اُن کے مرکزی نکات درج ذیل ہیں:
- آبادی کی نمو: مالتھس نے کہا کہ آبادی ایک جیومیٹرک یا ہندسی تسلسل کے مطابق بڑھتی ہے (یعنی دوگنی وغیرہ)، اگر اسے روکا نہ جائے۔
- خوراک اور وسائل: اُن کے نزدیک خوراک اور بقیہ ضروریات جیسی چیزیں حسابی (arithmetical) رفتار سے بڑھتی ہیں، یعنی وسائل محدود رفتار سے بڑھیں گے۔
- عدم توازن اور نتائج: اگر آبادی بے قابو بڑھے اور وسائل محدود رہیں تو غذائی قلت، افلاس، بیماری اور جنگ جیسی ‘مثبت چیکس’ واقع ہوں گے جو آبادی کو قابو میں لے آئیں گے۔
- روک تھام کے طریقے: مالتھس نے ‘پریوینٹیو چیکس’ کا تصور بھی دیا — جن میں شعوری بر وقت شادی، اخلاقی پیروی، اور پیدائش میں کمی شامل ہے — تاکہ آبادی کی شرح قابو میں رہے۔
مالتھس کے نظریہ کے اثرات اور تنقید:
- مالتھسین نظریہ نے وسائل کی قلت، غذائی سکیورٹی اور پالیسی سازی میں اہم بحثیں جنم دیں اور بعد کے دور میں ‘نیو-مالتھسین’ خیالات نے ماحولیاتی تحفظ اور وسائلِ قدرتی کی حدود پر زور دیا۔
- تاہم مالتھس کی تنقید میں کہا گیا کہ اُنہوں نے ٹیکنالوجی، زرعی پیداوار میں بہتری اور مارکیٹ میکانزم کے اثرات کو کمِ قدر جانا۔ گرین ریولوشن اور جدید زرعی طریقے اس کی مثال ہیں جو خوراک کی پیداوار کو بڑی حد تک بڑھا چکے ہیں۔
- مزید برآں، آبادیاتی ٹرانزیشن تھیوری (Demographic Transition) بتاتی ہے کہ معاشی و سماجی ترقی کے ساتھ پیدائش اور اموات دونوں کی شرح میں تبدیلی آتی ہے، جس سے آبادیاتی نمو خود بخود مستحکم ہو سکتی ہے — یہ مالتھس کے سیدھے سادے پیشن گوئی سے مختلف منظر پیش کرتی ہے۔
عملی معنوں میں مالتھس کا نظریہ آج کس طرح دیکھا جاتا ہے؟
مالتھس کا بنیادی خیال — یعنی آبادی اور وسائل کے درمیان تناسب — آج بھی اہم ہے خاص طور پر جب ہم ماحول، پانی،
توانائی اور کاربن اخراج جیسے عالمی مسائل دیکھتے ہیں۔ البتہ جدید ماہرین اس میں ٹیکنالوجی، پالیسی، بین الاقوامی
تجارت، اور سماجی عوامل شامل کرتے ہوئے زیادہ پیچیدہ ماڈلز استعمال کرتے ہیں۔ نتیجتاً بعض حالات میں مالتھسی خدشات
درست ثابت ہوتے ہیں اور بعض میں ترقی نے ان خدشات کو کم بھی کیا ہے۔
نتیجہ:
مردم شماری ایک بنیادی اور لازمی عمل ہے جو ملکوں کو مستقبل کی منصوبہ بندی، وسائل کی تقسیم اور سماجی پالیسی سازی
میں درست سمت دیتا ہے۔ مردم شماری کے کئی طریقے ہیں — روایتی جامع گنتی، نمونہ جاتی سروے، رجسٹر پر مبنی طریقے،
الیکٹرانک کلیکشن اور جدید جیو-سپیشل تکنیک — جن میں انتخاب مقامی حالات، دستیاب وسائل اور مطلوبہ نتائج پر منحصر
ہوتا ہے۔ تھامس مالتھس کا نظریہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آبادی کے بڑھنے اور محدود وسائل کے درمیان تعلق کو نظر
انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر آج کے دور میں اس نظریہ کو ٹیکنالوجی، سماجی اصلاحات اور پالیسی اقدامات کے تناظر میں
دیکھا جانا چاہیے تاکہ متوازن اور پائیدار ترقی ممکن بنائی جا سکے۔
سوال نمبر 3:
عمر اور جنس کی ساخت سے کیا مراد ہے؟ آبادی کی ساخت کو عمر اور جنس کے لحاظ سے تقسیم کرنے کے حوالے سے تحریر کریں۔
تعارف:
جب ہم کسی آبادی کو اس کے افراد کی عمر اور جنسی کیفیت (مرد/عورت) کے لحاظ سے منظم انداز میں دیکھتے ہیں تو اسے عمر
و جنس کی
ساخت کہتے ہیں۔ یہ ساخت بتاتی ہے کہ آبادی میں مختلف عمر کے افراد کتنے ہیں اور مرد و عورت کا تناسب کیسا ہے۔ یہ
معلومات پالیسی
سازی، معیشت، صحت، تعلیم اور سماجی منصوبہ بندی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔
عمر کی ساخت (Age Structure) کیا ہوتی ہے؟
عمر کی ساخت سے مراد آبادی کا وہ بٹوارا ہے جس میں افراد کو مخصوص عمر کے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عموماً عمر
کے گروپ
پانچ یا دس سال کے وقفوں میں لیے جاتے ہیں، مثلاً 0–4، 5–9، 10–14، …، 80+۔ ہر عمر گروپ میں افراد کی تعداد سے معلوم
ہوتا ہے کہ
آبادی جوان ہے یا بوڑھی، پیدائش کی شرح کس حد تک ہے اور مستقبل میں روزگار، تعلیم و صحت کی ضروریات کیا ہوں گی۔
جنس کی ساخت (Sex Structure) کیا ہوتی ہے؟
جنس کی ساخت سے مراد مرد اور عورت کی تعداد اور نسبت ہوتی ہے۔ عام پیمانہ یہ ہے کہ کسی مخصوص علاقے میں مردوں کی
تعداد کو خواتین
کی تعداد کے مقابل رکھا جاتا ہے اور جنسی تناسب نکالا جاتا ہے۔ جنس کی ساخت سمجھ کر جنسی بنیاد پر مخصوص پالیسیز،
معاشی
مواقع اور سماجی پروگرام بنائے جاتے ہیں۔
عمر اور جنس کے لحاظ سے آبادی کو تقسیم کرنے کے بنیادی طریقے:
-
عمر کے گروہ (Age Groups):
معمول یہ ہے کہ آبادی کو 5 سال کے وقفوں میں تقسیم کیا جائے: 0–4، 5–9، 10–14، 15–19 … 80+. یہ تقسیم تجزیے اور پیرا میٹرک گراف (جیسا کہ آبادیاتی پیرامِڈ) کے لیے موزوں ہے۔ -
جنس کے حساب سے علیحدہ کاؤنٹ (Sex-disaggregated Counts):
ہر عمر گروہ کے اندر مردوں اور عورتوں کی علیحدہ علیحدہ تعداد درج کی جاتی ہے تا کہ عمر کے ساتھ جنسی تناسب معلوم کیا جا سکے۔ -
نسبتِ جنسی (Sex Ratio):
جنسی تناسب = (مردوں کی تعداد ÷ خواتین کی تعداد) × 100۔ نوٹ: بعض اوقات اسے فی ۱۰۰۰ خواتین کے مقابلے میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے؛ اس کا انتخاب ملکی رواج پر منحصر ہوتا ہے۔ -
انحصاری تناسب (Dependency Ratios):
یہ بتاتے ہیں کہ معیشت پر غیر ورکنگ عمر کے افراد کتنا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ عام فارمولے درج ذیل ہیں:
چائلڈ انحصاری تناسب = (۰–۱۴ سال کی آبادی ÷ ۱۵–۶۴ سال کی آبادی) × ۱۰۰۔
بوڑھے کا انحصاری تناسب = (۶۵+ سال کی آبادی ÷ ۱۵–۶۴ سال کی آبادی) × ۱۰۰۔
کل انحصاری تناسب = ((۰–۱۴) + (۶۵+)) ÷ (۱۵–۶۴) × ۱۰۰۔ -
میڈین عمر اور اوسط عمر:
میڈین عمر وہ عمر ہے جو آبادی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے (نصف اس عمر سے کم، نصف زیادہ)؛ اوسط عمر (Mean Age) مجموعی عمر کو افراد کی تعداد سے تقسیم کر کے نکلتی ہے۔ میڈین عمر آبادی کی عمومی عمرانی صورتحال جلدی بتا دیتی ہے۔ -
عمراتی پیرامِڈ (Population Pyramid):
یہ ایک گرافیکل پیشکش ہوتی ہے جس میں افق کی ایک جانب مردوں کی تعداد اور دوسری جانب عورتوں کی تعداد عمودی محور پر عمر گروپس کے لحاظ سے دکھائی جاتی ہے۔ پیرامِڈ کی شکل سے پالیسی ساز فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آبادی ‘جوان’ ہے، ‘بوڑھی’ ہے یا ‘مستحکم’۔
آبادیاتی پیرامِڈ کی عام اقسام اور ان کی تشریح:
- پھیلتی ہوئی شکل (Expansive): چوٹی وسیع اور تیز اوپر کی طرف تنگ ہوتی ہے — پیدائش اعلیٰ، اموات کم عمر میں نسبتاً زیادہ، نتیجتاً نوجوان آبادی۔
- محدود یا تنگ ہوتی شکل (Constrictive): نیچے کی تہہ پتلی — کم پیدائش، بالغ اور بزرگ افراد کا تناسب بڑھ رہا ہو۔
- مستحکم یا اسٹیبل شکل (Stationary): پیرامِڈ کے اطراف نسبتاً سیدھی — پیدائش اور اموات کم متغیر، آبادی میں سست نمو۔
مثالی حسابی مثال — انحصاری تناسب کی تفصیلی گنتی:
فرض کریں ایک ملک میں عمراتی تقسیم یوں ہے: ۰–۱۴ سال: ۳۰ فیصد، ۱۵–۶۴ سال: ۶۰ فیصد، ۶۵+ سال: ۱۰ فیصد۔
ہم کل آبادی کو ۱۰۰ مان کر حساب کریں گے، تب:
چائلڈ انحصاری تناسب = (۰–۱۴ ÷ ۱۵–۶۴) × ۱۰۰ = (۳۰ ÷ ۶۰) × ۱۰۰۔
قدم بہ قدم: ۳۰ ÷ ۶۰ = ۰٫۵ → ۰٫۵ × ۱۰۰ = ۵۰۔ لہٰذا چائلڈ انحصاری تناسب = ۵۰ فیصد۔
بوڑھا انحصاری تناسب = (۶۵+ ÷ ۱۵–۶۴) × ۱۰۰ = (۱۰ ÷ ۶۰) × ۱۰۰۔
قدم بہ قدم: ۱۰ ÷ ۶۰ = ۰٫۱۶۶۶۶… → ۰٫۱۶۶۶۶… × ۱۰۰ ≈ ۱۶٫۶۷۔ لہٰذا بوڑھا انحصاری تناسب ≈ ۱۶٫۶۷ فیصد۔
کل انحصاری تناسب = ((۳۰ + ۱۰) ÷ ۶۰) × ۱۰۰ = (۴۰ ÷ ۶۰) × ۱۰۰ = ۰٫۶۶۶۶… × ۱۰۰ ≈ ۶۶٫۶۷ فیصد۔
عمر و جنس کی ساخت کے اثرات و پالیسیاتی مضمرات:
- تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ: نوجوان آبادی والے ممالک کو اسکولوں، تکنیکی تربیت اور روزگار کی فراہمی میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ ‘آبادیاتی فائدہ’ حاصل کیا جا سکے۔
- صحت و فلاح: بچوں اور تولیدی عمر والی آبادی کے لیے ماں و بچہ صحت، امکانی حمل و زچگی کی خدمات اور حفاظتی ٹیکہ جات کی ضرورت بڑھ جاتی ہے؛ جبکہ بڑھتی ہوئی عمر والی آبادی کے لیے دائمی بیماریوں اور نرسنگ کی خدمات درکار ہوتی ہیں۔
- مزدور قوت اور معیشت: ورکنگ ایج آبادی کا سائز براہِ راست معیشت کی پیداواری صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے؛ نوجوان ہجوم کو اگر روزگار نہ ملے تو بے روزگاری اور سماجی مسائل بڑھ سکتے ہیں۔
- پینشن اور سماجی تحفظ: بڑھتی عمر والی آبادی پینشن سسٹم اور صحتیاتی اخراجات میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اس لیے مالی منصوبہ بندی ضروری ہے۔
- مرد/عورت تناسب کے اثرات: جنس میں شدید عدم توازن شادی کے بازار، سماجی کشیدگی، اور خواتین/مردوں کے لیے مخصوص پالیسیز میں خلل ڈال سکتا ہے۔
- ہجرت اور شہریت: مردوں یا عورتوں کی مخصوص عمراتی-جنسی گروہوں کی ہجرت آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کر سکتی ہے؛ جس سے مقامی لیبر مارکیٹ اور کمیونٹی کی ساخت بدل سکتی ہے۔
عمر و جنس کے تجزیے میں درپیش مسائل (Data Quality Issues):
- عمر کا غلط اندراج (Age Misreporting / Age Heaping): بعض معاشروں میں لوگ اپنی عمر گول نمبروں (مثلاً ۳۰، ۴۰) میں بتا دیتے ہیں۔ اس سے عمراتی تقسیم میں بگاڑ آتا ہے۔
- خواتین کا کم اندراج: بعض جگہوں پر ثقافتی یا انتظامی وجوہات کی بنا پر خواتین کی آبادی کم ریکارڈ ہوتی ہے۔
- موبائل یا عبوری آبادیوں کا انڈرکاؤنٹ: خرد بردی کارکنان، داخلی تارکینِ وطن یا عبوری باشندے مردم شماری میں چھوٹ سکتے ہیں۔
- پیدائش و اموات کے ناقص ریکارڈ: رجسٹریشن سسٹمز کے خامیوں کی وجہ سے عمر و جنس کے پیمانے متاثر ہو سکتے ہیں۔
عملی سفارشات برائے پالیسی ساز:
- مردم شماری اور سرویز میں ۵ سالہ عمراتی وقفوں کا استعمال معمول بنایا جائے اور مرد و عورت دونوں کا علیحدہ ڈیٹا یقینی بنایا جائے۔
- ڈیٹا اکٹھا کرنے کے دوران عمر کی جانچ (انیورسل شناختی کارڈز، پیدائش سرٹیفکیٹس) اور تربیت یافتہ عملہ فراہم کیا جائے تا کہ عمر کی درستی بڑھے۔
- پالیسی سازی میں میڈین عمر، انحصاری تناسب اور جنسی تناسب کو مرکزی پیمانے کے طور پر رکھا جائے تاکہ تعلیم، صحت، روزگار اور سماجی تحفظ کی منصوبہ بندی درست ہو۔
- جنس کے عدم توازن کی صورت میں مخصوص سماجی و اقتصادی پروگرام متعارف کیے جائیں جیسے خواتین کی کفالت، روزگار کی تربیت اور صنفی مساوات کے اقدامات۔
نتیجہ:
عمر اور جنس کی ساخت آبادی کا لازمی اور طاقتور تجزیاتی آلہ ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف موجودہ سماجی و اقتصادی حالات کی
تصویر واضح ہوتی ہے بلکہ مستقبل
کی منصوبہ بندی، وسائل کی تقسیم اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے حکمتِ عملی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ صحیح اور معیاری
عمراتی و جنسی ڈیٹا کے بغیر
پالیسی سازی ناقص رہ جاتی ہے، اس لیے مردم شماری اور مسلسل آبادیاتی مانیٹرنگ کو مضبوط بنانا ہر قوم کی ترقی کے لیے
ناگزیر ہے۔
سوال نمبر 4:
شیر خوار کی شرح اموات سے کیا مراد ہے؟ نیز شرح پیدائش ماپنے کے پیمانے کون کونسے ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔
تعارف:
آبادی کے مطالعے میں شرح پیدائش (Birth Rate) اور شرح اموات (Death Rate) بنیادی اہمیت کے حامل عناصر ہیں۔ ان ہی کی
بنیاد پر
کسی خطے کی آبادی کے بڑھنے یا گھٹنے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ خصوصاً شیر خوار بچوں کی شرح اموات ایک معاشرتی، معاشی
اور
طبی معیار کا پیمانہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ کسی بھی معاشرے کے صحت عامہ کے نظام کی کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی
طرح
شرح پیدائش کے مختلف پیمانے آبادی کے بڑھنے کی رفتار اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔
شیر خوار کی شرح اموات:
شیر خوار کی شرح اموات (Infant Mortality Rate) سے مراد ایک سال سے کم عمر بچوں کی اموات کی شرح ہے جو عام طور پر
فی ایک ہزار زندہ پیدا ہونے والے بچوں کے حساب سے نکالی جاتی ہے۔ اس کا حساب یوں کیا جاتا ہے:
شیر خوار شرح اموات = (ایک سال سے کم عمر بچوں کی اموات ÷ فی سال زندہ پیدا ہونے والے بچوں کی کل تعداد) ×
1000
یہ شرح کسی بھی ملک کے سماجی و معاشی حالات، صحت کی سہولیات، غذائی معیار، تعلیم، اور ماں کی صحت پر منحصر ہوتی ہے۔
ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح بہت کم ہے، جبکہ پسماندہ اور غریب ممالک میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔
اہم نکات:
- یہ شرح صحت عامہ اور غذائی معیار کا اہم پیمانہ ہے۔
- اعلیٰ شرح اموات غربت، ناخواندگی اور صحت کی سہولیات کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔
- کم شرح اموات جدید طبی سہولیات، تعلیم اور بہتر خوراک کی علامت ہے۔
شرح پیدائش ماپنے کے پیمانے:
شرح پیدائش کو مختلف پیمانوں سے ماپا جاتا ہے تاکہ آبادی میں اضافے کے صحیح رجحانات کا پتا چل سکے۔ ان میں سے اہم
درج ذیل ہیں:
- خام شرح پیدائش (Crude Birth Rate):
یہ شرح فی سال ایک ہزار افراد میں زندہ پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سب سے عام پیمانہ ہے لیکن یہ عمر اور جنس کے فرق کو نظرانداز کر دیتا ہے۔ - عام شرح تولید (General Fertility Rate):
اس پیمانے میں صرف عورتوں کی تولیدی عمر (15 سے 49 سال) کو شامل کیا جاتا ہے اور فی ایک ہزار عورتوں میں پیدا ہونے والے بچوں کی شرح معلوم کی جاتی ہے۔ یہ خام شرح پیدائش سے زیادہ درست نتائج فراہم کرتی ہے۔ - عمر کے حساب سے مخصوص شرح تولید (Age-Specific Fertility Rate):
اس میں مختلف عمر کے گروہوں کی عورتوں کے لحاظ سے شرح پیدائش نکالی جاتی ہے، مثلاً 15–19 سال، 20–24 سال وغیرہ۔ یہ پیمانہ آبادیاتی تحقیق میں نہایت مفید ہے۔ - کل شرح تولید (Total Fertility Rate):
یہ ایک عورت کی پوری تولیدی زندگی کے دوران اوسطاً پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کا اندازہ لگاتی ہے۔ یہ شرح پیدائش کے رجحانات کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مددگار ہے۔
نتیجہ:
شیر خوار کی شرح اموات کسی بھی معاشرے کے صحت اور ترقی کا آئینہ دار ہے۔ اگر یہ شرح زیادہ ہو تو یہ ماں اور بچے کی
صحت کے
کمزور نظام کو ظاہر کرتی ہے جبکہ کم شرح اموات ترقی اور سہولیات کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح شرح پیدائش ماپنے کے
مختلف
پیمانے آبادی کی موجودہ اور آئندہ صورتحال جاننے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے حکومتیں منصوبہ بندی،
صحت
عامہ کی بہتری اور وسائل کی تقسیم کو مؤثر بنا سکتی ہیں۔
سوال نمبر 6:
نقل مکانی کیا ہے؟ نقل مکانی کے آبادی پر اثرات تحریر کریں نیز نقل مکانی کرنے والوں کی خصوصیات مختصر بیان کریں۔
تعارف:
“نقل مکانی” سے مراد لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ مستقل یا عارضی سکونت کے لیے جانا ہے۔ یہ ایک سماجی اور معاشی
عمل ہے جس کے تحت لوگ بہتر روزگار، تعلیم، سہولتوں، امن و سلامتی یا قدرتی آفات سے بچنے کے لیے اپنی رہائش گاہ تبدیل
کرتے ہیں۔ نقل مکانی عموماً دو اقسام میں تقسیم کی جاتی ہے: اندرونی (ملک کے اندر) اور
بیرونی (ملک سے باہر)۔
نقل مکانی کے آبادی پر اثرات:
- شہری آبادی میں اضافہ: دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت سے شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھتی ہے۔
- دیہی آبادی میں کمی: نوجوان اور محنتی افراد شہروں کو ترجیح دیتے ہیں جس سے دیہی علاقے خالی ہوتے ہیں۔
- مزدور قوت کی تقسیم: نقل مکانی سے ایک علاقے میں مزدور زیادہ اور دوسرے میں کم ہو جاتے ہیں، جس سے معاشی توازن متاثر ہوتا ہے۔
- ثقافتی میل جول: مختلف علاقوں کے لوگ ایک جگہ آ کر نئی تہذیبی اور ثقافتی روایات کو جنم دیتے ہیں۔
- معاشی دباؤ: شہروں میں زیادہ آبادی کی وجہ سے روزگار، رہائش اور سہولیات پر دباؤ بڑھتا ہے۔
نقل مکانی کرنے والوں کی خصوصیات:
- زیادہ تر نوجوان: ہجرت کرنے والوں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بہتر مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔
- کم ہنرمند طبقہ: زیادہ تر دیہی افراد یا غیر ہنرمند لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔
- مردوں کی اکثریت: عام طور پر مرد پہلے ہجرت کرتے ہیں اور بعد میں اپنے خاندان کو ساتھ لے آتے ہیں۔
- تعلیم یافتہ افراد: بیرونِ ملک جانے والے افراد اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ یا ہنرمند ہوتے ہیں۔
- معاشی طور پر غیر مستحکم لوگ: اکثر وہی لوگ ہجرت کرتے ہیں جو اپنے علاقے میں غربت یا محدود وسائل کا شکار ہوتے ہیں۔
نتیجہ:
نقل مکانی ایک اہم سماجی و معاشی رجحان ہے جو آبادی کی تقسیم اور معیشت پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگرچہ یہ نئے
مواقع اور ثقافتی روابط فراہم کرتا ہے لیکن اس کے منفی پہلو بھی ہیں جیسے شہروں میں بھیڑ، بے روزگاری اور سہولیات پر
دباؤ۔ اس لیے ضروری ہے کہ نقل مکانی کے رجحانات کو متوازن کرنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جائے تاکہ یہ عمل معاشرتی
ترقی کا ذریعہ بن سکے۔
سوال نمبر 7:
مختلف ادوار میں پاکستان کی شرح افزائش آبادی کا جائزہ لیں۔ نیز شیر بندی میں سہولیات کی فراہمی کیا کردار ادا کرتی ہیں؟
تعارف:
آبادی کی افزائش کسی بھی ملک کی سماجی، معاشی اور معاشرتی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان
ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں آبادی میں اضافہ بہت تیز رفتاری سے ہوا ہے۔ شرح افزائش آبادی کا تعلق پیدائش کی شرح،
اموات کی شرح اور شیر خوار بچوں کی بقاء سے ہے۔ مختلف ادوار میں یہ شرح بدلتی رہی ہے اور آج بھی یہ ایک اہم مسئلہ
ہے۔
پاکستان میں شرح افزائش آبادی کا جائزہ:
- 1947 تا 1960: قیام پاکستان کے ابتدائی برسوں میں شرح افزائش آبادی نسبتاً کم (تقریباً 2 فیصد سالانہ) تھی کیونکہ صحت عامہ کی سہولتیں محدود تھیں اور شرح اموات زیادہ تھی۔
- 1960 تا 1980: صحت، ادویات اور ویکسینیشن کی سہولتوں میں اضافے سے شرح اموات کم ہوئی لیکن شرح پیدائش زیادہ رہی، جس کے باعث شرح افزائش تیزی سے 3 فیصد کے قریب پہنچ گئی۔
- 1980 تا 2000: فیملی پلاننگ پروگرامز کے آغاز اور تعلیم میں بہتری کے باعث شرح افزائش میں کمی آئی مگر پھر بھی یہ تقریباً 2.5 فیصد رہی۔
- 2000 کے بعد: شہری کاری، تعلیم، میڈیا اور آگاہی مہمات کی بدولت شرح افزائش میں مزید کمی واقع ہوئی لیکن یہ اب بھی 1.9 سے 2 فیصد کے درمیان ہے جو خطے کے کئی ممالک سے زیادہ ہے۔
شیر بندی میں سہولیات کی فراہمی کا کردار:
- بچے کی صحت: ابتدائی چھ ماہ تک ماں کا دودھ پلانے سے بچے کو ضروری غذائیت اور بیماریوں سے بچاؤ کی قوت ملتی ہے، جس سے شیر خوار اموات کم ہوتی ہیں۔
- ماں کی صحت: شیر بندی ماں کو جسمانی طور پر صحت مند رکھتی ہے اور بار بار حمل سے بچاؤ میں بھی مدد دیتی ہے۔
- شرح افزائش پر اثر: اگر شیر بندی کی سہولت اور آگاہی زیادہ ہو تو ماؤں کے درمیان حمل کا وقفہ بڑھتا ہے، جو شرح افزائش کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- معاشی فائدہ: ماں کا دودھ ایک قدرتی اور سستا ذریعہ ہے جس سے غریب خاندانوں پر غذائی اخراجات کا بوجھ کم ہوتا ہے۔
- سرکاری کردار: ہسپتالوں، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور آگاہی مہمات کے ذریعے شیر بندی کے فوائد عام کیے جائیں تو شرح افزائش پر قابو پانے میں آسانی ہوتی ہے۔
نتیجہ:
پاکستان میں مختلف ادوار کے دوران شرح افزائش آبادی نے معیشت اور سماج پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ
کچھ بہتری آئی ہے مگر اب بھی یہ شرح زیادہ ہے۔ شیر بندی کی سہولیات اور آگاہی اس سلسلے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی
ہیں کیونکہ یہ بچوں کی صحت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ شرح افزائش میں کمی لانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے حکومت اور
عوام دونوں کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔
سوال نمبر 8:
پاکستان میں پائی جانے والی اہم بیماریوں اور ان کی وجوہات کا مختصر جائزہ لیں۔
تعارف:
صحت مند معاشرہ کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں متعدد بیماریاں عوامی
صحت کے بڑے مسائل کا باعث ہیں۔ یہ بیماریاں ماحولیاتی حالات، سماجی رویوں، خوراک کی کمی اور صحت کی سہولتوں کی کمی
کے باعث پھیلتی ہیں۔
پاکستان میں پائی جانے والی اہم بیماریاں:
- ملیریا: یہ بیماری مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہے اور پاکستان کے گرم و مرطوب علاقوں میں عام ہے۔ بخار، کپکپی اور پسینہ اس کی نمایاں علامات ہیں۔
- ہیپاٹائٹس (B اور C): غیر صحت مند سرنجوں، آلودہ پانی اور خون کے غیر محفوظ انتقال کے باعث یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ جگر کو متاثر کرتی ہے۔
- تپ دق (TB): غربت، زیادہ بھیڑ بھاڑ اور غذائی قلت کے باعث یہ بیماری عام ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے۔
- ڈائریا اور پیچش: گندے پانی اور غیر معیاری خوراک کے استعمال سے یہ بیماریاں عام ہیں، خاص طور پر بچوں میں۔
- شوگر اور بلڈ پریشر: غیر متوازن خوراک، ورزش کی کمی اور ذہنی دباؤ ان بیماریوں کی بڑی وجوہات ہیں جو شہروں میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔
- پولیو: ویکسینیشن مہمات کے باوجود بعض علاقوں میں پولیو اب بھی موجود ہے، جو معذوری کا باعث بنتا ہے۔
اہم وجوہات:
- صاف پانی اور نکاسی آب کی کمی۔
- غیر معیاری صحت کی سہولیات اور علاج مہنگا ہونا۔
- غذائی قلت اور غیر متوازن خوراک۔
- آبادی میں تیزی سے اضافہ اور شہروں میں زیادہ بھیڑ۔
- عوام میں بیماریوں اور صفائی ستھرائی کے بارے میں آگاہی کی کمی۔
- ماحولیاتی آلودگی اور غیر صحت مند طرزِ زندگی۔
نتیجہ:
پاکستان میں صحت کے مسائل کا بڑا سبب غربت، جہالت اور سہولتوں کی کمی ہے۔ اگر صاف پانی، معیاری خوراک، ویکسینیشن اور
بہتر صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں اور عوام میں آگاہی پھیلائی جائے تو ان بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صحت
مند معاشرہ ہی ایک مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔
سوال نمبر 9:
پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ یہاں عورتوں اور بچوں میں اموات کی اہم وجوہات کیا ہیں؟
تعارف:
پاکستان میں عورتوں اور بچوں کی صحت ایک نہایت اہم قومی مسئلہ ہے۔ جدید دور کے باوجود شرح اموات خاص طور پر زچگی کے
دوران عورتوں اور پیدائش کے پہلے پانچ سال میں بچوں کی شرح اموات دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی
وجوہات غربت، سہولیات کی کمی، کم علمی اور غذائی قلت ہیں۔
عورتوں میں اموات کی وجوہات:
- زچگی کے دوران پیچیدگیاں: خون کی زیادتی، غیر تربیت یافتہ دائیوں پر انحصار اور ہسپتالوں تک بروقت نہ پہنچ پانا۔
- غذائی قلت: آئرن اور وٹامنز کی کمی سے کمزوری، خون کی کمی (اینیمیا) اور قوت مدافعت میں کمی۔
- خاندانی دباؤ: کم عمری میں شادی اور بار بار حمل عورتوں کی صحت کو شدید متاثر کرتا ہے۔
- صحت کی سہولیات کی کمی: دیہی علاقوں میں ماہر ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کی کمی کے باعث بروقت علاج نہ ہو پانا۔
- سماجی اور ثقافتی رکاوٹیں: عورتوں کا تنہا ہسپتال نہ جا سکنا اور مردوں پر انحصار۔
بچوں میں اموات کی وجوہات:
- نوزائیدہ بچوں کی اموات: پیدائش کے فوراً بعد انفیکشن، کم وزن اور نالائق دائیوں کی غفلت۔
- متعدی بیماریاں: نمونیا، خسرہ، اسہال اور ملیریا بچوں کی سب سے بڑی قاتل بیماریاں ہیں۔
- پولیو اور دیگر بیماریوں کی ویکسینیشن میں کمی: بعض علاقوں میں ویکسینیشن نہ ہونا یا والدین کی لاعلمی۔
- غذائی قلت: بچوں میں کمزور مدافعتی نظام اور ترقی میں رکاوٹ۔
- صاف پانی اور صفائی کی کمی: گندا پانی اور غیر صحت مند ماحول بچوں میں بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔
اہم عوامل:
- غربت اور کمزور معیشت۔
- تعلیم کی کمی، خاص طور پر خواتین میں۔
- صحت کے شعبے پر کم توجہ اور فنڈز کی کمی۔
- دیہی اور پسماندہ علاقوں میں سہولیات کی عدم دستیابی۔
- آبادی میں بے تحاشا اضافہ اور وسائل کی کمی۔
نتیجہ:
پاکستان میں عورتوں اور بچوں کی اموات کی شرح کم کرنے کے لیے بنیادی صحت مراکز کو فعال بنانا، عوام میں آگاہی پیدا
کرنا، غذائی قلت کو دور کرنا اور خواتین کی تعلیم کو فروغ دینا ضروری ہے۔ حکومت اور عوام دونوں کی مشترکہ کوششیں ہی
ایک صحت مند اور محفوظ معاشرہ تشکیل دے سکتی ہیں۔
سوال نمبر 10:
اموات کے مطالعہ میں تعلیم اور ازدواجی حیثیت کی اہمیت بیان کریں۔
تعارف:
آبادی کے سائنسی مطالعے میں شرح اموات (Mortality Rate) ایک نہایت اہم عنصر ہے۔ اموات کی وجوہات اور ان سے متعلقہ
عوامل کا اندازہ لگانے کے لیے عمر، جنس، تعلیم اور ازدواجی حیثیت کو خاص طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان میں تعلیم اور
ازدواجی حیثیت دونوں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ براہِ راست انسان کے طرزِ زندگی، صحت، سہولیات تک رسائی
اور ذہنی سکون پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
تعلیم کی اہمیت:
- صحت سے آگاہی: تعلیم یافتہ افراد بیماریوں کی وجوہات اور ان سے بچاؤ کے طریقے بہتر طور پر جانتے ہیں۔
- بہتر علاج: پڑھے لکھے افراد بروقت طبی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جھوٹے توہمات سے بچتے ہیں۔
- غذائی بہتری: تعلیم خواتین اور مردوں کو متوازن غذا کی اہمیت سمجھنے میں مدد دیتی ہے جس سے بچوں اور ماؤں کی شرح اموات کم ہوتی ہے۔
- بچوں کی صحت پر اثر: خاص طور پر ماں کی تعلیم بچوں کی بقا اور بہتر پرورش میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
- شرح اموات میں کمی: تحقیق سے ثابت ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد میں اموات کی شرح ناخواندہ افراد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔
ازدواجی حیثیت کی اہمیت:
- ازدواجی زندگی اور سماجی تعاون: شادی شدہ افراد کو معاشرتی اور نفسیاتی سہارا حاصل ہوتا ہے جو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور صحت بہتر بناتا ہے۔
- بچوں کی پرورش: شادی شدہ خواتین اپنے بچوں کی دیکھ بھال بہتر طور پر کر سکتی ہیں جس سے شرح اموات میں کمی آتی ہے۔
- تنہائی کے اثرات: غیر شادی شدہ، بیوہ یا طلاق یافتہ افراد میں ذہنی دباؤ زیادہ ہونے کے باعث بیماریوں اور قبل از وقت موت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
- معاشی فوائد: شادی شدہ خاندان اکثر معاشی طور پر زیادہ مستحکم ہوتے ہیں جس سے بہتر صحت کی سہولیات میسر آتی ہیں۔
- صحت مند عادات: شادی شدہ افراد زیادہ تر منظم اور محتاط طرزِ زندگی اپناتے ہیں جو اموات کی شرح کم کرنے میں معاون ہے۔
اہم عوامل:
- پڑھی لکھی خواتین کا شرح اموات پر سب سے نمایاں اثر ہوتا ہے۔
- غیر شادی شدہ یا اکیلے رہنے والے افراد میں بیماری اور اموات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
- تعلیم اور ازدواجی حیثیت دونوں مل کر صحت مند معاشرے کی تشکیل میں مددگار ہیں۔
نتیجہ:
اموات کے مطالعہ میں تعلیم اور ازدواجی حیثیت دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیم انسان کو بیماریوں سے بچاؤ، بہتر
خوراک اور علاج کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جبکہ ازدواجی حیثیت نفسیاتی سکون اور سماجی تعاون فراہم کرتی ہے۔ اس لیے شرح
اموات میں کمی لانے کے لیے تعلیم کے فروغ اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔
سوال نمبر 10:
اموات کے مطالعہ میں تعلیم اور ازدواجی حیثیت کی اہمیت بیان کریں۔
تعارف:
آبادی کے سائنسی مطالعے میں شرح اموات (Mortality Rate) ایک نہایت اہم عنصر ہے۔ اموات کی وجوہات اور ان سے متعلقہ
عوامل کا اندازہ لگانے کے لیے عمر، جنس، تعلیم اور ازدواجی حیثیت کو خاص طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان میں تعلیم اور
ازدواجی حیثیت دونوں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ براہِ راست انسان کے طرزِ زندگی، صحت، سہولیات تک رسائی
اور ذہنی سکون پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
تعلیم کی اہمیت:
- صحت سے آگاہی: تعلیم یافتہ افراد بیماریوں کی وجوہات اور ان سے بچاؤ کے طریقے بہتر طور پر جانتے ہیں۔
- بہتر علاج: پڑھے لکھے افراد بروقت طبی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جھوٹے توہمات سے بچتے ہیں۔
- غذائی بہتری: تعلیم خواتین اور مردوں کو متوازن غذا کی اہمیت سمجھنے میں مدد دیتی ہے جس سے بچوں اور ماؤں کی شرح اموات کم ہوتی ہے۔
- بچوں کی صحت پر اثر: خاص طور پر ماں کی تعلیم بچوں کی بقا اور بہتر پرورش میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
- شرح اموات میں کمی: تحقیق سے ثابت ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد میں اموات کی شرح ناخواندہ افراد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔
ازدواجی حیثیت کی اہمیت:
- ازدواجی زندگی اور سماجی تعاون: شادی شدہ افراد کو معاشرتی اور نفسیاتی سہارا حاصل ہوتا ہے جو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور صحت بہتر بناتا ہے۔
- بچوں کی پرورش: شادی شدہ خواتین اپنے بچوں کی دیکھ بھال بہتر طور پر کر سکتی ہیں جس سے شرح اموات میں کمی آتی ہے۔
- تنہائی کے اثرات: غیر شادی شدہ، بیوہ یا طلاق یافتہ افراد میں ذہنی دباؤ زیادہ ہونے کے باعث بیماریوں اور قبل از وقت موت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
- معاشی فوائد: شادی شدہ خاندان اکثر معاشی طور پر زیادہ مستحکم ہوتے ہیں جس سے بہتر صحت کی سہولیات میسر آتی ہیں۔
- صحت مند عادات: شادی شدہ افراد زیادہ تر منظم اور محتاط طرزِ زندگی اپناتے ہیں جو اموات کی شرح کم کرنے میں معاون ہے۔
اہم عوامل:
- پڑھی لکھی خواتین کا شرح اموات پر سب سے نمایاں اثر ہوتا ہے۔
- غیر شادی شدہ یا اکیلے رہنے والے افراد میں بیماری اور اموات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
- تعلیم اور ازدواجی حیثیت دونوں مل کر صحت مند معاشرے کی تشکیل میں مددگار ہیں۔
نتیجہ:
اموات کے مطالعہ میں تعلیم اور ازدواجی حیثیت دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیم انسان کو بیماریوں سے بچاؤ، بہتر
خوراک اور علاج کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جبکہ ازدواجی حیثیت نفسیاتی سکون اور سماجی تعاون فراہم کرتی ہے۔ اس لیے شرح
اموات میں کمی لانے کے لیے تعلیم کے فروغ اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔
سوال نمبر 11:
آبادی کی ساخت کے اعداد و شمار کی اہمیت بیان کریں نیز بالیدگی سے متعلق مختلف رابیوجرافک عوامل کون کونسے ہیں؟
تعارف:
آبادی کی ساخت (Population Structure) کے اعداد و شمار سماجی، معاشی اور معاشرتی منصوبہ بندی میں نہایت بنیادی حیثیت
رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے کسی ملک یا علاقے کی آبادی کی عمر، جنس، تعلیمی سطح، پیشہ، ازدواجی حیثیت اور شہری و دیہی
تقسیم کو جانچا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار آبادی کی پالیسیوں، وسائل کے بہتر استعمال اور ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے
بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
آبادی کی ساخت کے اعداد و شمار کی اہمیت:
- معاشی منصوبہ بندی: عمر اور جنس کی تقسیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ محنت کش طبقہ میں شامل ہیں اور کتنے افراد زیرِ کفالت ہیں۔
- تعلیمی منصوبہ بندی: بچوں اور نوجوانوں کی تعداد کی بنیاد پر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے قیام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
- صحت کے منصوبے: بچوں، خواتین اور بوڑھوں کی شرح کو دیکھتے ہوئے ہسپتالوں اور طبی سہولیات کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔
- شہری و دیہی تقسیم: دیہی و شہری آبادی کے تناسب سے ترقیاتی بجٹ اور انفراسٹرکچر (سڑکیں، پانی، بجلی وغیرہ) کی تقسیم کی جاتی ہے۔
- سماجی پالیسی سازی: ازدواجی حیثیت اور خواندگی کی بنیاد پر خاندانوں اور خواتین کے لیے فلاحی منصوبے مرتب کیے جاتے ہیں۔
بالیدگی سے متعلق مختلف رابیوجرافک عوامل:
آبادی کی بالیدگی (Population Growth) کئی عوامل پر منحصر ہے جنہیں ڈیموگرافک (Demographic) عناصر کہا جاتا ہے۔ ان
میں سب سے اہم درج ذیل ہیں:
- شرح پیدائش (Birth Rate): کسی ملک میں پیدا ہونے والے بچوں کی شرح آبادی کی بڑھوتری کا بنیادی عنصر ہے۔ زیادہ شرح پیدائش آبادی میں تیزی سے اضافہ کرتی ہے۔
- شرح اموات (Death Rate): اگر شرح اموات کم ہو تو آبادی میں اضافہ زیادہ تیز ہوتا ہے، جبکہ زیادہ اموات آبادی کی ترقی کو سست کر دیتی ہیں۔
- شرح ہجرت (Migration Rate): لوگوں کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا آبادی کی ساخت اور بالیدگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔
- شرح تولید (Fertility Rate): خواتین کی زرخیزی اور فی عورت پیدا ہونے والے بچوں کی اوسط تعداد آبادی کے بڑھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔
- اوسط عمر (Life Expectancy): اگر کسی ملک میں اوسط عمر زیادہ ہے تو زیادہ لوگ محنت کش طبقے میں شامل رہتے ہیں اور آبادی کی قوتِ کار بڑھتی ہے۔
- عمر کی ساخت (Age Structure): نوجوانوں کی زیادہ تعداد آبادی میں تیزی سے اضافے کا سبب بنتی ہے، جبکہ بوڑھی آبادی ترقی کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔
- ازدواجی حیثیت: شادی کی اوسط عمر اور شرحِ نکاح آبادی کی شرحِ پیدائش پر براہِ راست اثر ڈالتی ہے۔
نتیجہ:
آبادی کی ساخت کے اعداد و شمار قومی منصوبہ بندی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان سے صحت، تعلیم، معاشی ترقی اور سماجی بہبود
کے منصوبے مؤثر انداز میں بنائے جا سکتے ہیں۔ جبکہ بالیدگی کے عوامل جیسے پیدائش، اموات، ہجرت، تولید اور عمر کی
ساخت آبادی کی رفتار اور سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ایک متوازن اور پائیدار معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان عوامل کو
مد نظر رکھ کر پالیسیاں ترتیب دی جائیں۔
سوال نمبر 12:
زندگی کے دورانیہ اور درازی عمر کی تعریف کریں نیز ان دونوں کے درمیان فرق مثالوں سے واضح کریں۔
تعارف:
انسان کی زندگی کی طوالت اور اس کے دورانیے کے مطالعے کو ڈیموگرافی میں نہایت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ پہلو صحت عامہ،
معاشرتی بہبود، اور ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ دو اصطلاحات خاص طور پر قابلِ ذکر
ہیں: زندگی کا دورانیہ (Life Span) اور درازی عمر (Life Expectancy)۔
زندگی کا دورانیہ (Life Span):
کسی جاندار کی ممکنہ زیادہ سے زیادہ عمر جسے وہ فطری حالات میں گزار سکتا ہے، زندگی کا دورانیہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک
حیاتیاتی حد ہے جس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔
مثال: انسانی زندگی کا حیاتیاتی دورانیہ تقریباً 120 سال تک ہے، اگرچہ زیادہ تر لوگ اس عمر کو نہیں پہنچ
پاتے۔
درازی عمر (Life Expectancy):
کسی مخصوص معاشرے یا ملک میں ایک فرد کی اوسط متوقع عمر جس تک وہ عموماً زندہ رہتا ہے، درازی عمر کہلاتی ہے۔ یہ صحت،
خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولیات اور ماحولیاتی حالات پر منحصر ہوتی ہے۔
مثال: جاپان میں اوسط درازی عمر تقریباً 84 سال ہے، جبکہ بعض افریقی ممالک میں یہ محض 50 تا 60 سال ہے۔
فرق (Life Span اور Life Expectancy میں):
- حیاتیاتی بمقابلہ سماجی: زندگی کا دورانیہ حیاتیاتی حد ہے جبکہ درازی عمر معاشرتی اور ماحولیاتی عوامل پر منحصر ہے۔
- مطلق اور اوسط: زندگی کا دورانیہ ایک مطلق زیادہ سے زیادہ حد ہے، جبکہ درازی عمر ایک اوسط (Average) ہے۔
- تغیر پذیری: زندگی کے دورانیہ میں زیادہ فرق نہیں آتا، لیکن درازی عمر وقت اور حالات کے ساتھ بدل سکتی ہے۔
- مثال: انسانی دورانیہ آج بھی تقریباً 120 سال ہے لیکن اوسط درازی عمر مختلف ممالک میں 50، 70 یا 80 سال تک مختلف ہوتی ہے۔
اہم نکات:
- زندگی کا دورانیہ جینیاتی اور فطری حدود پر منحصر ہے۔
- درازی عمر میں اضافہ طبی سہولیات، تعلیم، اور بہتر خوراک کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔
- سماجی ترقی اور صحت عامہ کی پالیسیوں کا براہِ راست اثر درازی عمر پر پڑتا ہے۔
نتیجہ:
زندگی کا دورانیہ ایک فطری اور حیاتیاتی حد ہے جبکہ درازی عمر انسان کے سماجی اور معاشی حالات کا عکاس ہے۔ بہتر صحت
کے نظام اور معیاری زندگی کے ذریعے درازی عمر میں اضافہ ممکن ہے، تاہم زندگی کے دورانیہ کی حیاتیاتی حد کو عبور کرنا
ممکن نہیں۔ یوں دونوں تصورات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مگر اپنی نوعیت میں مختلف ہیں۔
سوال نمبر 13:
آبادی کی ساخت کے اعداد و شمار کی اہمیت بیان کریں نیز بالیدگی سے متعلق مختلف ڈیموگرافک عوامل کون کونسے ہیں؟
تعارف:
آبادی کی ساخت کے اعداد و شمار (Population Structure Statistics) ڈیموگرافی کے بنیادی عناصر میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ
نہ صرف کسی ملک کی سماجی و معاشی حالت کا عکس پیش کرتے ہیں بلکہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بھی اہم رہنمائی فراہم
کرتے ہیں۔ آبادی کی ساخت کا مطالعہ عموماً عمر، جنس، تعلیم، پیشہ، اور رہائشی تقسیم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
آبادی کی ساخت کے اعداد و شمار کی اہمیت:
- قومی منصوبہ بندی: عمر اور جنس کی تقسیم کے ذریعے حکومت صحت، تعلیم، روزگار اور رہائش کے شعبوں میں درست منصوبہ بندی کر سکتی ہے۔
- معاشی ترقی: ورکنگ ایج گروپ (15 تا 64 سال) کے تناسب سے یہ تعین ہوتا ہے کہ کتنے افراد ملک کی معیشت میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔
- تعلیمی منصوبہ بندی: بچوں اور نوجوانوں کی تعداد کے اعداد و شمار تعلیمی اداروں کی طلب و رسد کے درمیان توازن قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
- صحت عامہ: بوڑھے افراد کی تعداد بڑھنے سے صحت عامہ اور سوشل سیکیورٹی پر خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے۔
- علاقائی ترقی: شہری و دیہی آبادی کے تناسب سے بنیادی سہولیات جیسے سڑکیں، پانی، بجلی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
بالیدگی (Growth) سے متعلق ڈیموگرافک عوامل:
آبادی کی بالیدگی دراصل مختلف ڈیموگرافک عوامل پر منحصر ہے جو براہ راست پیدائش، اموات اور ہجرت کے تناسب کو متاثر
کرتے ہیں۔ اہم عوامل درج ذیل ہیں:
- شرح پیدائش (Birth Rate): کسی ملک میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد براہ راست آبادی کے حجم میں اضافہ کرتی ہے۔
- شرح اموات (Death Rate): اموات کی شرح میں کمی آبادی کی تیز رفتار بڑھوتری کا باعث بنتی ہے۔
- شرح ہجرت (Migration Rate): بیرونی یا داخلی ہجرت آبادی کی ساخت اور بالیدگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر دیہی سے شہری ہجرت شہروں کی آبادی کو بڑھا دیتی ہے۔
- درازی عمر (Life Expectancy): جب اوسط عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو بوڑھی آبادی کا تناسب بڑھتا ہے جو صحت اور سماجی تحفظ کے نئے تقاضے پیدا کرتا ہے۔
- شرح افزائش (Fertility Rate): خواتین کی زرخیزی کی شرح جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آبادی کی بالیدگی تیز ہوگی۔
- معاشی و تعلیمی عوامل: اعلیٰ تعلیم اور بہتر معیشت شرح پیدائش کو کم کر کے آبادی کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اہم نکات:
- آبادی کی ساخت معیشت، سماج اور ریاستی پالیسیوں کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔
- بالیدگی سے متعلق عوامل میں شرح پیدائش، شرح اموات اور ہجرت سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔
- آبادی کے درست اعداد و شمار کے بغیر ترقیاتی منصوبہ بندی ممکن نہیں۔
نتیجہ:
آبادی کی ساخت کے اعداد و شمار کسی بھی ملک کی ترقی، سماجی انصاف اور معاشی استحکام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت
رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے نہ صرف موجودہ مسائل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے بلکہ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی ممکن ہے۔
بالیدگی کو سمجھنے کے لیے شرح پیدائش، شرح اموات، ہجرت اور درازی عمر جیسے عوامل کا مطالعہ لازمی ہے۔
سوال نمبر 14:
نقل مکانی کی اقسام بیان کریں نیز اندرونی نقل مکانی پر تفصیلاً بحث کریں؟
تعارف:
نقل مکانی (Migration) سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کی منتقلی ہے، خواہ وہ مستقل ہو یا عارضی۔ یہ عمل انسانی
تاریخ کا قدیم حصہ ہے اور آج بھی دنیا بھر میں سماجی، معاشی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی بنیاد بنتا ہے۔ نقل مکانی کو
مختلف بنیادوں پر اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں اندرونی (Internal) اور بیرونی (International) نقل مکانی سب
سے اہم ہیں۔
نقل مکانی کی اقسام:
- اندرونی نقل مکانی: ایک ہی ملک کے اندر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کو اندرونی نقل مکانی کہا جاتا ہے، جیسے دیہی سے شہری علاقوں کی جانب ہجرت۔
- بیرونی نقل مکانی: جب افراد ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے ہیں تو اسے بیرونی یا بین الاقوامی نقل مکانی کہا جاتا ہے۔
- رضاکارانہ نقل مکانی: بہتر تعلیم، روزگار یا معیارِ زندگی کے حصول کے لیے اپنی مرضی سے کی جانے والی ہجرت۔
- جبری نقل مکانی: جنگ، فسادات، قدرتی آفات یا حکومتی پالیسیوں کے باعث کی جانے والی ہجرت۔
- عارضی نقل مکانی: محدود وقت کے لیے کی جانے والی ہجرت جیسے موسمی مزدوروں کی نقل مکانی۔
- مستقل نقل مکانی: جب لوگ کسی نئی جگہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔
اندرونی نقل مکانی پر تفصیلی بحث:
اندرونی نقل مکانی کسی بھی ملک کی آبادی اور اس کے معاشرتی و معاشی ڈھانچے پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ پاکستان سمیت
دنیا کے بیشتر ترقی پذیر ممالک میں دیہی سے شہری ہجرت سب سے عام رجحان ہے۔
اندرونی نقل مکانی کی وجوہات:
- معاشی وجوہات: دیہی علاقوں میں روزگار کے محدود مواقع لوگوں کو شہروں کا رخ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔
- تعلیمی سہولتیں: شہروں میں بہتر تعلیمی ادارے دستیاب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے والدین بچوں کو لے کر ہجرت کرتے ہیں۔
- صحت کی سہولتیں: شہروں میں ہسپتال، کلینک اور ماہر ڈاکٹروں کی موجودگی لوگوں کو کشش فراہم کرتی ہے۔
- سماجی عوامل: جدید طرز زندگی، بہتر رہائش، اور سماجی ترقی کے امکانات شہروں کی طرف ہجرت کا باعث بنتے ہیں۔
- ماحولیاتی عوامل: سیلاب، خشک سالی اور زمین کی زرخیزی میں کمی بھی لوگوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔
اندرونی نقل مکانی کے اثرات:
- شہروں پر دباؤ: آبادی میں تیز رفتار اضافہ شہروں میں بے ہنگم آبادی، ٹریفک مسائل اور آلودگی کو جنم دیتا ہے۔
- دیہی علاقوں پر اثر: نوجوان اور ہنرمند طبقہ دیہی علاقوں سے نکلنے کی وجہ سے دیہات میں ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔
- معاشی ترقی: شہروں میں لیبر فورس میں اضافہ صنعتوں کو ترقی دیتا ہے۔
- سماجی تبدیلی: لوگوں کے میل جول اور کلچر کے ملاپ سے معاشرتی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔
اہم نکات:
- اندرونی نقل مکانی دیہی اور شہری دونوں علاقوں پر مثبت اور منفی اثرات ڈالتی ہے۔
- بہتر منصوبہ بندی اور شہری انفراسٹرکچر کی ترقی کے ذریعے ان مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے۔
- دیہی علاقوں میں سہولیات فراہم کر کے ہجرت کے دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔
نتیجہ:
نقل مکانی ایک فطری اور قدیم عمل ہے لیکن اس کی اقسام اور اثرات معاشرتی و معاشی ڈھانچے پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔
خاص طور پر اندرونی نقل مکانی شہروں کی ترقی اور مسائل دونوں کا باعث بنتی ہے۔ اس کے مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھانے
اور منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے متوازن پالیسیوں کی تشکیل نہایت ضروری ہے۔
سوال نمبر 15:
نقل مکانی کی رفتار اگر تیز ہو جائے تو آبادی اور ماحول پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔
تعارف:
نقل مکانی ایک ایسا سماجی و معاشی عمل ہے جو ہر دور میں انسانوں کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ لیکن جب یہ عمل معمول سے
زیادہ تیز رفتار ہو جائے تو آبادی کے توازن اور ماحول دونوں پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ترقی پذیر
ممالک میں تیز رفتار ہجرت (Migration) معاشرتی ڈھانچے کو متاثر کرتی ہے اور ماحولیاتی مسائل کو بڑھا دیتی ہے۔
آبادی پر اثرات:
- شہروں کی آبادی میں اضافہ: تیز رفتار ہجرت کے باعث شہروں میں بے تحاشا آبادی بڑھتی ہے جس سے گنجان بستیاں، کچی آبادیوں اور جھونپڑیوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔
- بے روزگاری میں اضافہ: زیادہ لوگ کم مواقع کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں جس سے روزگار کے ذرائع ناکافی ہو جاتے ہیں۔
- دیہی علاقوں کی تنزلی: نوجوان اور ہنرمند افراد دیہات سے نکلنے لگتے ہیں جس سے زرعی پیداوار اور دیہی ترقی سست ہو جاتی ہے۔
- سماجی مسائل: آبادی کے دباؤ سے جرائم، غربت، رہائشی مسائل اور صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں۔
- ثقافتی تبدیلیاں: مختلف علاقوں سے آنے والے افراد کے میل جول سے معاشرتی اقدار اور ثقافتی توازن میں تبدیلی آتی ہے۔
ماحول پر اثرات:
- قدرتی وسائل پر دباؤ: تیز رفتار ہجرت شہروں میں پانی، بجلی، گیس اور خوراک کی طلب کو بڑھا دیتی ہے جس سے وسائل کی قلت پیدا ہوتی ہے۔
- رہائشی مسائل: شہروں میں رہائش کی کمی کی وجہ سے کچی آبادیاں پھیلتی ہیں جو صحت اور ماحول دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔
- آلودگی میں اضافہ: زیادہ آبادی ٹریفک جام، فضائی آلودگی، شور اور کچرے کے ڈھیروں کا باعث بنتی ہے۔
- زمین کا بے تحاشا استعمال: ہجرت کے دباؤ کے تحت زرعی زمینیں رہائشی یا تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگتی ہیں جس سے زرعی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔
- ماحولیاتی توازن میں بگاڑ: جنگلات کی کٹائی، صاف پانی کی کمی، اور کوڑے کرکٹ کے پھیلاؤ سے ماحول شدید متاثر ہوتا ہے۔
اہم نکات:
- تیز رفتار نقل مکانی سے شہروں میں ترقی تو ہوتی ہے مگر مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔
- دیہی علاقوں کی ترقی رکنے سے معاشی توازن بگڑتا ہے۔
- ماحولیاتی آلودگی اور وسائل کی کمی براہِ راست انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔
نتیجہ:
اگر نقل مکانی کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہو جائے تو آبادی اور ماحول دونوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شہروں میں
بے ہنگم آبادی کے باعث مسائل بڑھتے ہیں جبکہ دیہی علاقے ترقی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے
حکومت کو دیہی علاقوں میں سہولتوں کی فراہمی، شہری منصوبہ بندی اور ماحول دوست پالیسیاں اپنانا ناگزیر ہے۔ یوں نقل
مکانی کے مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔
سوال نمبر 16:
قدرتی وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ کسی کی چار پر تفصیل سے لکھئے۔ نیز پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کی تاریخ کا جائزہ لیں۔
تعارف:
قدرتی وسائل وہ عطیہ ہیں جو انسان کو براہِ راست قدرت کی طرف سے ملتے ہیں اور جن پر انسانی زندگی، معیشت اور تہذیب
کا دارومدار ہے۔ ان وسائل کو درست اور متوازن طریقے سے استعمال کرنا انسانی ترقی اور پائیداری کے لیے بنیادی حیثیت
رکھتا ہے۔ قدرتی وسائل کو کئی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے مثلاً حیاتیاتی، غیر حیاتیاتی، قابلِ تجدید، ناقابلِ
تجدید، آبی اور معدنی وسائل وغیرہ۔
قدرتی وسائل کی اہم اقسام اور تفصیل:
- ۱۔ آبی وسائل:
پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ پاکستان میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کا نظام سب سے اہم آبی ذریعہ ہے۔ زراعت، صنعت، پینے کے پانی اور توانائی کے لیے آبی وسائل ناگزیر ہیں۔ تاہم تیزی سے بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پانی کی کمیاب ی ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ - ۲۔ جنگلات:
جنگلات نہ صرف لکڑی اور ایندھن مہیا کرتے ہیں بلکہ فضائی آلودگی کو کم کرتے، بارش کے نظام کو متوازن رکھتے اور جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ کل رقبے کے صرف 5 فیصد کے قریب ہے جو عالمی معیار سے بہت کم ہے۔ ان کی حفاظت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ - ۳۔ معدنی وسائل:
معدنیات کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ پاکستان کو تانبہ، سونا، کوئلہ، کرومائیٹ، قدرتی گیس اور نمک جیسے معدنی وسائل قدرت نے وافر مقدار میں عطا کیے ہیں۔ اگر ان وسائل کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے استعمال کیا جائے تو ملک معیشتی طور پر خود کفیل ہو سکتا ہے۔ - ۴۔ زرعی وسائل:
پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار زرعی وسائل پر ہے۔ زرخیز زمین، دریاؤں سے حاصل شدہ آبپاشی کا نظام، گندم، کپاس، چاول اور گنا جیسی فصلیں ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تاہم غیر متوازن استعمال اور آبادی کے دباؤ کی وجہ سے یہ وسائل متاثر ہو رہے ہیں۔
پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کی تاریخ:
پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کا آغاز 1953ء میں نجی سطح پر ہوا جب ایک تنظیم نے کراچی میں محدود پیمانے پر یہ
مہم شروع کی۔ 1960ء کی دہائی میں حکومتِ پاکستان نے اس پروگرام کو سرکاری سطح پر اپنایا اور “فیملی پلاننگ پروگرام”
شروع کیا۔
1970ء کے بعد اسے “آبادی بہبود پروگرام” کا نام دیا گیا اور دیہی و شہری مراکز صحت کے ذریعے آگاہی اور سہولتیں فراہم
کی گئیں۔
1990ء کی دہائی میں بین الاقوامی اداروں کی معاونت سے اس پروگرام کو مزید وسعت دی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد آبادی کی
تیز رفتار بڑھوتری پر قابو پانا، ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانا اور وسائل و ضروریات کے درمیان توازن قائم کرنا
تھا۔
آج بھی پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کو کئی سماجی، مذہبی اور ثقافتی رکاوٹوں کا سامنا ہے، تاہم بتدریج عوامی
شعور اور حکومتی اقدامات کے نتیجے میں اس کی افادیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔
اہم نکات:
- قدرتی وسائل انسان کی بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔
- پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں بلکہ ان کے درست استعمال کی ضرورت ہے۔
- خاندانی منصوبہ بندی آبادی اور وسائل میں توازن قائم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
نتیجہ:
قدرتی وسائل اور خاندانی منصوبہ بندی دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر وسائل کا مؤثر استعمال اور آبادی پر کنٹرول
کیا جائے تو ملک معاشی، سماجی اور ماحولیاتی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بصورتِ دیگر وسائل پر دباؤ بڑھتا جائے
گا اور ترقی کا خواب ادھورا رہے گا۔
سوال نمبر 17:
پاکستان میں افزائش آبادی کی صورتحال کا جائزہ پیش کریں۔
تعارف:
افزائشِ آبادی کا مطلب ہے کسی ملک یا خطے میں لوگوں کی تعداد کا بڑھنا۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی بہت
تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ آبادی کسی بھی ملک کے لیے افرادی قوت اور ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اگر وسائل کے
مطابق کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بوجھ اور مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ پاکستان میں آبادی کی تیز رفتار بڑھوتری ایک بڑا
سماجی، معاشی اور ماحولیاتی چیلنج بن چکی ہے۔
پاکستان میں آبادی کی موجودہ صورتحال:
پاکستان کی آبادی 1951ء میں صرف 3 کروڑ 40 لاکھ تھی جو آج بڑھ کر تقریباً 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ آبادی میں یہ
تیز رفتار اضافہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ موجودہ وقت میں پاکستان دنیا کا پانچواں سب سے
زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ آبادی کی سالانہ شرحِ نمو تقریباً 2 فیصد ہے جو جنوبی ایشیا کے اوسط سے زیادہ ہے۔
افزائش آبادی کی وجوہات:
- اعلی شرح پیدائش اور کم شرح اموات۔
- خاندانی منصوبہ بندی کی سہولتوں کی کمی اور آگاہی کا فقدان۔
- دیہی علاقوں میں بڑی فیملی کو معاشی طاقت سمجھا جانا۔
- شرح خواندگی میں کمی، خاص طور پر خواتین کی تعلیم کی کمی۔
- ثقافتی و مذہبی رکاوٹیں اور خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں غلط فہمیاں۔
آبادی کے اضافے کے اثرات:
- وسائل پر دباؤ: پانی، زمین، توانائی اور دیگر وسائل کم پڑنے لگتے ہیں۔
- معاشی مسائل: روزگار کے مواقع محدود ہوتے ہیں اور غربت بڑھتی ہے۔
- صحت کے مسائل: ہسپتالوں اور طبی سہولیات پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔
- تعلیمی مسائل: بڑھتی آبادی کے لیے تعلیمی ادارے ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔
- ماحولیاتی آلودگی: زیادہ آبادی شہروں میں کچرے، آلودگی اور بے ہنگم آبادکاری کا باعث بنتی ہے۔
افزائش آبادی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات:
- خاندانی منصوبہ بندی کی سہولتوں کو عام اور آسان بنانا۔
- تعلیم کو فروغ دینا، خاص طور پر خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا۔
- عوامی آگاہی مہمات کے ذریعے چھوٹے خاندان کے فوائد اجاگر کرنا۔
- صحت و تولیدی سہولیات کو دیہی علاقوں تک پہنچانا۔
- حکومتی پالیسیوں میں آبادی اور وسائل کے درمیان توازن پیدا کرنا۔
اہم نکات:
- پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جو ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
- وسائل اور سہولتیں آبادی کے حساب سے ناکافی ہیں۔
- اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو غربت اور بے روزگاری مزید بڑھیں گی۔
نتیجہ:
پاکستان میں افزائشِ آبادی ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ آبادی کنٹرول کے بغیر نہ صرف وسائل کم
پڑ جائیں گے بلکہ سماجی و معاشی مسائل بھی شدت اختیار کر جائیں گے۔ اگر تعلیم، آگاہی اور خاندانی منصوبہ بندی کو
فروغ دیا جائے تو آبادی اور وسائل کے درمیان توازن قائم کیا جا سکتا ہے، جو ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے
ناگزیر ہے۔
سوال نمبر 18:
اموات کے مطالعہ میں تعلیم اور ازدواجی حیثیت کی اہمیت بیان کریں۔
تعارف:
آبادیاتی مطالعات میں اموات کی شرح (Mortality Rate) ایک بنیادی عنصر ہے۔ کسی ملک یا معاشرے میں اموات کی شرح کو
سمجھنے کے لیے کئی سماجی، معاشی اور ثقافتی عوامل کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان عوامل میں “تعلیم” اور “ازدواجی
حیثیت” (Marital Status) بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں عوامل براہِ راست صحت، معیارِ زندگی اور زندگی کے دورانیے پر
اثر انداز ہوتے ہیں۔
تعلیم اور اموات:
تعلیم کسی بھی شخص کی زندگی کے معیار اور صحت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد بہتر صحت کے اصولوں سے آگاہ
ہوتا ہے اور بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات اختیار کرتا ہے۔ اس حوالے سے درج ذیل نکات اہم ہیں:
- صحت کی آگاہی: تعلیم یافتہ افراد بیماریوں سے بچاؤ، صفائی اور خوراک کی اہمیت کو بہتر سمجھتے ہیں۔
- بہتر سہولیات تک رسائی: تعلیم یافتہ افراد صحت عامہ کی سہولتوں تک بہتر رسائی حاصل کرتے ہیں۔
- کم شرح اموات: شرح اموات تعلیم یافتہ طبقے میں نسبتاً کم دیکھی جاتی ہے کیونکہ وہ صحت مند طرزِ زندگی اپناتے ہیں۔
- بچوں کی اموات پر اثر: ماں کی تعلیم بچوں کی شرحِ اموات کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے۔
ازدواجی حیثیت اور اموات:
ازدواجی حیثیت بھی اموات کی شرح پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کی صحت اور اوسط عمر میں
نمایاں فرق دیکھا جاتا ہے۔
- شادی شدہ افراد: عام طور پر شادی شدہ افراد کی صحت بہتر اور عمر طویل ہوتی ہے کیونکہ وہ سماجی و جذباتی سہارا حاصل کرتے ہیں۔
- غیر شادی شدہ افراد: غیر شادی شدہ یا اکیلے رہنے والے افراد میں ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور قبل از وقت موت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔
- بیوہ یا طلاق یافتہ: بیوہ یا طلاق یافتہ افراد کی شرحِ اموات زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تنہائی اور مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔
- ازدواجی تعلقات کا مثبت کردار: شادی شدہ افراد ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھتے ہیں جس سے ان کی بیماریوں سے بچنے اور علاج تک رسائی کی شرح بڑھ جاتی ہے۔
اہم نکات:
- تعلیم اموات کی شرح کم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔
- شادی شدہ افراد عام طور پر زیادہ صحت مند اور طویل زندگی گزارتے ہیں۔
- بیوہ، مطلقہ اور غیر شادی شدہ افراد میں اموات کی شرح زیادہ دیکھی گئی ہے۔
- تعلیم اور ازدواجی حیثیت دونوں سماجی استحکام اور صحت کے اہم عناصر ہیں۔
نتیجہ:
اموات کے مطالعے میں تعلیم اور ازدواجی حیثیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم صحت مند طرزِ زندگی اپنانے، بیماریوں
سے بچنے اور علاج تک رسائی کو آسان بناتی ہے، جبکہ ازدواجی حیثیت جذباتی و سماجی تعاون فراہم کر کے صحت اور لمبی عمر
میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تعلیم کو عام کیا جائے اور مستحکم خاندانی نظام کو فروغ دیا جائے تو معاشرے میں
اموات کی شرح کو کم کیا جا سکتا ہے۔
سوال نمبر 19:
پاکستان میں پائی جانے والی اہم بیماریوں اور ان کی وجوہات کا مختصر جائزہ لیں۔
تعارف:
پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں صحت کے مسائل ہمیشہ سے سنگین رہے ہیں۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ، ماحولیاتی آلودگی،
غربت، کم تعلیمی شعور اور ناقص صحت عامہ کی سہولیات نے بیماریوں کی شرح کو بڑھا دیا ہے۔ یہاں مختلف متعدی
(Infectious) اور غیر متعدی (Non-communicable) امراض وسیع پیمانے پر موجود ہیں جن کی وجوہات معاشرتی اور ماحولیاتی
عوامل سے جڑی ہیں۔
پاکستان میں پائی جانے والی اہم بیماریاں:
- ہیپاٹائٹس (Hepatitis B & C): یہ جگر کی مہلک بیماری ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے۔
- تپ دق (Tuberculosis – TB): ایک متعدی بیماری جو زیادہ تر پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے۔
- ملیریا (Malaria): مچھر کے ذریعے پھیلنے والی بیماری جو دیہی علاقوں میں عام ہے۔
- شوگر (Diabetes): ایک غیر متعدی مرض جو شہری آبادی میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
- بلڈ پریشر اور دل کے امراض: تیزی سے بدلتی طرزِ زندگی اور غیر متوازن خوراک کی وجہ سے عام ہیں۔
- اسہال اور پانی سے پھیلنے والی بیماریاں: آلودہ پانی اور ناقص صفائی کی وجہ سے بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔
- ڈینگی بخار: حالیہ برسوں میں مچھر سے پھیلنے والا یہ مرض بڑے شہروں میں عام ہو گیا ہے۔
ان بیماریوں کی وجوہات:
- آلودہ پانی اور ناقص صفائی: ہیضہ، اسہال اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔
- ماحولیاتی آلودگی: سانس کی بیماریوں، دمہ اور دل کے امراض کو بڑھا رہی ہے۔
- ناقص صحت عامہ کا نظام: بنیادی صحت مراکز کی کمی اور علاج کی سہولتوں کا فقدان۔
- غربت اور غذائی قلت: کمزور قوتِ مدافعت کے باعث بچے اور خواتین زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
- تعلیم اور آگاہی کی کمی: حفاظتی ٹیکوں سے انکار، غلط علاج اور بیماریوں کے بارے میں لاعلمی۔
- آبادی میں تیزی سے اضافہ: محدود وسائل پر دباؤ اور بیماریوں کے پھیلاؤ میں اضافہ۔
اہم نکات:
- پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بیماریاں متعدی اور غیر متعدی دونوں اقسام کی ہیں۔
- ہیپاٹائٹس اور تپ دق جیسے امراض سنگین نوعیت کے ہیں اور شرحِ اموات بڑھا رہے ہیں۔
- غربت، آلودگی، ناقص نظامِ صحت اور تعلیمی کمی بنیادی وجوہات ہیں۔
- ان بیماریوں پر قابو پانے کے لیے بہتر صحت سہولتیں، عوامی آگاہی اور صاف ماحول ضروری ہیں۔
نتیجہ:
پاکستان میں بیماریوں کے پھیلاؤ کی اصل وجوہات غربت، ماحولیاتی آلودگی، ناقص صحت عامہ کا نظام اور تعلیم کی کمی ہیں۔
اگر عوامی سطح پر صحت کی آگاہی، صاف پانی کی فراہمی، ویکسینیشن اور مؤثر صحت پالیسیوں کو فروغ دیا جائے تو ان
بیماریوں کی شرح کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔
سوال نمبر 20:
مندرجہ ذیل پر نوٹ تحریر کریں: پاکستانی آبادی کے مخر و لی مینارے، پاکستان میں مختلف ادوار کے دوران شرح پیدائش، پاکستان میں صحت کی سہولیات، شرح پیدائش کے معاشرتی و ثقافتی عوامل، بچوں میں پیدائش پر وزن اور ویکسینیشن، شہر بندی کے تاریخی پس منظر۔
تعارف:
پاکستان دنیا کا چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جس کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آبادیاتی تبدیلیوں، صحت کے
شعبے، شرح پیدائش اور شہری کاری کے رجحانات کا مطالعہ ملکی ترقی اور پالیسی سازی کے لیے نہایت اہم ہے۔ پاکستان کی
آبادی کی ساخت، صحت، شرح پیدائش اور شہربندی کے پہلوؤں کا مطالعہ نہ صرف آبادیاتی علم (Demography) کے لیے اہم ہے
بلکہ ملکی پالیسی سازی کے لیے بھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مخر و لی مینارے (Population Pyramids)، صحت کی سہولیات،
پیدائش کے عوامل، بچوں کی صحت اور شہر بندی پاکستان کے سماجی و معاشی ڈھانچے پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔
پاکستانی آبادی کے مخر و لی مینارے:
آبادیاتی مخر و لی مینارے کسی بھی ملک کی آبادی کی عمر اور جنس کے لحاظ سے ساخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کا
آبادیاتی ڈھانچہ عموماً نوجوان آبادی پر مشتمل ہے، جہاں بڑی تعداد 15 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے۔
پاکستان کی تقریباً 64% آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، جو کہ ایک “توسیعی” آبادیاتی ہرم کی نشاندہی کرتی
ہے۔ 0-4 سال کی عمر کے گروپ میں آبادی کا ایک بڑا حصہ موجود ہے جبکہ 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی تعداد نسبتاً
کم ہے۔ یہ “یوتھ بلج” مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور چیلنجز بھی، کیونکہ روزگار، تعلیم اور صحت کی سہولیات پر دباؤ بڑھ
جاتا ہے۔ موجودہ آبادیاتی ڈھانچہ بتاتا ہے کہ آنے والے برسوں میں آبادی میں اضافہ جاری رہے گا، جس کے لیے منصوبہ
بندی کی ضرورت ہے۔
پاکستان میں مختلف ادوار کے دوران شرح پیدائش:
قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں میں شرح پیدائش بہت بلند (تقریباً 7 بچے فی عورت) تھی۔ 1970 سے 1990 کے دوران شرح
پیدائش میں بتدریج کمی (6.0 سے 5.4 بچے فی عورت) دیکھی گئی۔ 1990 سے 2010 تک شرح پیدائش میں سست رفتاری سے کمی جاری
رہی (5.4 سے 4.1 بچے فی عورت)۔ موجودہ دور میں یہ شرح کم ہو کر تقریباً 3.6 بچے فی عورت رہ گئی ہے، مگر اب بھی یہ
جنوبی ایشیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ صوبائی سطح پر نمایاں فرق پایا جاتا ہے، جہاں بلوچستان میں شرح
پیدائش سب سے زیادہ جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے کم ہے۔ شہری علاقوں میں شرح پیدائش دیہی علاقوں کے مقابلے میں
نمایاں طور پر کم ہے، جس کی بڑی وجہ شہری علاقوں میں تعلیم اور خاندانی منصوبہ بندی کی بہتر سہولیات ہیں۔
پاکستان میں صحت کی سہولیات:
پاکستان کا صحت کا نظام محدود وسائل کا شکار ہے۔ ملک میں تقریباً 1200 سرکاری اسپتال، 5500 بنیادی مراکز صحت (BHUs)
اور دیہی مراکز صحت (RHUs) موجود ہیں مگر ان میں جدید سہولیات اور عملے کی کمی ہے۔ صحت کے بجٹ کا جی ڈی پی کا محض
2.8% حصہ ہے، جو عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ 5% سے کم ہے۔ شہری علاقوں میں بڑے اسپتال موجود ہیں لیکن وہاں بھی
آبادی کے دباؤ کی وجہ سے سہولیات ناکافی ہیں۔ دیہی علاقوں میں زچہ و بچہ کی دیکھ بھال، ماہر ڈاکٹروں کی کمی اور
ویکسینیشن کی عدم دستیابی اہم مسائل ہیں۔ ادویات کی اعلیٰ قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ متعدی بیماریوں (ٹی
بی، ملیریا، ہیپاٹائٹس) اور غیر متعدی بیماریوں (ذیابیطس، دل کی بیماریاں) دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ غذائی
قلت خاص طور پر خواتین اور بچوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔
شرح پیدائش کے معاشرتی و ثقافتی عوامل:
شرح پیدائش کو بڑھانے والے عوامل میں کم تعلیمی شرح، خاص طور پر خواتین کی تعلیم کی کمی (صرف 48% خواتین خواندہ)،
بچوں کو “معاشی سہارا” سمجھنے کا رجحان، شادی کی کم عمری (پاکستان میں 21% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے پہلے)، اور
خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں کم آگاہی شامل ہیں۔ دیہی علاقوں میں زیادہ بچے رکھنے کو سماجی حیثیت کی علامت سمجھا
جاتا ہے، جو بلند شرح پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ مذہبی رہنماؤں کا خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں مختلف نقطہ نظر،
“قدر کی مرضی” کا تصور، بیٹے کی خواہش اور اس کے لیے بار بار حمل، اور مردانہ غلبے والے معاشرے میں خواتین کی کم
فیصلہ سازی کی طاقت بھی اہم عوامل ہیں۔ بڑے خاندان کو مثبت نظر سے دیکھا جانا اور خاندانی منصوبہ بندی کے آلات کے
استعمال میں ہچکچاہٹ بھی شرح پیدائش بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
بچوں میں پیدائش پر وزن اور ویکسینیشن:
پاکستان میں بچوں کی پیدائش کے وقت اوسط وزن کئی بار عالمی معیار سے کم ہوتا ہے۔ تقریباً 32% بچے کم وزن کے ساتھ
پیدا ہوتے ہیں، جو عالمی اوسط (15%) سے کہیں زیادہ ہے، اور دیہی علاقوں میں صورتحال زیادہ سنگین ہے۔ اس کی وجہ ماں
کی غذائی قلت (51% خواتین خون کی کمی کا شکار) اور دورانِ حمل ناقص طبی سہولیات ہیں۔ کم عمری میں حمل اور زیادہ بچوں
کی پیدائش بھی اس مسئلے کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو حفاظتی ٹیکوں (EPI) کی مکمل فراہمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔
صرف 66% بچوں کو تمام بنیادی ویکسینز مل پاتی ہیں۔ اگرچہ حکومت نے ویکسینیشن پروگرام شروع کیے ہیں، لیکن شرحِ کوریج
مکمل نہیں ہے، خصوصاً دور دراز دیہی علاقوں میں۔ ویکسینیشن کے بارے میں غلط تصورات اور معلومات کی کمی، سکیورٹی
مسائل (خاص طور پر قبائلی علاقوں میں)، اور صحت کے کارکنوں کی کمی ویکسینیشن میں رکاوٹیں ہیں۔ حکومت Expanded
Program on Immunization (EPI) چلا رہی ہے اور بین الاقوامی اداروں (UNICEF, WHO) کے ساتھ شراکت داری کر رہی ہے،
لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔
شہر بندی کے تاریخی پس منظر:
پاکستان میں شہربندی (Urbanization) تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت صرف چند بڑے شہر موجود تھے مگر آج
کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور اور راولپنڈی جیسے میگا سٹیز آبادی سے بھر گئے ہیں۔ تاریخی طور پر، 1947-1960 کے
دوران مہاجرین کی کثیر تعداد کے شہروں میں آباد ہونے سے شہری آبادی میں اچانک اضافہ ہوا۔ 1960-1980 میں صنعتی ترقی
اور سبز انقلاب کے نتیجے میں دیہی سے شہری علاقوں کی طرف ہجرت ہوئی۔ 1980-2000 میں افغان مہاجرین کے پاکستان میں
داخلے سے شہری آبادی پر دباؤ بڑھا۔ 2000 سے اب تک میگا سٹیز کی تشکیل ہوئی ہے۔ دیہی علاقوں سے روزگار، تعلیم اور
بہتر سہولتوں کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت نے شہر بندی کو تیز کر دیا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو 1951ء میں
پاکستان کی صرف 17 فیصد آبادی شہروں میں رہتی تھی جبکہ آج یہ شرح بڑھ کر 38 فیصد سے زائد ہو گئی ہے۔ اس تیزی نے کچی
آبادیوں، ٹریفک مسائل، آلودگی اور سہولتوں کی کمی جیسے مسائل کو جنم دیا ہے۔ شہر بندی کے مثبت اثرات میں معاشی ترقی،
روزگار کے مواقع، تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات شامل ہیں، جبکہ منفی اثرات میں آلودگی، ٹریفک مسائل، کچی آبادیوں کا
پھیلاؤ، اور جرائم میں اضافہ شامل ہیں۔
اہم نکات:
- پاکستان کی آبادی نوجوان اکثریت پر مشتمل ہے (64% آبادی 30 سال سے کم عمر) جو مواقع اور چیلنج دونوں فراہم کرتی ہے۔
- شرح پیدائش میں کمی آئی ہے (7 سے 3.6 بچے فی عورت) مگر اب بھی عالمی معیار کے لحاظ سے بلند ہے۔
- صحت کی سہولیات ناکافی (جی ڈی پی کا محض 2.8%) اور غیر مساوی طور پر تقسیم ہیں۔
- معاشرتی و ثقافتی عوامل (خواتین کی کم تعلیم، بچوں کو معاشی سہارا سمجھنا، شادی کی کم عمری) بلند شرح پیدائش کا باعث بنتے ہیں۔
- بچوں کی صحت میں غذائی قلت (32% بچے کم وزن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں) اور ویکسینیشن کی کمی (صرف 66% کوریج) بنیادی چیلنج ہے۔
- شہر بندی نے معیشت پر مثبت (روزگار، ترقی) اور سماج پر منفی (آلودگی، کچی آبادیاں) دونوں اثرات ڈالے ہیں۔
- صوبائی سطح پر نمایاں فرق پایا جاتا ہے، خاص طور پر شرح پیدائش اور صحت کی سہولیات تک رسائی میں۔
نتیجہ:
پاکستان میں آبادی کے مسائل، شرح پیدائش، صحت کی سہولیات اور شہر بندی کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کو مضبوط
پالیسیوں، صحت عامہ کی بہتری، خواتین کی تعلیم، خاندانی منصوبہ بندی کے فروغ اور پائیدار شہری منصوبہ بندی کی اشد
ضرورت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے پروگراموں کو مضبوط بنانے، صحت کے بجٹ میں اضافہ کرنے، خواتین کی تعلیم پر توجہ
دینے، شہری منصوبہ بندی بہتر بنانے، اور معاشی ترقی کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر ان پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا
تو آبادی کا دباؤ مزید بڑھ کر معاشی و سماجی مسائل کو سنگین بنا دے گا۔ حکومت، سول سوسائٹی اور بین الاقوامی اداروں
کے باہمی تعاون سے ہی ان چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے اور آبادیاتی ڈویڈنڈ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔

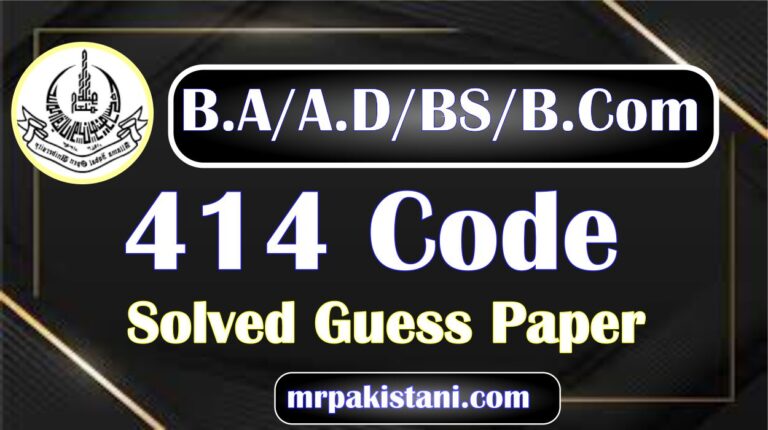




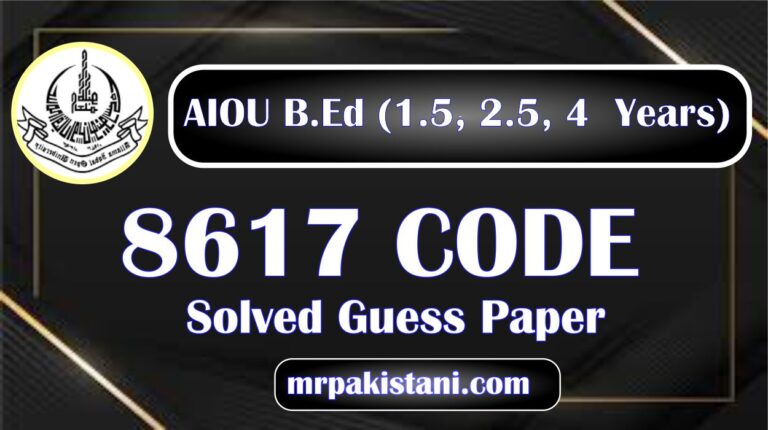


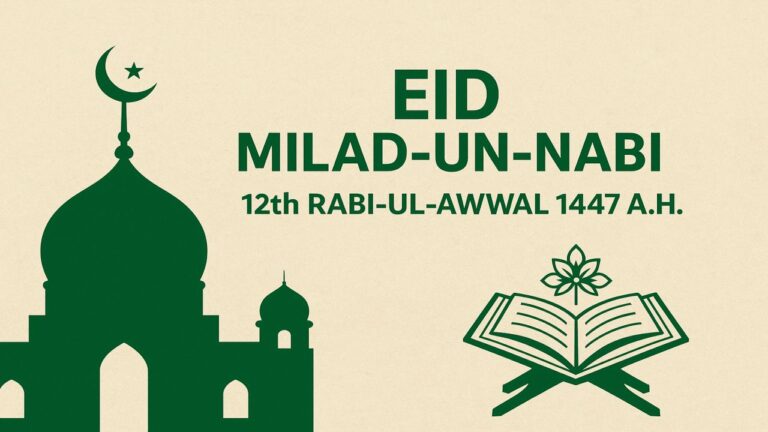
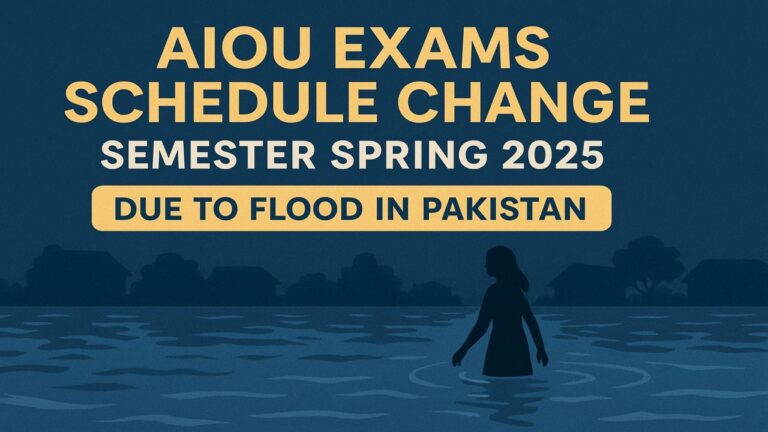






2 Comments
السلام علیکم۔ سر برائے مہربانی گس پیپرز کو پی ڈی ایف کی فائل بنا کر ڈاؤنلوڈ کا أپشن ہو تاکہ أسانی ہو
dear student pdf file mai question add krna problem hoti ha jis wja sy pdf file ni ha