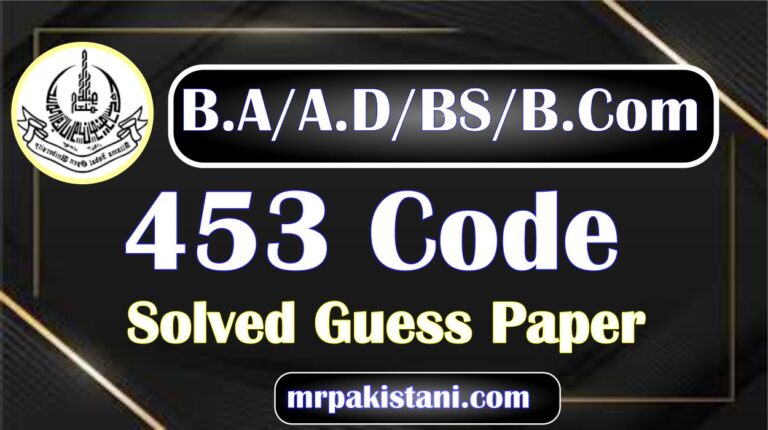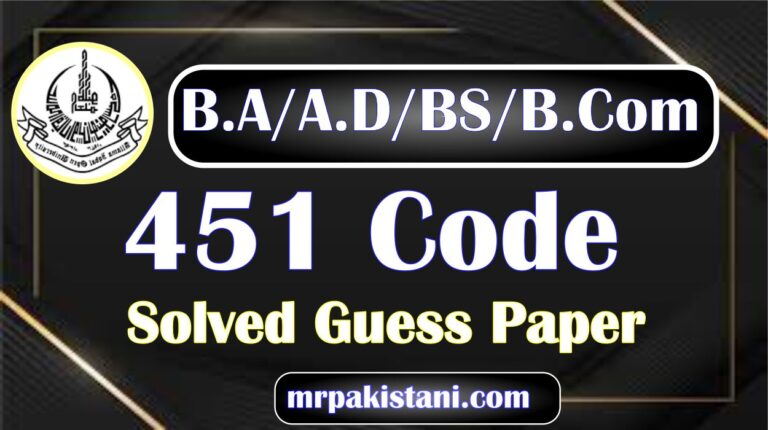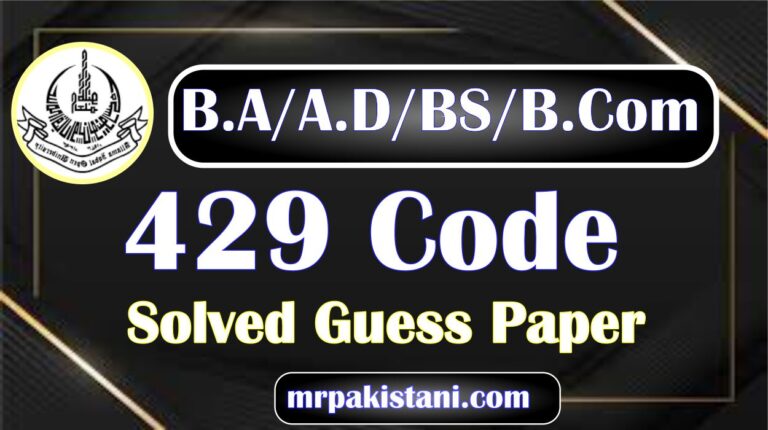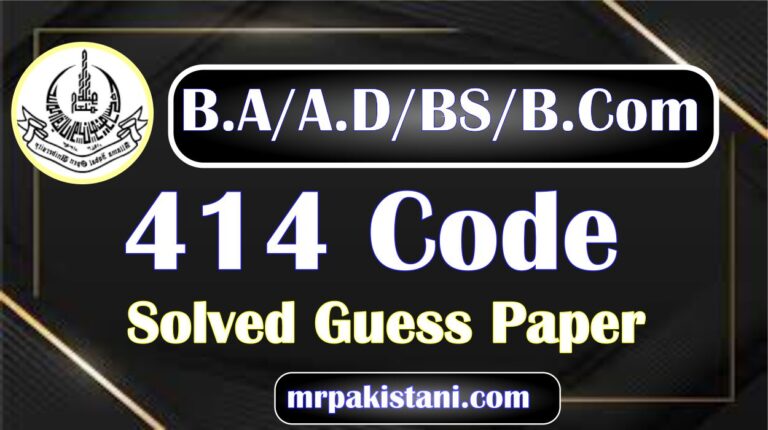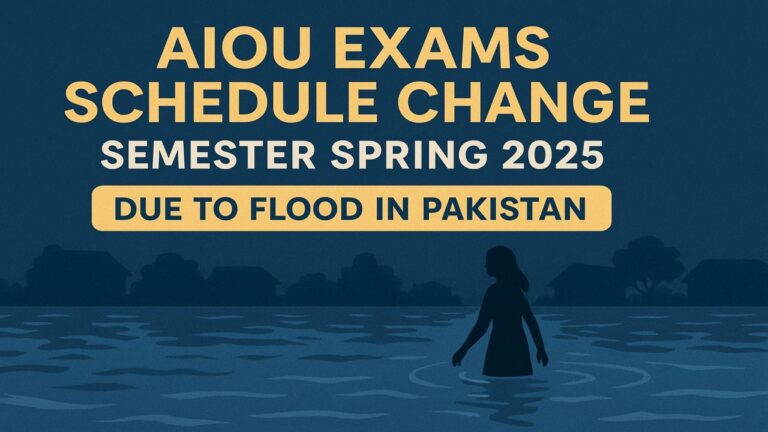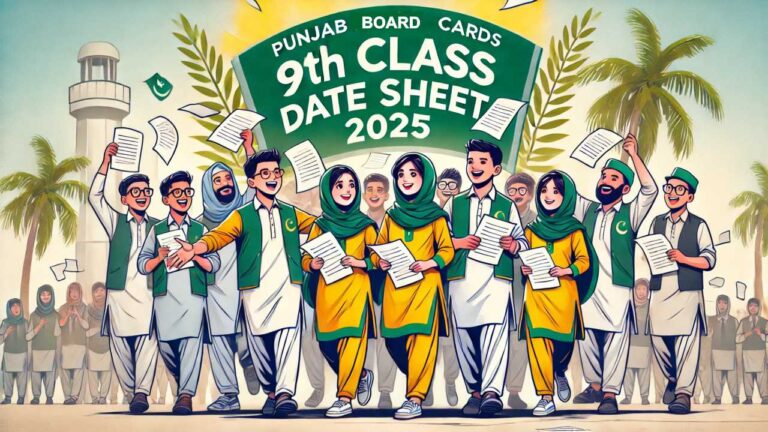For students of AIOU Course Code 416 (Islamiat), we have prepared a complete solved guess paper to make your exam preparation easier and more focused. This guess paper covers the most important questions and topics that are frequently asked in exams, along with solved answers for better understanding. It serves as a quick revision guide and ensures that you don’t miss out on the key concepts of Islamiat. You can download the AIOU 416 Solved Guess Paper from our website mrpakistani.com and also explore video explanations on our YouTube channel Asif Brain Academy.
AIOU 416 Code (Islamiat) Solved Guess Paper
سوال نمبر 1:
توحید کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کی تعریف کریں نیز توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے بیان کیجئے۔
تعارف:
توحید اسلام کی اساس اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دینِ اسلام کا سارا نظام عقیدۂ توحید پر قائم ہے۔ اگر توحید نہ ہو تو نہ
عبادت کا کوئی مفہوم باقی رہتا ہے اور نہ ہی شریعت کا۔ قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت
کو بیان فرمایا اور یہ واضح کر دیا کہ حقیقی معبود صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی
دعوت کا آغاز اسی پیغام سے کیا: “لا الٰہ الا اللہ”۔ لہٰذا توحید ایمان کی جڑ ہے اور اس کے بغیر کوئی عمل مقبول
نہیں۔
توحید کا لغوی مفہوم:
لفظ “توحید” عربی زبان کے مادہ “وحد” سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں: ایک ماننا، یکتا تسلیم کرنا اور کسی کو منفرد قرار
دینا۔ اس اعتبار سے توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور بے مثال ماننا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
کرنا۔
توحید کا اصطلاحی مفہوم:
شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادات میں یکتا مانا جائے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی نظیر نہیں، کائنات کی تخلیق و تدبیر میں کوئی
دوسرا اس کا شریک نہیں، اور عبادت کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد
رہا۔ قرآن میں فرمایا گیا: “وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا
إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ” (الانبیاء: 25) یعنی “ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، اسے یہی وحی
کی
کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔”
توحید کی اقسام:
- توحید ربوبیت: یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔
- توحید الوہیت: یہ عقیدہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ دعا، نماز، روزہ، حج، قربانی اور کسی بھی قسم کی بندگی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔
- توحید اسماء و صفات: یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات یکتا اور کامل ہیں۔ وہ صفات میں کسی مخلوق سے مشابہ نہیں اور نہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے۔
توحید کی اہمیت:
توحید کی اہمیت قرآن و سنت میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ اس کی چند نمایاں جہات درج ذیل ہیں:
- یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمۂ طیبہ “لا الٰہ الا اللہ” توحید ہی کا اعلان ہے۔
- تمام انبیاء کی دعوت کا پہلا پیغام یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔
- شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔
- توحید انسان کو ذہنی و قلبی سکون عطا کرتی ہے کیونکہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔
- یہی عقیدہ انسان کی زندگی کو ایک مقصد عطا کرتا ہے اور اسے غلامی، خوف اور باطل معبودوں سے آزاد کرتا ہے۔
- آخرت کی کامیابی اسی عقیدۂ توحید پر منحصر ہے۔
توحید کے تقاضے:
محض زبان سے توحید کا اقرار کافی نہیں بلکہ اس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے:
- تمام عبادات صرف اللہ کے لیے انجام دینا اور کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔
- اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو ہمسر نہ ٹھہرانا۔
- زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام کو ماننا اور اس کے مطابق چلنا۔
- غیر اللہ سے مدد طلب کرنے یا ان کے آگے جھکنے سے اجتناب کرنا۔
- شرک کی ہر شکل (مثلاً قبروں پر سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا) سے مکمل اجتناب۔
- اللہ کی محبت، خوف اور امید کو سب سے بڑھ کر رکھنا۔
- اللہ تعالیٰ کے احکام پر یقین اور اطاعت کے ذریعے عملی زندگی میں توحید کو نافذ کرنا۔
اہم نکات:
- توحید لغوی طور پر “ایک ماننا” اور اصطلاحی طور پر “اللہ کو ذات، صفات اور عبادات میں یکتا ماننا” ہے۔
- یہ عقیدہ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی پیغام ہے۔
- توحید کی تین بنیادی اقسام ہیں: ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔
- یہی عقیدہ انسان کو ذہنی سکون، مقصدِ حیات اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔
- توحید کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
نتیجہ:
خلاصہ یہ کہ توحید دینِ اسلام کی روح اور اساس ہے۔ یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر قسم کے باطل
معبودوں
اور شرک سے آزاد کرتی ہے۔ توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت قابلِ قبول نہیں اور نہ ہی نجات ممکن ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر
لازم ہے کہ وہ دل سے، زبان سے اور عمل سے توحید کا اقرار کرے اور اپنی عملی زندگی میں اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہی
دراصل کامیابی کی کنجی اور اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔
سوال نمبر 2:
شرک کے مفہوم ذکر کرتے ہوئے شرک کی مختلف صورتیں بیان کیجئے۔
تعارف:
اسلام کا بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اسی کی بندگی ہے۔ اس کے برعکس شرک وہ
عظیم گناہ ہے جو انسان کے ایمان کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ شرک کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے کو نہیں بخشتا اگر کوئی شخص توبہ کے بغیر اس حال میں مر جائے۔
اسی لیے تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نکتہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات رہا۔
لغوی و اصطلاحی مفہومِ شرک:
لغت میں شرک کے معنی ہیں شریک ٹھہرانا، حصہ دار بنانا اور کسی غیر کو اس حق میں شریک کرنا جو اصل میں صرف ایک کے لیے
مخصوص ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال یا حقوقِ عبادت میں کسی
مخلوق کو حصہ دار ٹھہرایا جائے؛ دل، زبان یا عمل سے اس طرح کا عقیدہ رکھا جائے یا ایسا عمل کیا جائے جو عبادت
کے لائق ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بجا لایا جائے۔
شرک کی قباحت اور اس کی حرمت:
شرک سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ خالقِ حقیقی کے حق میں مخلوق کو شریک بناتا ہے۔ شرک اعمال کو باطل کر دیتا ہے، دل کو
خوف و وہم کا اسیر بنا دیتا ہے، انسان کو مخلوق کا غلام اور اسباب کا قیدی بنا دیتا ہے اور بندگی کے اصل مقصد کو مسخ
کر دیتا ہے۔ آخرت میں کامیابی کی پہلی شرط شرک سے پاک عقیدہ و عمل ہے۔
شرک کی بنیادی اقسام:
- شرک فی الذات: اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا؛ جیسے اللہ کے لیے اولاد یا ہمسر ماننا، متعدد معبودوں کا عقیدہ رکھنا یا کسی مخلوق کو اسی درجے کی ازلی و ابدی ہستی سمجھنا۔
- شرک فی الصفات: اللہ کی خاص صفات (علمِ مطلق، قدرتِ کاملہ، سمع و بصرِ محیط، خالقیت، رزاقیت) میں کسی کو شریک ٹھہرانا؛ مثلاً کسی کو ہر جگہ حاضر و ناظر، ہر دل کے حال کو بذاتِ خود جاننے والا یا خودمختار نفع و نقصان پہنچانے والا سمجھنا۔
- شرک فی الربوبیت (افعال): کائنات کی تخلیق، رزق کی تقسیم، زندگی و موت، بارش و پیداوار اور تدبیرِ امور میں کسی کو اللہ کے ساتھ مستقل مؤثر ماننا؛ اسباب کے پسِ پردہ اصل مؤثر کے طور پر اللہ کے بجائے کسی اور کو سمجھنا۔
- شرک فی العبادت (الوہیت): عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی کے لیے مخصوص کرنا؛ جیسے دعا و پکار، نذر و نیاز، ذبح و سجدہ، رکوع، استعانتِ تعبدی، توکلِ کامل، خوفِ تعبدی اور امیدِ تعبدی کو غیرِ اللہ کی طرف پھیر دینا۔
شرک کی نمایاں صورتیں (تفصیلی بیان):
- بتوں، اشخاص یا مظاہرِ قدرت کو معبود ٹھہرانا: پتھروں، درختوں، ستاروں، سورج یا چاند کی تعظیم کو عبادت کی حد تک لے جانا؛ اولیاء یا صالحین کی قبروں کے سامنے جھکنا یا سجدہ کرنا؛ کسی بزرگ یا رہنما کو اس طرح پکارنا گویا وہ بذاتِ خود ہر جگہ سن کر فوراً مدد دینے پر قادر ہو۔
- دعا و ندا میں شرک: حاجت روائی، مشکل کشائی اور مراد برآری کے لیے براہِ راست غیرِ اللہ کو پکارنا؛ دعا عبادت کا مغز ہے، اسے غیر کی طرف پھیرنا شرکِ اکبر ہے۔ جائز صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور کسی زندہ، حاضر انسان سے اسباب کی حد تک مدد طلب کرے جس کا اختیار اللہ نے اسے دیا ہو۔
- نذر و نیاز اور ذبح میں شرک: کسی بزرگ، مزار یا جن کے نام پر نذر ماننا، چراغاں کرنا یا جانور ذبح کرنا؛ نذر و قربانی خالص اللہ کے لیے ہیں، ان میں غیر کی شرکت شرک ہے۔
- طواف و سجدہ میں شرک: طواف صرف بیت اللہ کے لیے مشروع ہے؛ اسی طرح سجدہ عبادت ہے، اسے کسی انسان یا قبر کے لیے کرنا شرکِ جلی ہے۔
- صفاتِ الوہیت میں شرک: کسی کو عالم بالغیبِ مطلق سمجھنا، ہر جگہ بذاتِ خود حاضر و ناظر ماننا، بیماری سے شفا دینے یا رزق عطا کرنے کو اس کے ذاتی اختیار میں سمجھنا؛ حالاں کہ یہ سب اللہ کی خاص صفات ہیں۔
- ربوبیت میں شرکِ اسباب: اسباب کو مستقل مؤثر سمجھ لینا؛ مثلاً ستاروں کی گردش کو بذاتِ خود تنہا خوشی و غمی کا فیصلہ کن سمجھنا، تعویذ یا کسی چیز کو مؤثرِ حقیقی مان لینا؛ درست عقیدہ یہ ہے کہ اسباب اللہ کے حکم کے ماتحت محض ذریعہ ہیں، اثر اللہ کے ارادہ سے پیدا ہوتا ہے۔
- الفاظ و جملات میں شرک: ایسے کلمات جو دل کے باطن کا عقیدہ بگاڑ دیں؛ مثلاً کہنا کہ فلاں نے مجھے روزی دی، یا اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا؛ اس کی درستگی یوں ہو: اللہ نے فلاں کو سبب بنایا، اللہ نے مجھے بچایا اور فلاں ذریعہ بنا۔
- ریا اور شرکِ خفی: دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرنا؛ یہ شرکِ اصغر ہے مگر دل کی تطہیر کے بغیر آہستہ آہستہ بڑے شرک کی طرف لے جا سکتا ہے۔
- غلو فی الاشخاص: انبیاء و اولیاء، مشائخ یا رہنماؤں کے مقام میں حد سے بڑھ جانا؛ ان کا ادب و محبت مطلوب ہے مگر انہیں الوہیت یا صفاتِ خاصہ کے درجہ پر لے جانا ممنوع ہے۔
- فال بینی، نجوم اور توہمات: قسمت کا فیصلہ ستاروں، اعداد، ہاتھ کی لکیروں یا گھڑیوں کی نحوس و سعد کے حوالے سے ثابت سمجھنا؛ یہ سب شرکیہ مزاج اور توکلِ الٰہی کے منافی ہیں۔
شرکِ جلی اور شرکِ خفی کا فرق:
شرکِ جلی وہ ہے جو واضح اور کھلا ہو؛ جیسے بت پرستی، سجدہ غیرِ اللہ کے لیے، نذر و ذبح غیر اللہ کے
نام پر۔ شرکِ خفی وہ ہے جو لطیف ہو اور دلوں میں سرایت کر جائے؛ جیسے ریا، سمعہ، غیرِ اللہ کے ڈر
سے دین میں مداہنت، یا اسباب پر ایسا بھروسا کہ دل اللہ کے ذکر و توکل سے غافل ہو جائے۔
عصرِ حاضر میں شرک کی عام صورتیں (مثالی توضیحات):
- قبر پرستی اور مزاروں کے گرد ایسے اعمال جو عبادت کے دائرہ میں آ جائیں؛ چادریں چڑھانا بطورِ عبادت، نذر مان کر چراغاں کرنا، سجدہ یا طواف کرنا۔
- روحانی پیشواؤں یا جِنّات سے غیبی مدد کی امید اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ بذاتِ خود ہر جگہ سن کر اختیار رکھتے ہیں۔
- تعویذات و گنڈوں کو مؤثرِ حقیقی سمجھنا؛ اگر قرآنی آیات یا مسنون دعاؤں کو بطورِ ذریعہ، ادب و احترام کے ساتھ، صحیح عقیدہ کے ساتھ رکھا جائے تو وہ سبب ہیں، مؤثر اللہ ہے۔
- نجومیوں سے قسمت پوچھنا، رمل، جفر اور ستارہ بینی پر قطعی یقین رکھنا، ایام و مہینوں کو بلا دلیل منحوس سمجھنا۔
- قانونِ حیات، اخلاق و معاشرت میں اللہ کی حاکمیتِ اعلیٰ کو نظرانداز کر کے غیر کے بنائے اصولوں کو حلال و حرام کے درجے میں مطاع بنانا۔
شرک کے اسباب:
- جہالتِ دین اور تعلیمِ توحید سے دوری۔
- تقلیدِ آباء و اسلاف میں غلو اور باطل رسوم کی تقدیس۔
- حبِّ دنیا، خوف و امید کا غلط رخ اور نفسانی خواہشات کی پیروی۔
- باطل افکار کی تبلیغ، کرامات و خوابوں کی غلط تعبیر اور واقعاتی قصوں کو دین کا معیار بنا لینا۔
شرک کے دینی و سماجی اثرات:
شرک سے ایمان مجروح ہوتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، قلوب میں خوف و وہم کا غلبہ پیدا ہوتا ہے، انسان اسباب اور
شخصیات کا محتاج بن جاتا ہے اور معاشرہ اخلاقی و فکری غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس توحید دل کو سکون،
فکر کو آزادی اور عمل کو اخلاص عطا کرتی ہے۔
شرک سے بچاؤ کے عملی تقاضے:
- عقیدۂ توحید کی مضبوط تعلیم، قرآنِ مجید کی تدبر کے ساتھ تلاوت اور سنتِ نبوی کی پیروی۔
- دعاؤں، اذکار اور توکلِ الٰہی کی عادت؛ ہر حاجت میں براہِ راست اللہ کی طرف رجوع۔
- شرکیہ الفاظ سے زبان کی حفاظت؛ قسم صرف اللہ کے نام کی، تعریف و شکر کا محور اللہ کی ذات۔
- زیارتِ قبور کے مسنون آداب: عبرت و دعا کے لیے جانا، نہ کہ تعظیمِ عبادت یا حاجت روائی کے لیے۔
- نذر و نیاز، ذبح اور سجدہ جیسے اعمال کو خالص اللہ کے لیے مخصوص رکھنا۔
- اسباب و مسبّبات کا صحیح تصور: سبب اختیار کرنا سنتِ کائنات ہے، اثر اللہ کے اذن سے پیدا ہوتا ہے۔
- اولیاء و صالحین سے محبت و ادب مگر غلو سے اجتناب؛ احترام کے ساتھ عقیدے کی حدیں قائم رکھنا۔
- بچوں اور نوجوانوں کی فکری تربیت؛ شرکیہ خرافات، جادو ٹونا اور توہمات سے ذہنی تحفظ۔
شرکیہ عبارات و اعمال: چند مثالیں اور درستگی:
- غلط: فلاں بزرگ نے مجھے شفا دی۔ — درست: اللہ نے شفا دی، فلاں سبب بنا۔
- غلط: میری روزی فلاں دیتا ہے۔ — درست: روزی اللہ دیتا ہے، فلاں ذریعہ بنتا ہے۔
- غلط: اگر فلاں نہ ہوتا تو میں بچتا ہی نہ۔ — درست: اگر اللہ نہ بچاتا اور فلاں ذریعہ نہ بنتا تو میں نہ بچتا۔
- غلط: اللہ اور فلاں چاہیں تو ہوگا۔ — درست: اللہ چاہے تو ہوگا؛ یا یوں کہیں: اللہ کے بعد فلاں سبب بنے تو۔
تاریخی پس منظر: شرک کیسے پیدا ہوا؟
انسانیت کی ابتدا توحید پر ہوئی؛ وقت گزرنے کے ساتھ صالحین کی قبروں کا حد سے زیادہ ادب، تصاویر و مجسموں کی تعظیم،
توہمات اور باطل رسموں نے شرک کو جنم دیا۔ آخرکار وہی مجسمے معبود بن گئے، ان کی طرف نذر و نیاز ہونے لگیں اور دعا و
سجدہ انہیں ملنے لگے۔ انبیاءِ کرام بارہا آئے، انہوں نے شرک کی ہر شکل کی تردید کی اور انسان کو ربِ واحد کی بندگی
کی طرف بلایا۔
اہم نکات:
- شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، افعال یا حقوقِ عبادت میں غیر کو شریک کیا جائے۔
- بنیادی اقسام: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الربوبیت اور شرک فی العبادت۔
- نمایاں صورتیں: بت پرستی، دعا و نذر غیر اللہ کے لیے، ذبح و سجدہ غیر اللہ کے نام پر، صفاتِ خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نجوم و توہمات پر قطعی یقین، ریا اور شرکِ خفی۔
- شرک اعمال کو باطل اور دل کو خوف و وہم کا اسیر بناتا ہے؛ توحید آزادی، اخلاص اور مقصدِ حیات عطا کرتی ہے۔
- بچاؤ کا راستہ: علمِ توحید، سنت کی پیروی، شرکیہ الفاظ و اعمال سے اجتناب، اسباب کا درست تصور اور اولیاء کے احترام میں اعتدال۔
نتیجہ:
خلاصہ یہ کہ شرک دین و ایمان کی جڑ پر کاری ضرب ہے۔ اس سے نجات ہی نجاتِ آخرت ہے۔ عقیدہ و عمل میں ہر طرح کے شرک سے
پاک رہنا اور توحید کو دل، زبان اور عمل میں راسخ کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جب بندہ اللہ ہی کو خالق، رازق، مدبر
اور معبودِ برحق مان کر اسی سے مانگتا ہے، اسی پر بھروسا کرتا ہے اور اسی کے لیے جیتا ہے تو وہ حقیقی آزادی، سکونِ
قلب اور کامیابی پاتا ہے۔
سوال نمبر 3:
آخرت کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کی تعریف کریں نیز عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان کیجئے۔
تعارف:
اسلامی عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ “ایمان بالآخرت” ہے۔ قرآن و سنت میں بار بار اس حقیقت پر زور دیا گیا ہے کہ
دنیا ایک عارضی اور امتحانی زندگی ہے جبکہ آخرت ابدی اور دائمی زندگی ہے۔ آخرت پر ایمان دراصل انسان کو یہ شعور دیتا
ہے کہ دنیا میں اس کے تمام اعمال کا حساب ہوگا اور نیک و بد کی جزا و سزا دی جائے گی۔ اس عقیدے کی بدولت انسان اپنی
زندگی کو صحیح رخ پر ڈھالتا ہے اور اخلاقی و سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔
آخرت کا لغوی مفہوم:
لفظ “آخرت” عربی زبان کے لفظ “آخر” سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے “بعد آنے والی چیز” یا “انجام”۔ لغوی اعتبار سے آخرت
کا مطلب ہے “دنیا کے بعد آنے والی زندگی”۔ قرآن میں مختلف مقامات پر آخرت کو “دارالآخرة”، “یوم الحساب” اور “یوم
الجزاء” کے ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد انسان کو یہ باور کرانا ہے کہ دنیا کے بعد ایک اور دائمی زندگی
موجود ہے۔
آخرت کا اصطلاحی مفہوم:
شریعت کی اصطلاح میں آخرت سے مراد وہ دائمی زندگی ہے جو انسان کو مرنے کے بعد حاصل ہوگی۔ یہ زندگی دنیاوی زندگی کے
برعکس ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور قیامت کے دن حشر، حساب و کتاب، میزان، صراط اور جنت
و دوزخ کی منازل سے گزرتا ہے۔ عقیدہ آخرت دراصل اس یقین کا نام ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ لازمی طور پر
ملے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی۔
عقیدہ آخرت کی اہمیت:
عقیدہ آخرت اسلامی تعلیمات کی روح اور ایمان کی تکمیل کے لیے بنیادی ستون ہے۔ اس کی اہمیت درج ذیل پہلوؤں سے واضح
ہوتی ہے:
- زندگی کے مقصد کا تعین: آخرت پر ایمان انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کی زندگی محض کھانے پینے اور دنیاوی لذتوں تک محدود نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور امتحان ہے۔
- اعمال کی جواب دہی: یہ عقیدہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ احساس انسان کو برائیوں سے بچاتا اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔
- اخلاقی تربیت: آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور بدعنوانی سے بچتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔
- صبر اور برداشت: مصیبتوں، آزمائشوں اور مشکلات میں صبر کرنا عقیدہ آخرت کی برکت ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں عظیم اجر ہے۔
- انسانی مساوات: دنیا میں طاقتور و کمزور، امیر و غریب کے درمیان فرق موجود رہتا ہے لیکن عقیدہ آخرت یہ یقین دلاتا ہے کہ اصل انصاف قیامت کے دن ہوگا جہاں کوئی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔
- زندگی میں توازن: آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص دنیاوی خواہشات میں اندھا دھند نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اور دین کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔
- امن و سکون: آخرت پر ایمان انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے کہ اگر دنیا میں انصاف نہ ملے تو آخرت میں ضرور انصاف ہوگا۔
اہم نکات:
- آخرت کا لغوی مفہوم ہے “بعد آنے والی زندگی”۔
- اصطلاحی طور پر آخرت موت کے بعد کی دائمی زندگی ہے جس میں حساب و کتاب ہوگا۔
- عقیدہ آخرت انسان کو نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے دور کرتا ہے۔
- یہ عقیدہ صبر، برداشت، انصاف اور مساوات کو فروغ دیتا ہے۔
- دنیاوی زندگی کو عارضی اور امتحان گاہ سمجھنے کا شعور آخرت پر ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔
نتیجہ:
عقیدہ آخرت دراصل انسان کی پوری زندگی کا رخ متعین کرتا ہے۔ یہ ایمان نہ صرف دنیاوی زندگی کو منظم کرتا ہے بلکہ
انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ اگر انسان اس عقیدے سے غافل ہو جائے تو وہ دنیاوی لذتوں اور وقتی
مفادات میں الجھ کر اپنی ابدی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ آخرت کو اپنی
زندگی کا محور بنائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔
سوال نمبر 4:
اسلام میں عبادات کا مفہوم واضح سمجھیے نیز نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔
تعارف:
اسلام ایک ہمہ گیر دین ہے جو انسان کی انفرادی، اجتماعی، روحانی اور مادی زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرتا ہے۔
اسلام کے بنیادی ارکان میں “عبادات” کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ عبادات دراصل بندے اور خالق کے درمیان تعلق کو مضبوط
کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان کا مقصد انسان کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ اکیلا، آزاد اور بے مقصد نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد
کے تحت اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے:
“وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” (الذاریات:56)
یعنی “میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔”
اسلام میں عبادات کا مفہوم:
عبادت کے لغوی معنی عاجزی، بندگی اور اطاعت کے ہیں۔ عربی زبان میں “عبد” غلام کو کہتے ہیں، اور عبادت کا مطلب ہے
غلام کا اپنے مالک کے سامنے مکمل سر جھکا دینا۔ اصطلاحی طور پر “عبادت” سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا،
اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اور اس کی رضا و خوشنودی کو مقصدِ زندگی بنانا۔ اسلامی نقطہ نظر سے عبادت صرف چند
مخصوص اعمال (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) کا نام نہیں بلکہ ہر وہ قول و فعل جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، عبادت شمار
ہوتا
ہے۔ مثلاً رزقِ حلال کمانا، والدین کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، علم حاصل کرنا اور حتیٰ کہ مسکراہٹ کے ساتھ
دوسرے سے ملنا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا اسلام میں عبادت ایک ہمہ گیر تصور ہے جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔
عبادات کی اقسام:
اسلام میں عبادات کو عام طور پر دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے:
- عباداتِ محضہ (خالص عبادات): جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ وہ اعمال ہیں جو براہِ راست اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔
- عباداتِ غیر محضہ (معاشرتی و اخلاقی عبادات): جیسے والدین کی خدمت، حسنِ سلوک، امانت و دیانت، عدل و انصاف، صلہ رحمی اور غریبوں کی مدد۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بظاہر سماجی و اخلاقی ہیں لیکن نیت اگر اللہ کی رضا ہو تو یہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔
نماز کی اہمیت:
عبادات میں سب سے زیادہ اہم اور مرکزی عبادت نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کو دین کی بنیاد اور ایمان کی علامت قرار
دیا گیا ہے۔ نماز بندے کو براہِ راست اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کرتی ہے اور اس سے تعلق جوڑنے کا سب سے مؤثر ذریعہ
ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔
قرآن مجید میں نماز کی اہمیت:
قرآن کریم نے نماز کو مومن کی پہلی صفت قرار دیا:
“الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ” (المعارج:23)
یعنی “وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔”
ایک اور مقام پر ارشاد ہے:
“إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ” (العنکبوت:45)
یعنی “بیشک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔”
اس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ صرف اللہ کی بندگی کا اظہار ہے بلکہ یہ انسان کی اخلاقی اصلاح اور معاشرتی تطہیر کا بھی
ذریعہ ہے۔
احادیثِ نبوی ﷺ میں نماز کی اہمیت:
احادیث میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:
“الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ
الدِّينَ”
یعنی “نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو
ڈھادیا۔”
اسی طرح فرمایا: “قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست
ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔”
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز باقی عبادات کی قبولیت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔
نماز کے انفرادی و اجتماعی اثرات:
- روحانی اثرات: نماز دل کو سکون، اطمینان اور اللہ تعالیٰ سے قرب عطا کرتی ہے۔
- اخلاقی اثرات: یہ انسان کو برائی، گناہ اور بدکاری سے بچاتی ہے۔
- معاشرتی اثرات: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے مساوات، اخوت اور اتحاد کو فروغ ملتا ہے۔ امیر، غریب، آقا، غلام سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
- جسمانی اثرات: نماز میں رکوع، سجدہ اور دیگر حرکات انسان کی جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہیں۔
اہم نکات:
- عبادت لغوی طور پر عاجزی اور اطاعت، جبکہ اصطلاحی طور پر اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو کہا جاتا ہے۔
- عبادات کی دو اقسام ہیں: محضہ (نماز، روزہ وغیرہ) اور غیر محضہ (اخلاقی و معاشرتی اعمال)۔
- نماز دین کا ستون اور سب سے اہم عبادت ہے جس پر باقی اعمال کی قبولیت کا دارومدار ہے۔
- قرآن کے مطابق نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔
- حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔
- نماز انفرادی طور پر روحانی سکون اور اجتماعی طور پر مساوات و اتحاد پیدا کرتی ہے۔
نتیجہ:
اسلام میں عبادات انسان کی زندگی کا مقصد اور اصل سرمایہ ہیں۔ ان میں سب سے اہم نماز ہے جو نہ صرف اللہ کی بندگی کا
بہترین اظہار ہے بلکہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز دین کی اساس اور مومن کی
پہچان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ قرآن و حدیث کی
روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نماز چھوڑنے والا گویا دین کے بنیادی ستون کو گرا دیتا ہے، جبکہ نماز قائم کرنے
والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور نیکی و فلاح کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔
سوال نمبر 5:
زکوٰۃ کے معنی و مفہوم بتائیں اور زکوٰۃ کی اہمیت اور مقاصد تحریر کریں نیز قرآن وسنت کی روشنی میں زکوٰۃ کے احکام لکھیں۔
تعارف:
اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی اصلاح کرتا ہے۔ عبادات میں زکوٰۃ نہ صرف ایک مالی
عبادت ہے بلکہ ایک ایسا اجتماعی فلاحی نظام بھی ہے جو معاشرتی عدل و انصاف کو یقینی بناتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ
کی اہمیت بار بار بیان ہوئی ہے اور اسے ایمان اور اسلام کا لازمی رکن قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد صرف مالی تقسیم
نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنا، غربت کا خاتمہ اور معیشت کا توازن قائم کرنا ہے۔
زکوٰۃ کے معنی و مفہوم:
لفظ “زکوٰۃ” عربی زبان کے مادہ “زکا” سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں “پاکیزگی، نمو، برکت اور اضافہ”۔ شریعت کی اصطلاح
میں زکوٰۃ اس مخصوص مال کے حصے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزرنے پر فقرا،
مساکین اور دیگر مستحقین کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، دل سے بخل ختم ہوتا ہے اور محتاج افراد کی
ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”
(التوبہ: 103) یعنی “ان کے مالوں سے صدقہ (زکوٰۃ) لے لو جس سے تم انہیں پاک اور پاکیزہ کر دو۔”
زکوٰۃ کی اہمیت:
اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت بہت بنیادی ہے۔ یہ اسلام کے پانچ ارکان میں شامل ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ زور زکوٰۃ پر
دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صرف
ایک مالی فریضہ نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: “اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت،
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔” (بخاری و مسلم)
زکوٰۃ کے مقاصد:
زکوٰۃ کے کئی اہم مقاصد ہیں جو انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں:
- روحانی تطہیر: زکوٰۃ سے دل بخل اور حرص سے پاک ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
- معاشرتی مساوات: زکوٰۃ دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتی ہے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے۔
- غربت کا خاتمہ: محتاجوں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کر کے غربت کو کم کرتی ہے۔
- معاشی استحکام: زکوٰۃ کا نظام اسلامی ریاست کو ایک مضبوط معاشی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
- اخوت و ہمدردی: زکوٰۃ سے مالدار اور غریب کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی بڑھتی ہے۔
قرآن میں زکوٰۃ کے احکام:
قرآن کریم میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت 60 میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے
ہیں:
“إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ”
(التوبہ: 60) یعنی “زکوٰۃ تو صرف فقرا، مساکین، اس پر کام کرنے والوں، دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے والوں، غلاموں
کو آزاد کرانے، قرض داروں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے ہے۔”
احادیث میں زکوٰۃ کے احکام:
احادیث میں بھی زکوٰۃ کی سخت تاکید کی گئی ہے:
- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: “جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا جو اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔” (بخاری)
- حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا: “میں ان سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔” (بخاری) یہ ظاہر کرتا ہے کہ زکوٰۃ چھوڑنا اسلام کے بنیادی حکم کی خلاف ورزی ہے۔
اہم نکات:
- زکوٰۃ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں شامل ہے۔
- زکوٰۃ کے ذریعے مال پاک اور معاشرتی انصاف قائم ہوتا ہے۔
- قرآن نے زکوٰۃ کے آٹھ مصارف مقرر کیے ہیں۔
- زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں سخت وعید آئی ہے۔
- زکوٰۃ فرد کی روحانی تربیت اور معاشرے کی اجتماعی فلاح دونوں کے لیے ناگزیر ہے۔
نتیجہ:
زکوٰۃ اسلامی معاشی نظام کا ستون ہے جو نہ صرف افراد کو بخل اور حرص سے پاک کرتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو عدل و
مساوات، معاشی استحکام اور باہمی ہمدردی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ قرآن و سنت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا
گیا ہے اور اس سے انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ اگر اسلامی معاشروں میں زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم
ہو جائے تو غربت اور معاشی ناہمواری کا خاتمہ ممکن ہے اور ایک خوشحال، منصفانہ اور پرامن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔
سوال نمبر 6:
حج کے معنی، اہمیت اور مقاصد بیان کریں اور خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات بیان کریں۔
تعارف:
حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہر صاحبِ استطاعت مسلمان پر زندگی
میں
ایک بار فرض ہے۔ حج نہ صرف عبادت کا ایک جامع مظہر ہے بلکہ اجتماعی اتحاد، مساوات، قربانی اور اللہ کے حضور بندگی
کا عظیم ترین عملی نمونہ ہے۔ اس عبادت میں عبادتِ بدنی، عبادتِ مالی اور عبادتِ روحانی تینوں پہلو یکجا ہیں۔ حج کا
مقصد محض رسومات ادا کرنا نہیں بلکہ مسلمان کے دل میں اللہ کی اطاعت، تقویٰ، صبر، قربانی اور اخوت کا جذبہ پیدا
کرنا ہے۔
حج کے معنی و مفہوم:
لغوی اعتبار سے “حج” کا مطلب قصد کرنا اور کسی عظیم مقصد کے لیے سفر اختیار کرنا ہے۔ اصطلاحی طور پر حج سے مراد
مخصوص ایام میں مخصوص مقامات (بیت اللہ، عرفات، مزدلفہ، منیٰ) پر مخصوص اعمال بجا لانے کو کہا جاتا ہے۔ حج کا آغاز
احرام سے ہوتا ہے اور طواف، سعی، عرفات میں وقوف، مزدلفہ کی حاضری، رمی جمار، قربانی اور حلق یا قصر جیسے اعمال کے
ذریعے مکمل ہوتا ہے۔
حج کی اہمیت:
حج کو قرآن و سنت میں غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
“وَلِلّٰہِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِ سَبِیْلًا” (آل عمران: 97)
یعنی: “اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔”
حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: “اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے: کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا
اور بیت اللہ کا حج کرنا۔” (بخاری و مسلم)
حج کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک عالمی اجتماع ہے جس میں رنگ، نسل، زبان اور علاقے کے امتیازات
مٹ جاتے ہیں اور سب ایک لباس (احرام) میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔
حج کے مقاصد:
حج کے بے شمار مقاصد ہیں جن میں چند اہم درج ذیل ہیں:
- اللہ کی اطاعت اور بندگی: حج میں مسلمان مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔
- اخوت و مساوات: دنیا بھر کے مسلمان ایک لباس، ایک جگہ اور ایک مقصد کے ساتھ جمع ہو کر مساوات اور بھائی چارے کا عملی ثبوت پیش کرتے ہیں۔
- تقویٰ و روحانی تربیت: حج انسان کے اندر صبر، برداشت، تقویٰ اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔
- قربانی و ایثار: جانور کی قربانی انسان کو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا سبق دیتی ہے۔
- یادگارِ ابراہیمیؑ: حج سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔
- امت کا اتحاد: حج دنیا کے مختلف خطوں سے آئے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے امت کے اتحاد اور وحدت کو مضبوط کرتا ہے۔
خطبہ حجۃ الوداع:
حضور اکرم ﷺ نے 10 ہجری میں اپنے آخری حج کے موقع پر “خطبہ حجۃ الوداع” دیا، جو اسلام کے مکمل اور جامع اصولوں پر
مشتمل تھا۔ اس خطبہ کو انسانی حقوق کا عظیم ترین منشور کہا جاتا ہے۔ خطبہ کے اہم نکات درج ذیل ہیں:
خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات:
- انسانی جان و مال کی حرمت: آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا خون اور مال اتنا ہی محترم ہے جتنا اس دن اور اس شہر کی حرمت ہے۔
- سود کی حرمت: آپ ﷺ نے تمام سودی لین دین کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ میرے خاندان کا سود ہے۔
- عورتوں کے حقوق: آپ ﷺ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور فرمایا کہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں۔
- اخوت اور مساوات: آپ ﷺ نے اعلان کیا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔
- امانت و ذمہ داری: مسلمانوں کو امانت داری اور ذمہ داری کی ادائیگی کا حکم دیا۔
- قرآن و سنت کی پیروی: آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: قرآن اور سنت۔ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔
- امت کا اتحاد: آپ ﷺ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور تفرقہ بازی سے بچنے کی تاکید کی۔
اہم نکات:
- حج اسلام کا پانچواں رکن اور ایک جامع عبادت ہے۔
- یہ تقویٰ، صبر، قربانی، اخوت اور اتحاد کا عملی مظاہرہ ہے۔
- قرآن و سنت نے استطاعت رکھنے والوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔
- حج میں اخوت، مساوات اور عالمگیر اتحاد کے پہلو نمایاں ہیں۔
- خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا عظیم منشور ہے، جس میں مساوات، انصاف، عورتوں کے حقوق، سود کی حرمت اور امت کے اتحاد پر زور دیا گیا۔
نتیجہ:
حج مسلمانوں کے لیے نہ صرف عبادت بلکہ ایک جامع تربیت گاہ ہے جو انہیں اللہ کی بندگی، صبر، قربانی، مساوات،
اخوت اور اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور ﷺ نے وہ اصول بیان کیے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی
رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ حج کے حقیقی پیغام کو اپنائے اور خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات پر عمل کرے تو دنیا
میں عدل، مساوات، امن اور بھائی چارے کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔
سوال نمبر 7:
ختم نبوت کے خصائص و خصوصیات بیان کریں نیز قرآن کی روشنی میں آپ ﷺ کے مسلمانوں پر حقوق بیان کریں۔
تعارف:
ختمِ نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے آخری نبی
اور رسول ہیں۔
آپ ﷺ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی وحی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ قرآن و حدیث دونوں میں اس عقیدے کی واضح اور
قطعی دلائل موجود ہیں۔
ختم نبوت کا تصور نہ صرف اسلام کے دینی ڈھانچے کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ امت مسلمہ کی دینی وحدت اور عقیدے کی بنیاد کو
بھی مضبوط کرتا ہے۔
اسی طرح قرآن کریم میں مسلمانوں پر رسول اللہ ﷺ کے حقوق بھی بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں جن میں آپ ﷺ کی اطاعت،
محبت، عزت اور آپ کی تعلیمات پر عمل بنیادی ہیں۔
ختم نبوت کے خصائص و خصوصیات:
ختم نبوت کی خصوصیات درج ذیل ہیں:
- آخری رسول ہونے کا اعلان: قرآن میں واضح اعلان کیا گیا ہے: وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب:40)۔ یعنی آپ ﷺ اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخری ہیں۔ اس آیت سے یہ عقیدہ قطعی اور دائمی طور پر ثابت ہے۔
- شریعت کی تکمیل: آپ ﷺ پر دین مکمل کر دیا گیا: اليوم أكملت لكم دينكم (المائدہ:3)۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ شریعت کامل و جامع ہے۔
- امت کی وحدت: ختم نبوت کی برکت سے امت ایک ہی رسول اور ایک ہی شریعت کی پیروی پر قائم ہے۔ اگر بعد میں اور انبیاء آتے تو امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جاتی۔
- تحریف سے حفاظت: پچھلی امتوں کی کتابوں میں تحریف ہوئی لیکن قرآن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ختم نبوت اسی تسلسل کی ضمانت ہے کہ اب دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
- عالمگیر رسالت: پچھلے انبیاء مخصوص قوموں کے لیے مبعوث ہوتے تھے، مگر آپ ﷺ کی نبوت قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے عام ہے۔
- ایمان کی شرط: ختم نبوت پر ایمان رکھنا دین اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
قرآن کی روشنی میں نبی کریم ﷺ کے مسلمانوں پر حقوق:
قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کے متعدد حقوق بیان کیے گئے ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہیں:
- ایمان اور اطاعت: قرآن میں فرمایا گیا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (النساء:59)۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مسلمان پر فرض ہے۔
- محبت رسول ﷺ: قرآن میں آیا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (الاحزاب:6)۔ نبی ﷺ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس سے محبت رسول کا حق ظاہر ہوتا ہے۔
- تعظیم و توقیر: قرآن میں حکم ہے: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه (الفتح:9)۔ نبی کی عزت اور توقیر کرنا ایمان کا حصہ ہے۔
- درود و سلام: فرمایا گیا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (الاحزاب:56)۔ نبی ﷺ پر درود و سلام بھیجنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
- فیصلوں کو تسلیم کرنا: قرآن کہتا ہے: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم (النساء:65)۔ یعنی جب تک مسلمان اپنے معاملات میں نبی ﷺ کو حَکَم نہ مانیں ان کا ایمان کامل نہیں۔
- اتباع سنت: قرآن میں ہے: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمران:31)۔ اللہ کی محبت رسول کی سنت کی پیروی میں ہے۔
اہم نکات:
- ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جو قرآن و سنت سے قطعی طور پر ثابت ہے۔
- ختم نبوت امت مسلمہ کی وحدت اور دین کی تکمیل کی ضمانت ہے۔
- حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔
- رسول اللہ ﷺ کی محبت، عزت، اتباع اور درود بھیجنا قرآن کے مطابق مسلمانوں کے بنیادی فرائض ہیں۔
- آپ ﷺ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔
نتیجہ:
ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی اساس اور مسلمانوں کی ایمانی شناخت ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت محمدی ﷺ قیامت
تک کے لیے کافی اور کامل ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت کریں، آپ ﷺ سے محبت رکھیں، آپ کی عزت کریں، آپ پر
درود و سلام بھیجیں اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
درحقیقت ختم نبوت اور حقوق رسالت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی ﷺ کی آخری نبوت پر ایمان اور آپ کے
حقوق کی ادائیگی ہی حقیقی ایمان کی تکمیل ہے۔
سوال نمبر 8:
صبر کا مفہوم، اہمیت اور فضائل و برکات پر مضمون تحریر کریں۔
تعارف:
صبر اسلام کی ایک بنیادی اور عظیم صفت ہے جسے قرآن و حدیث میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ صبر کا تعلق صرف مشکلات
برداشت کرنے سے نہیں بلکہ یہ ایک ہمہ گیر صفت ہے جو انسان کو ایمان پر قائم رکھتی ہے، نیکی پر ثابت قدم کرتی ہے،
گناہوں سے بچاتی ہے اور آزمائشوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ صبر کو ایمان کا نصف قرار دیا گیا ہے
کیونکہ ایمان کا دوسرا حصہ شکر ہے۔ صبر دراصل ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔
صبر کا مفہوم:
صبر کے لغوی معنی ہیں “روکنا، تھامنا اور ضبط کرنا”۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر سے مراد ہے “اللہ کی رضا کے لیے اپنی
خواہشات کو قابو میں رکھنا، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا اور نافرمانی سے بچنا”۔ صبر صرف دکھ درد یا مصیبت برداشت
کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک جامع رویہ ہے جو انسان کو مشکلات میں بے صبری، شکوہ شکایت اور ناشکری سے روکتا ہے۔ صبر
کے تین درجے بیان کیے گئے ہیں: (1) طاعت پر صبر یعنی عبادت میں مستقل مزاجی، (2) معصیت سے صبر یعنی گناہوں سے بچنا،
(3) مصیبت پر صبر یعنی آزمائش میں ثابت قدم رہنا۔
صبر کی اہمیت:
قرآن مجید میں صبر کو کامیابی کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” (آل عمران: 200)۔ یعنی اے
ایمان والو! صبر کرو، صبر کی مشق کرتے رہو، ثابت قدم رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اسلام نے صبر کو ہر حال میں لازمی قرار دیا ہے، خواہ انسان پر خوشی آئے یا غم۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: “مومن کا حال
عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔”
یہ صفت انسان کو زندگی کے نشیب و فراز میں متوازن اور پُر سکون رکھتی ہے، اور مایوسی یا ناشکری جیسے منفی رویوں سے
بچاتی ہے۔
صبر کے فضائل و برکات:
صبر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں:
1. اللہ کی معیت: قرآن میں فرمایا گیا: “إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ” (البقرہ: 153) یعنی بے
شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اپنی خاص مدد اور نصرت کے ذریعے صابرین کے ساتھ
ہوتا ہے۔
2. اجر بے حساب: قرآن میں ہے: “إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ”
(الزمر: 10) یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ فضیلت کسی اور عمل کے ساتھ نہیں جڑی۔
3. گناہوں کا کفارہ: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: “جو مسلمان تھوڑی یا بڑی کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔” (صحیح بخاری)۔
4. جنت کا وعدہ: قرآن میں ہے: “وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا” (الانسان: 12) یعنی
صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس دیا جائے گا۔
5. قیادت و عزت: صبر کے ذریعے انسان کو دنیا میں عزت اور قیادت عطا ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے: “وَجَعَلْنَا
مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا” (السجدہ: 24)۔ یعنی ہم نے ان میں سے ایسے رہنما
بنائے جو صبر کے بدلے ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔
6. روحانی سکون: صبر انسان کو اضطراب، بے چینی اور گھبراہٹ سے محفوظ رکھتا ہے، اور دل و دماغ کو سکون عطا
کرتا ہے۔ یہ دراصل روحانی طاقت ہے جو انسان کو مایوسی اور کفرانِ نعمت سے بچاتی ہے۔
صبر کے عملی مظاہر:
صبر کا عملی مظاہرہ ہر مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات صبر کے بغیر ممکن نہیں۔
گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے فتنہ میں صبر کا مظاہرہ
کیا اور اللہ نے انہیں عزت و مقام عطا فرمایا۔
اسی طرح صحابہ کرامؓ نے مکہ کی سخت آزمائشوں میں صبر کیا تو اللہ نے انہیں دنیا کی قیادت عطا کر دی۔ رسول اکرم ﷺ کی
پوری زندگی صبر کی عملی تصویر تھی، چاہے وہ شعب ابی طالب کی بھوک ہو، طائف کی تکلیف ہو یا میدانِ اُحد کا صدمہ، آپ ﷺ
نے صبر اور استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔
اہم نکات:
- صبر ایمان کا نصف ہے اور ہر مسلمان کی بنیادی صفت ہے۔
- صبر کے تین درجے ہیں: طاعت پر، معصیت سے، اور مصیبت پر صبر۔
- قرآن میں صبر کو کامیابی اور جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔
- صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی خاص معیت اور نصرت شامل رہتی ہے۔
- صبر کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بے حساب اجر ملتا ہے۔
- رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی زندگیاں صبر کی عملی مثال ہیں۔
نتیجہ:
صبر ایک ایسی عظیم دولت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ یہ ایمان کی پختگی، روح کی پاکیزگی اور
اللہ پر بھروسے کی علامت ہے۔ صبر کرنے والے افراد نہ صرف اپنی ذات کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ معاشرے میں سکون، امن اور
محبت کا ماحول قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں صابرین کو بار بار خوشخبری دی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال
میں صبر اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا، دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت حاصل کر سکیں۔
سوال نمبر 9:
مندرجہ ذیل پر نوٹ تحریر کریں: عالم اسلام کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی مسائل۔
تعارف:
عالم اسلام دنیا کی سب سے بڑی تہذیبی اور جغرافیائی اکائیوں میں سے ایک ہے، جو تقریباً پچاس سے زائد آزاد ممالک پر
مشتمل ہے اور دنیا کی آبادی کا تقریباً ایک چوتھائی مسلمان ہے۔ اسلامی ممالک کی سرزمین تیل، گیس، معدنیات اور زرعی
وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس کے باوجود بیشتر اسلامی ممالک سیاسی عدم استحکام، معاشی پسماندگی، غربت، بدعنوانی اور
بیرونی انحصار جیسے مسائل کا شکار ہیں۔ ان مسائل کی جڑیں نوآبادیاتی دور کی میراث، اندرونی تقسیم، عالمی طاقتوں کی
مداخلت اور قیادت کی ناکامی میں پیوستہ ہیں۔
عالم اسلام کے سیاسی مسائل:
عالم اسلام کو سب سے بڑا چیلنج سیاسی عدم استحکام کا ہے۔ بیشتر اسلامی ممالک میں جمہوری ادارے کمزور ہیں، بادشاہت یا
آمریت کا غلبہ ہے اور عوام کو سیاسی عمل میں حقیقی شرکت کے مواقع محدود ملتے ہیں۔ فوجی بغاوتیں، حکومتوں کی بار بار
تبدیلی اور غیر شفاف انتخابات سیاسی نظام کو غیر مستحکم کرتے ہیں۔
مزید برآں، عالم اسلام اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار ہے۔ شام، یمن، لیبیا اور سوڈان جیسے ممالک میں خانہ
جنگی اور بیرونی مداخلت نے سیاسی ڈھانچے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ سات دہائیوں سے حل طلب ہے، جس
کے نتیجے میں امت مسلمہ میں اضطراب اور تقسیم ہے۔
فرقہ واریت اور مسلکی اختلافات بھی سیاسی مسائل کو بڑھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسلامی دنیا متحد ہونے کے بجائے مزید
تقسیم ہو رہی ہے۔ او آئی سی (Organization of Islamic Cooperation) جیسی تنظیمیں امت مسلمہ کی نمائندگی کرتی ہیں مگر
ان کے فیصلے زیادہ تر علامتی رہ جاتے ہیں اور عملی اثرات پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔
عالم اسلام کے معاشی مسائل:
اسلامی ممالک فطری وسائل کی دولت سے بھرپور ہونے کے باوجود معاشی طور پر کمزور ہیں۔ تیل اور گیس کے چند ممالک (سعودی
عرب، قطر، یو اے ای، کویت) معاشی خوشحالی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مگر بیشتر اسلامی ممالک شدید غربت کا شکار ہیں۔
افریقہ اور جنوبی ایشیا کے اسلامی ممالک میں فی کس آمدنی عالمی اوسط سے کہیں کم ہے۔
اسلامی ممالک کی معیشتیں زیادہ تر خام مال (Raw Material) کی برآمد پر انحصار کرتی ہیں اور صنعتی و ٹیکنالوجی کی
ترقی میں پیچھے ہیں۔ نتیجتاً وہ عالمی منڈی میں کمزور پوزیشن رکھتے ہیں۔ درآمدات پر زیادہ انحصار اور برآمدات میں
کمی تجارتی خسارہ بڑھاتی ہے۔
بے روزگاری، مہنگائی، غربت اور کرپشن بھی اسلامی دنیا کے بڑے معاشی مسائل ہیں۔ کئی اسلامی ممالک اپنے بجٹ کا بڑا حصہ
قرضوں اور سود کی ادائیگی پر خرچ کرتے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے (IMF, World Bank) ان پر اقتصادی دباؤ ڈال کر اپنی
شرائط منواتے ہیں، جو مقامی معیشتوں کو مزید کمزور کر دیتی ہیں۔
عالم اسلام کے اقتصادی مسائل:
اسلامی دنیا میں بنیادی ڈھانچے (Infrastructure) کی کمی، جدید صنعت و حرفت میں پسماندگی اور تعلیمی معیار کی کمزوری
اقتصادی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ اکثر ممالک زرعی معیشت پر انحصار کرتے ہیں لیکن جدید ٹیکنالوجی کی کمی، پانی
کی قلت اور زرعی اصلاحات کے فقدان کی وجہ سے پیداوار کم ہے۔
اسلامی مالیاتی نظام (Interest-Free Economy) کو عملی طور پر نافذ کرنے میں مشکلات ہیں۔ اگرچہ اسلامی بینکاری اور
مالیاتی ادارے قائم ہو چکے ہیں، لیکن مجموعی معیشت اب بھی سودی نظام اور مغربی معاشی ڈھانچوں پر انحصار کرتی ہے۔
اقتصادی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ غیر مساوی تقسیم ہے۔ خلیجی ممالک میں دولت کی بھرمار ہے مگر دیگر اسلامی ممالک
غربت، افلاس اور بنیادی سہولتوں کی کمی سے دوچار ہیں۔ یہ عدم مساوات امت مسلمہ میں اتحاد و یگانگت کو بھی متاثر کرتی
ہے۔
اہم نکات:
- اسلامی ممالک میں سیاسی عدم استحکام، آمریت اور جمہوری اداروں کی کمزوری نمایاں مسئلہ ہے۔
- خانگی جنگیں، بیرونی مداخلت اور فرقہ واریت امت مسلمہ کو مزید تقسیم کر رہی ہیں۔
- بیشتر اسلامی ممالک خام مال پر انحصار کرتے ہیں اور صنعتی ترقی میں پیچھے ہیں۔
- غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور کرپشن اسلامی دنیا کے بڑے معاشی مسائل ہیں۔
- اقتصادی لحاظ سے اسلامی دنیا میں غیر مساوی تقسیم پائی جاتی ہے، خلیجی ممالک اور غریب مسلم ممالک کے درمیان بڑا فرق ہے۔
- اسلامی مالیاتی نظام کے قیام میں عملی مشکلات اور سودی معیشت پر انحصار امت مسلمہ کی معیشت کو مغرب کا محتاج بناتا ہے۔
- او آئی سی اور دیگر اسلامی ادارے مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
نتیجہ:
عالم اسلام کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی مسائل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اتحاد، خود انحصاری،
مضبوط قیادت اور جدید تعلیم و ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ اسلامی دنیا اگر اپنے فطری وسائل کو منصفانہ طور پر استعمال
کرے، سود سے پاک معاشی نظام قائم کرے اور داخلی خلفشار کو ختم کر کے اتحاد پیدا کرے تو یہ عالمی طاقت بن سکتی ہے۔
بصورت دیگر یہ تقسیم، کمزوری اور بیرونی انحصار کے چکر میں ہی پھنسی رہے گی۔
سوال نمبر 10:
جہاد کا مفہوم اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیجئے۔
تعارف:
جہاد اسلام کا ایک جامع اور ہمہ گیر تصور ہے جو صرف جنگ اور قتال تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ زندگی کے ہر شعبے
کو محیط ہے۔ لغوی اعتبار سے جہاد کا مطلب ہے “کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اور اپنی تمام تر توانائیاں کسی مقصد کے حصول
میں صرف کرنا”۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد سے مراد ہے: اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، ظلم و فساد کے خاتمے اور
انسانیت کی فلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ جہاد کبھی زبان، قلم، مال، علم اور کردار سے ہوتا ہے اور کبھی میدانِ جنگ
میں دشمنانِ اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے سے۔ اس لیے جہاد کو صرف قتال یا جنگ کے مترادف سمجھنا درست نہیں، بلکہ یہ
ایک ہمہ جہت دینی فریضہ ہے۔
جہاد کا مفہوم قرآن کی روشنی میں:
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جہاد کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
“اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے” (سورۃ الحج: 78)
ایک اور مقام پر فرمایا: “اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو” (سورۃ التوبہ:
41)
ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور
دین کی سربلندی کے لیے بھرپور کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔
جہاد کا مفہوم سنت کی روشنی میں:
نبی اکرم ﷺ نے بھی جہاد کی اہمیت اور مختلف صورتوں کو اجاگر فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے:
“تم میں بہترین جہاد یہ ہے کہ آدمی ظالم حکمران کے سامنے کلمۂ حق کہے۔” (ابو داؤد)
ایک اور موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: “مجاہد وہ ہے جو اپنی جان اور خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔”
(مسند احمد)
ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد کی کئی اقسام ہیں، اور یہ صرف تلوار یا جنگ سے محدود نہیں بلکہ نفس، زبان، قلم
اور
حق گوئی بھی جہاد ہے۔
جہاد کی اقسام:
اسلام میں جہاد کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں جنہیں درج ذیل عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے:
1. جہاد بالنفس (نفس کے خلاف جہاد):
سب سے پہلا اور اہم جہاد انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ یہ جہاد اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے، گناہوں سے
بچنے
اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس جہاد کو “اکبر جہاد” قرار دیا ہے کیونکہ سب سے بڑا دشمن
انسان کا اپنا نفس ہے۔
2. جہاد بالعلم و القلم (علم و قلم کے ذریعے جہاد):
علم کی اشاعت، دین کی تبلیغ، باطل نظریات کا رد، اور اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا بھی جہاد ہے۔ آج کے
دور میں میڈیا اور تعلیم کے میدان میں اسلام کی درست ترجمانی اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا جہاد بالقلم ہے۔
3. جہاد بالمال (مال کے ذریعے جہاد):
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد بالمال کو جہاد بالنفس کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ
اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ فلاحی کاموں، غربا کی مدد، دینی اداروں کی
سرپرستی، اور جہادی قافلوں کی معاونت جہاد بالمال کی مثالیں ہیں۔
4. جہاد باللسان (زبان کے ذریعے جہاد):
زبان کے ذریعے باطل نظریات کا رد، حق کی تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جہاد باللسان ہے۔ ظالم حکمران
کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی اسی جہاد کی ایک شکل ہے جیسا کہ حدیث میں آیا۔
5. جہاد فی سبیل اللہ (جہاد بالقتال):
یہ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب اسلام اور مسلمانوں پر کفر و باطل کی طرف سے حملہ ہو۔ یہ دفاعی نوعیت کا جہاد ہے جس
کا مقصد ظلم و جبر کا خاتمہ اور دین کی حفاظت ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا: “اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ
رہے اور دین پورا اللہ کے لیے ہو جائے” (الانفال: 39)
جہاد بالقتال ہمیشہ ریاستی سطح پر، امام یا خلیفہ کی قیادت میں کیا جاتا ہے۔ انفرادی طور پر یا ذاتی مفاد کے لیے
قتال جہاد نہیں بلکہ فساد ہے۔
جہاد کی اہمیت و مقاصد:
جہاد کے بنیادی مقاصد میں شامل ہیں: دین اسلام کی سربلندی، ظلم و جبر کا خاتمہ، مظلوموں کی مدد، عدل و انصاف کا
قیام،
اور انسانیت کی فلاح۔ جہاد کا مقصد کسی قوم کی زمین یا وسائل پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ امن قائم کرنا اور اللہ کے دین
کو غالب کرنا ہے۔
اہم نکات:
- جہاد لغوی طور پر کوشش اور جدوجہد کو کہتے ہیں۔
- قرآن و سنت میں جہاد کا تصور جامع ہے، صرف جنگ تک محدود نہیں۔
- جہاد کی بنیادی اقسام: جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالمال، جہاد باللسان اور جہاد بالقتال ہیں۔
- سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جدوجہد ہے۔
- جہاد بالقتال دفاعی نوعیت کا ہوتا ہے اور ریاستی سطح پر کیا جاتا ہے۔
- جہاد کا مقصد دین کی سربلندی، عدل و انصاف کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہے۔
نتیجہ:
جہاد اسلام کا ایک ہمہ گیر اور جامع تصور ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے۔ قرآن و سنت میں جہاد کو صرف جنگ کے
معنوں میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ اسے دین کی خدمت، ظلم کے خلاف جدوجہد، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، علم و قلم کے
ذریعے اسلام کی تبلیغ اور باطل کے رد تک وسیع کیا گیا ہے۔ جہاد بالقتال ایک اہم جہت ضرور ہے مگر یہ آخری مرحلہ ہے جو
مخصوص حالات میں اور ریاستی سطح پر ادا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاد کو اس کے صحیح اور متوازن مفہوم میں سمجھنا اور اس
پر عمل کرنا ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
سوال نمبر 11:
سنت کے لغوی معنی کیا ہیں اور شرعی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔
تعارف:
اسلام دو اہم ستونوں پر قائم ہے: کتابِ الٰہی (قرآنِ مجید) اور سیرت و سنتِ نبوی ﷺ۔ جہاں قرآنِ مجید ضابطۂ حیات کے
بنیادی اصول بیان کرتا ہے، وہیں سنت وہ عملی نمونہ اور تفصیلی رہنمائی ہے جو ان اصولوں کو عملی شکل دیتی ہے۔ سنت
کا مطالعہ نہ صرف فقہ و شریعت کی سمجھ کے لیے ضروری ہے بلکہ اخلاق، عبادات اور روزمرہ کے معاملات میں بھی اس کی
اہمیت
لازمی ہے۔
سنت کا لغوی مفہوم:
لغت میں لفظ “سنت” کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، معمول یا پیروی کا معمول۔ یہ لفظ مادۂ “سَنَّ” سے آیا ہے جس کے معنی
ہیں “اچھی روایت بنانا” یا “چلی آتی ہوئی روایات”۔ لغوی طور پر سنت سے وہ طریقہ مراد لیا جاتا ہے جو کسی شخص نے
قائم کیا ہو اور دوسروں کے لیے نمونہ بن گیا ہو۔
سنت کا شرعی (اصطلاحی) مفہوم:
شرعی اصطلاح میں “سنت” سے مراد وہ کلمات، افعال اور تقریرات ہیں جو نبیِ کریم ﷺ کی طرف منسوب ہوں اور امت نے ان
کو بطورِ نمونہ قبول کیا ہو۔ عام طور پر سنت کو تین حصوں میں بیان کیا جاتا ہے:
1. قولِ نبوی (جو کچھ آنحضرت ﷺ نے کہا)،
2. فعلِ نبوی (جو بعض اوقات عمل میں لائے گئے)، اور
3. تَقرِیرِ نبوی (جو وہ چیزیں تھیں جنہیں آپ ﷺ نے دوسروں کے متعلق برداشت کیا یا رضا مندی سے دیکھ
لیا)۔
اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ “سنت” وہ عملی اور بیانی نمونہ ہے جو قرآنِ مجید کی تشریح، توضیح اور عملی اطلاق کا
ذریعہ
بنتی ہے۔
سنت کی اقسام (شرعی اعتبار سے):
- سنت قولی: احادیثِ قوالی جو لفظی اقوالِ نبی ﷺ ہیں۔
- سنت فعلی: وہ افعال جو نبی ﷺ نے عملی طور پر انجام دیے، جیسے نماز کے افعال، سعی کا طریقہ وغیرہ۔
- سنت تَقرِیریہ (تصدیق): وہ عمل جو صحابہ کرام نے کیے اور نبی ﷺ نے ان پر خاموشی اختیار کی یا قبول فرمایا؛ یہ بھی سنت شمار ہوتی ہے۔
- سنت متواتر و آحاد: بعض روایات اتنے وسیع طریقے سے منقول ہوتی ہیں کہ ان کا انکار ناممکن ہے (متواتر)، اور بعض واحد یا محدود ذریعہ سے منقول ہوتی ہیں (آحاد)؛ فقہی حیثیت کے اعتبار سے دونوں کا وزن مختلف ہو سکتا ہے۔
سنت کی تحریر، روایت اور حفظ کا عمل:
صحابہ کرام نے سنت کو زبان زد اور عملی طور پر محفوظ رکھا؛ بعد ازاں محدثین نے احادیث کو مجموعوں کی شکل میں مرتب
کیا
(مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ)۔ علمِ حدیث کا ہر شق—سند، متن، رجال، طبقات—سنت کے معیارِ قبولیت
کو پرکھنے کے لیے وضع کیا گیا۔ اس علمی مشقت کے باعث سنت آج ایک منظم اور تحقیقی مواد کے طور پر دستیاب ہے۔
سنت کی اہمیت (تفصیلی نوٹ):
سنت قرآن کے بعد شریعتِ اسلامی کی سب سے اہم ماخذ سمجھائی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کئی جہتوں میں واضح ہوتی ہے:
- 1. ماخذِ شریعت میں مقام: سنت قرآن کے بعد شریعت کی دوسری وہ قابلِ استناد چیز ہے جس سے حکمِ شریعت اخذ کیا جاتا ہے۔ بسیاری مسائل میں قرآنِ مجید عموم یا اطلاق بیان کرتا ہے جبکہ تفصیل، بیان، یا طریقِ عمل سنت سے ملتی ہے۔
- 2. قرآن کی تفسیر و تشریح: بہت سی قرآنی آیات کی عملی تشریح سنت ہی سے ہوتی ہے؛ مثلاً نماز، روزہ، حج جیسی عبادات کے تفصیلی ارکان و طریقہ کار کا ماخذ سنت ہے۔ قرآن میں “نماز قائم کرو” آیا مگر نماز کے مخصوص انداز و اوقات و فرائض کی وضاحت احادیث اور سیرت سے ملتی ہے۔
- 3. عملی نمونہ و سیرتِ نبوی: سنت مسلمانوں کو ایک زندہ نمونہ دیتی ہے — نبی ﷺ کی سیرت ایک عملی نصاب ہے جو اخلاق، معاملات، حکمرانی، دعوت اور عبادات میں رہنمائی کرتی ہے۔ سیرت کی پیروی سے امت میں تہذیبی یکجہتی اور عملی مطابقِ شریعت پیدا ہوتی ہے۔
- 4. فقہی استنباط میں رہنما: فقیہہ اور مصلحین سنت کو اصولِ استنباط کا حصہ مانتے ہیں؛ مسائلِ جدید میں بھی سنت کی روشنی سے قیاس، استصحاب، اور مقاصدی اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ سنت اکثر ایسی مثالیں اور اصول دیتی ہے جو نئے معاملات پر راہِ حل فراہم کرتی ہیں۔
- 5. اخلاقی و تربیتی کردار: سنت میں اخلاق و آداب، حکمرانی کے اصول، معاشرتی آداب اور فردی تربیت کی جامع رہنمائی موجود ہے۔ سیرتِ نبوی میں رحمت، عدل، رواداری، صبر، شکر اور حسنِ سلوک کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔
- 6. وحدت امت و قانونی معیار: سنت نے امت میں افہام و تفہیم اور شرعی ضوابط متعین کیے؛ جب امت ایک متواتر سنت کی پیروی کرتی ہے تو اختلاف کم ہوتا ہے اور ایک عمومی قانونی بنیاد قائم ہوتی ہے۔
- 7. ثبوت و تحفظ: سند و متن کے تقویم کے ذریعے احادیث کی درجہ بندی سنت کی سچائی و افادیت کو یقینی بناتی ہے؛ اس علمِ حدیث نے غلط منسوب اقوال کی پہچان ممکن بنائی اور شریعت کے متفرق آئینے صاف رکھے۔
سنت اور قرآن کا باہمی تعلق:
سنت اور قرآن ایک دینی نظام کے دو لازمی ستون ہیں؛ قرآن کلیۃً ہدایتِ الٰہی ہے اور سنت اس کی تشریع و تفصیل ہے۔
فقہاء
کا اصول ہے کہ سنت قرآن کی تشریح ہے اور اگر کبھی ظاہری طور پر کنفلیکٹ محسوس ہو تو ارجحیت ہمیشہ قرآن کو
دی
جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر سنتِ متواتر سے کوئی معاملہ ثابت ہو تو اس کی حیثیت قطعی سمجھی جاتی ہے کیونکہ متواتر
روایت
کے ذریعے روایت کا یقین حاصل ہوتا ہے جو قرآن کے قریب تر سچائی کا درجہ لیتی ہے۔
سنت کے فقہی استعمال کے چند قواعد (مختصر):
- قرآن کے واضح حکم کے خلاف کبھی بھی سنت کو بطورِ حجت نہیں رکھا جا سکتا؛ قرآن کی تشریعِ اولیت ہے۔
- متواتر سنت کا ثبوت بہت مضبوط ہوتا ہے اور فقہی استدلال میں قطعی حیثیت رکھتا ہے۔
- آحاد احادیث بھی شریعت کی بنیاد بن سکتی ہیں، خاص طور پر اخلاقی، بیان و وضاحت یا مسائلِ عبادت کی تفصیل میں؛ البتہ قطعیت کے لئے ان کے سند و متن کی جانچ لازم ہے۔
- علمِ حدیث کے معیار (سند کا تسلسل، راویوں کی عدالت و ضبط، متن کی مخالفت وغیرہ) کے ذریعے سنت کی قبولیت پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔
سنت کی حفاظت و تدوین:
ابتدائی دور میں سنت کا ذریعہ زبانِ حال اور عملی نمونہ تھا؛ بعد ازاں محدثین نے قرونِ اوّلین سے احادیث کو جمع،
مرتب
اور درجہ بندی کی۔ کتباتِ صحیحہ (صحیح بخاری، صحیح مسلم) اور دیگر کتبِ احادیث کے مجموعے آج ہمارے پاس سنتِ نبوی
کی معتمد شدہ شکلیں ہیں۔ علمِ رجال، علمِ مصطلح الحدیث اور فنونِ تحقیق نے سنّت کو ایک محفوظ اور تحقیقی ماخذ بنایا۔
اہم نکات:
- سنت لغوی: طریقہ، روایات اور نمونہ؛ شرعی: قول، فعل اور توقیرِ نبوی کو کہتے ہیں۔
- سنت قرآن کی تشریح کا بنیادی ذریعہ ہے اور فقہ میں دوسری ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔
- سنت کی صحت و قبولیت کا تعین علمِ حدیث کے معیار سے ہوتا ہے (سند، متن، رجال وغیرہ)۔
- سنتِ متواتر کا ثبوت قطعی ہوتا ہے اور آحاد کا بھی فقہی اعتبار ہوتا ہے بشرطیکہ وہ قرآن یا اقویٰ نصوص سے متصادم نہ ہو۔
- سنت نے عبادات، اخلاق، معاشرت اور شریعت کے عملی پہلوؤں کو واضح کیا اور امت کو عملی رہنمائی دی۔
نتیجہ:
سنت وہ زندہ میراث ہے جو نبیِ کریم ﷺ نے امت کو چھوڑی۔ یہ محض تاریخی روایات نہیں بلکہ عملی ہدایت، نمونہِ حسنہ
اور شریعت کے نفاذ کا ذریعہ ہے۔ سنت کی روشنی میں ہی قرآنِ مجید کے مقاصد عملی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہر
مسلمان
کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح سنت کو پہچانے، اس کے اصول و ضوابط سمجھے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت دونوں کی روشنی
میں
عمل پیرا ہو۔ سنت کے بغیر اسلام کا عملی چہرہ ادھورا رہ جائے گا؛ اسی لیے علمِ حدیث، علمِ سیرت اور فقہ کی تعلیم
قرآنی
حُکم کو زندہ رکھتے ہوئے امت کی رہنمائی کا بنیادی وسیلہ ہیں۔
سوال نمبر 12:
ہجرت کا لغوی و اصطلاحی معنی تحریر کریں نیز ہجرت مدینہ کا واقعہ تحریر کریں۔
تعارف:
اسلام کی تاریخ میں “ہجرت” کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک نئی دینی
اور اجتماعی زندگی عطا کی بلکہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ برس تک دین کی دعوت و تبلیغ کی لیکن وہاں کفر،
شرک، ظلم و ستم اور معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگیا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ
کے حکم سے ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کیا۔
ہجرت کا لغوی معنی:
لفظ “ہجرت” عربی زبان کے مادہ “ہجر” سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں: “چھوڑ دینا، الگ ہونا، ترک کرنا یا کسی جگہ سے
دوسری
جگہ منتقل ہونا۔” لغت میں اس کے معنی کسی چیز کو چھوڑنے اور کسی نئی جگہ پر منتقل ہونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
ہجرت کا اصطلاحی معنی:
شریعتِ اسلامیہ کی اصطلاح میں ہجرت سے مراد ہے: “اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے
وطن، گھر بار اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر ایسی جگہ منتقل ہونا جہاں انسان اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرسکے۔”
قرآن و حدیث میں ہجرت کو ایک عظیم دینی فریضہ قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر جب وطن میں دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے۔
ہجرت مدینہ کا پس منظر:
مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتوں اور تکالیف کا سامنا تھا۔ کئی صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، بعض کو گرم
ریت پر لٹایا گیا، کئی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پتھر برسائے گئے اور
معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ ان حالات میں کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کرچکے تھے مگر مکمل سکون اور آزادی پھر بھی نہ ملی۔
ادھر مدینہ منورہ (یثرب) میں انصار کے قبائل (اوس و خزرج) اسلام قبول کرچکے تھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ منورہ اسلام کے مرکز کے
طور پر ابھرنے لگا۔
ہجرت مدینہ کا واقعہ:
قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو (نعوذباللہ) قتل کردیا جائے تاکہ اسلام کی دعوت ختم
ہوجائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی حفاظت میں لیا۔ اس موقع پر اللہ نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف
سفر فرمایا۔ تین دن تک آپ دونوں حضرات غار ثور میں چھپے رہے جہاں کفار قریش آپ کی تلاش میں پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ
کی قدرت سے وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت فکر لاحق ہوئی تو رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی: “لا تحزن إن الله معنا” (غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے)۔
غار سے نکل کر آپ نے مدینہ کی طرف سفر کیا۔ راستے میں کئی اہم واقعات پیش آئے، جیسے حضرت سراقہ بن مالک کا تعاقب اور معجزانہ حفاظت۔ بالآخر آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ کے باسیوں نے والہانہ استقبال کیا اور یوں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔
ہجرت مدینہ کی اہمیت:
- ہجرت مدینہ نے مسلمانوں کو دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا موقع دیا۔
- مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کا مرکز مسجد نبوی تھا۔
- اسلامی معاشرت، معیشت اور سیاست کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی۔
- ہجرت نے اسلام کے پیغام کو عرب کے دیگر علاقوں تک پھیلانے میں مدد دی۔
- یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے قربانی، صبر اور ایمان کا عملی نمونہ ہے۔
- ہجرت مدینہ اتنی اہم تھی کہ اسلامی تقویم (ہجری سال) اسی واقعہ سے شروع کی گئی۔
اہم نکات:
- “ہجرت” کے لغوی معنی ہیں ترک کرنا اور منتقل ہونا۔
- اصطلاحی طور پر ہجرت کا مطلب ہے دین کے لیے وطن اور گھر بار چھوڑ دینا۔
- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ظلم و ستم سے تنگ آکر اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔
- غار ثور کا واقعہ ہجرت کی یادگار اور اللہ کی نصرت کا عملی ثبوت ہے۔
- ہجرت کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔
- ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا نقطۂ آغاز اور ہجری کلینڈر کا سرچشمہ ہے۔
نتیجہ:
ہجرت مدینہ کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن مرحلہ تھا جس نے اسلام کو محدود
ظلم و ستم کے ماحول سے نکال کر عالمی سطح پر پھیلنے کی راہ ہموار کی۔ ہجرت نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ دین کی
سربلندی کے لیے قربانی ناگزیر ہے۔ آج بھی ہجرت کا سبق یہی ہے کہ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہوجائے تو اللہ اور اس کے
رسول کی رضا کے لیے ہر قربانی پیش کرنی چاہیے۔
سوال نمبر 13:
دین اسلام کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اہمیت پر تفصیل سے بحث کیجیے۔
تعارف:
“دین” کا لفظ اور خصوصاً “دینِ اسلام” کا تصور اسلام کی بنیادی شناخت اور عالمی پیغام کا محور ہے۔ دین نہ محض عبادات
اور رسمی فرائض کا مجموعہ ہے بلکہ انسان کی ذاتی، سماجی، اخلاقی، قانونی اور سیاسی زندگی کے نظم و ضبط کا جامع نظام
ہے۔ اسلام نے بشر کو ایک ایسا جامع ضابطہ فراہم کیا ہے جو فرد، خاندان، معاشرہ اور ریاست میں توازن، عدل اور فلاح
لانے کے قابل ہے۔ اس نوٹ میں ہم پہلے دین کے لغوی معنی، پھر اس کے شرعی/اصطلاحی معنی واضح کریں گے اور آخر میں دینِ
اسلام کی اہمیت کے مختلف پہلو مفصل انداز میں بیان کریں گے۔
دین کا لغوی معنی:
لفظ “دین” عربی اصل میں آتا ہے اور لغوی معنوں میں اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں: “واجب طور پر گردانا جانے
والا طریقہ،
طریقۂ کار، فرمانبرداری، سزا و جزا کا نظام، اور کسی کے حکم و راہ کی اطاعت”۔ اردو/فارسی میں بھی “دین” کو عموماً
مذہب یا راستہِ حیات کے طور پر سمجھا جاتا ہے—یعنی وہ طریقۂ زندگی جو انسان کو اپنے رب کے سامنے ذمّہ دار بناتا ہے۔
دین کا اصطلاحی (شرعی) معنی:
شرعی اصطلاح میں “دین” سے مراد ہے: “وہ کامل اور منظم نظامِ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام (قرآن) اور اپنے
رسول ﷺ کے ذریعے بشر تک پہنچایا؛ جو عقیدہ، عبادات، اخلاق، معاملات، قانون، سیاسی اصول، معاشرتی ضوابط اور
معاشی رہنمائی کا مجموعہ ہو”۔ اس تعریف میں یہ بات واضح ہے کہ دین صرف عقائد یا عبادات تک محدود نہیں بلکہ ایک
کثیرالجہتی ضابطہِ حیات ہے جو انسان کے ہر شعبے کو احکام و رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔
دینِ اسلام کے بنیادی عناصر (خلاصۂ اجزاء):
دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی اجزاء کو الگ کرنا مفید ہے۔ ان میں نمایاں ہیں:
- عقیدہ (العقائد): توحید، رسالت، معاد، فرشتے، کتبِ الٰہی وغیرہ۔
- عبادات (العبادات): نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ — فرد و اجتماعی عبادات۔
- اخلاق و تربیت (الاخلاق): سچائی، امانت، عدل، احسان، حُسنِ سلوک وغیرہ۔
- معاملات و قوانین (المعاملات): خاندانی قانون، معاہدات، تجارت، جرائم و سزائیں، وراثت کے اصول وغیرہ۔
- سیاسۃ و حکمروائی (السیاسة الشرعیہ): قیادت، انصاف، امن و تحفظ کے قواعد اور ریاستی اصول۔
- مقاصدِ شریعت (مقاصد): جان، دین، عقل، نسل اور مال کی حفاظت (مقاصدِ اسلامیہ)۔
دینِ اسلام کی اہمیت — مفصل بحث:
دینِ اسلام کی اہمیت کو مختلف زاویوں سے بیان کیا جا سکتا ہے؛ یہاں ہم ہر زاویے پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔
1) روحانی و نفسیاتی اہمیت (انفرادی نجات و سکون):
اسلام فرد کو روحانی شناخت اور زندگی کا مقصد فراہم کرتا ہے۔ ایمان انسان کو اضطراب، مایوسی اور بے معنویت سے محفوظ
رکھتا ہے۔ عبادات (نماز، روزہ، توبہ وغیرہ) انسان کو ذاتی کنٹرول، ضبط نفس اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ذریعے
قلبی سکون عطا کرتی ہیں۔ قرآن میں ہدایت کے ذریعے دلوں کو اطمینان پہنچانے کے وعدے متعدد مقامات پر موجود ہیں؛
اسلام انسان کی فطری تلاشِ معنی کو پورا کرتا ہے۔
2) اخلاقی و تربیتی اہمیت:
اسلام نے اخلاق کو شریعت کا لازمی جز بنایا۔ نبی کریم ﷺ کی سیرت اخلاقی نمونہ ہے—رحمت، شکر، صبر، عدل، انصاف اور
حسنِ سلوک کا درس۔ معاشرے کی بقا کیلئے اخلاقی تربیت نہایت ضروری ہے؛ اسلام نے اخلاقی اقدار کو عبادت کے درجے تک
پہنچایا (مثلاً سچ بولنا، امانتداری) تاکہ فرد و معاشرہ باہم مربوط رہیں۔
3) عدل و انصاف اور سماجی توازن:
اسلام نے عدل کو مرکزِ معاشرت قراردیا۔ شریعت کے قوانین، تعلیمی اصول، اور اقتصادی ضوابط سماج میں مساوات لا کر ظلم،
استحصال اور محرومیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات اور انصاف پسندانہ قوانین غربت کم کرنے اور وسائل
کی منصفانہ تقسیم میں مدد دیتے ہیں۔
4) قانون و حکمرانی کا نظام (شریعت بطورِ آئین):
اسلام نے ایک ایسا نظامِ قانون دیا جو ذاتی حقوق اور اجتماعی ذمہ داریوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ اسلامی شریعت
محض مذہبی رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ عدلیہ، معاہدات، تجارتی قوانین، وراثت کے اصول اور جزا و سزا کے ضابطے
بھی دیتی ہے۔ اس سے ریاستی نظام، انتظامی اصول اور عدالتی انصاف کے بنیادی ضوابط حاصل کیے جاتے ہیں۔
5) معاشی انصاف اور معاشی ضابطے:
اسلام نے اقتصادی معاملات میں اخلاقی حدود قائم کیں: ربا (سود) کی مذمت، تجارت میں شفافیت، حقوقِ محنت، زکوٰۃ
کے ذریعے فلاحی نظام، اور وراثت کے واضح اصول۔ یہ ضوابط معیشت میں صحت، شفافیت اور سماجی بہبود کی ضمانت دیتے ہیں۔
6) سیاسی و بین الاقوامی پہلو:
دین اسلام ایک بین الاقوامی نظریہ بھی پیش کرتا ہے—امتِ واحدہ کا تصور، حقوقِ غیر مسلم، جنگ و امن کے اصول، اور
سفارت
کاری کے اہداف۔ اسلام نے جنگ میں بھی اخلاقی حدود (مثلاً غیر جنگجوؤں کا تحفظ) مقرر کیے ہیں۔ یہ اصول بین الاقوامی
تعاون، امن پسندی اور انسانی حقوق کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
7) تعلیمی و علمی اہمیت:
اسلام نے علم کو بڑا درجہ دیا؛ پہلی وحی “اقْرَأْ” تھی—یعنی پڑھو۔ علم و تحقیق، فہم نصوص اور علمِ حدیث و فقہ
کے ذریعے امت نے سائنسی، فکری اور ثقافتی ترقی کی راہیں اپنائیں۔ اسلام معلوماتی ترقی کو اخلاقی حدود کے اندر
رہ کر فروغ دیتا ہے۔
8) تہذیبی اور ثقافتی اثرات:
اسلام نے فنونِ لطیفہ، عمارت، ادب، زبان اور معاشرتی آداب پر گہرے اثرات ڈالے۔ اسلامی تہذیب نے مختلف ادوار میں
دنیا کو سائنس، طب، فلسفہ اور فنون میں اہم خدمات دیں۔ دین نے ایک ایسی ثقافتی شناخت عطا کی جو قیامِ معاشرت میں
معاون رہی۔
9) مقاصدِ شریعت (Maqasid al-Shariah) اور عملی تحفظ:
شریعت کے بنیادی مقاصد—حفظِ دین، حفظِ جان، حفظِ عقل، حفظِ نسل اور حفظِ مال—اسلام کی عملی حکمرانی اور قانون
سازی کا مقصد بتاتے ہیں۔ یہ مقاصد اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام کا بنیادی مقصد انسان کی فلاح و بہبود ہے، نہ کہ محض
رسومی پابندیاں۔
قرآن و سنت کی روشنی میں دینِ اسلام کی جامعیت:
قرآن نے اسلام کو “مکمل دین” قرار دیا ہے: “اليوم أكملت لكم دينكم…” (المائدة:3) — یعنی دین کی تکمیل کا
اعلان۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا: “إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَامُ” (آل عمران:19) یعنی اللہ
کے نزدیک دین وہی
ہے جو اللہ کی طرف رجوع اور اطاعت ہو۔ نیز قرآن نے حضور ﷺ کو رحمتِ عالمین قرار دیا: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ” (الانبياء:107) — یہ آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اسلام ایک مکمل، رحمت والا اور عالمی
پیغام ہے۔
دینِ اسلام کے عملی چیلنجز اور ضرورتِ جدید استنباط:
جدید دور میں اسلام کے اطلاق میں چند چیلنجز درپیش ہیں: سیکولر ازم، جدید انسانی حقوق کے تصورات، سائنسی ترقیات، اور
عالمی قانون سازی کے تقاضے۔ اس لیے فقہِ اسلامی میں ijtihad، مقاصدی فکر اور معاصر مسائل پر استدلال کی ضرورت ہے
تاکہ
دین کی روح کے مطابق جدید حالات کا حل پیش کیا جا سکے—بغیر بنیادی اصولوں کو نقصان پہنچائے۔
اہم نکات (خلاصہ):
- دین لغوی طور پر طریقۂ کار/راستہ ہے؛ شرعی طور پر یہ اللہ کا وہ مکمل نظامِ ہدایت ہے جو عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور قوانین پر مشتمل ہے۔
- اسلامی دین فردی، سماجی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کی جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
- دین کے مقاصدِ شریعت انسان کی حفاظت اور فلاح کے گرد گھومتے ہیں: دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت۔
- قرآن و سنت دینِ اسلام کو مکمل، جامع اور عالمگیر قرار دیتی ہیں۔
- جدید دور میں دین کے عملی اطلاق کے لیے علمائے کرام، فقہا اور مفکرین کا مقاصدی استنباط ضروری ہے۔
نتیجہ:
دینِ اسلام محض عبادات یا اخلاقی نصائح کا مجموعہ نہیں؛ یہ انسان کے وجود کے ہر پہلو کو منظم کرنے والا ایک مکمل
ضابطہ ہے—روحانی
سکون سے لے کر اجتماعی عدل، ذاتی اخلاق سے لے کر ریاستی قوانین تک۔ اس کی اہمیت اس وقت بہتر طور پر سمجھ آئے گی جب
اس
کو ایک مربوط نظام کے طور پر اپنایا جائے—علم، عمل، عدل اور رحمت کے ساتھ۔ اسلام نے انسان کو وہ رہنمائی دی ہے جس کے
ذریعے فرد اور معاشرہ دونوں ترقی کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس کے بنیادی اصولوں کی روح کو مدنظر رکھ کر قابلِ تقلید عملی
نظام وضع کیا جائے۔
سوال نمبر 14:
مسلمانوں کی علمی خدمات پر جامع نوٹ تحریر کریں۔
تعارف:
اسلام کے آغاز ہی سے علم کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی “اقْرَأْ” سے نازل ہوئی، جس نے
مسلمانوں کو علم حاصل کرنے، تحقیق کرنے اور کائنات کے راز جاننے کی طرف متوجہ کیا۔ حضور ﷺ نے علم کو ہر مسلمان مرد و
عورت پر فرض قرار دیا۔ اسی تعلیم سے متاثر ہو کر مسلمان سائنس، فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات، جغرافیہ، تاریخ، معاشیات،
زبان و ادب سمیت مختلف علوم میں دنیا کی رہنمائی کرنے لگے۔ مسلمانوں کی علمی خدمات نے یورپ کے نشاۃ ثانیہ
(Renaissance) کو
جنم دیا اور آج کی سائنسی ترقی انہی بنیادوں پر کھڑی ہے۔
قرآن و حدیث کے علوم میں خدمات:
مسلمانوں نے سب سے پہلے قرآن و حدیث کے علوم پر بے مثال کام کیا۔ مفسرین جیسے امام طبری، زمخشری، فخر الدین رازی نے
تفسیر القرآن کے میدان میں علمی شاہکار چھوڑے۔ محدثین جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو
داؤد اور امام ابن ماجہ نے احادیث کے مستند مجموعے مرتب کیے۔ اصولِ حدیث اور جرح و تعدیل کے اصولوں نے تحقیق کے
جدید معیارات قائم کیے، جنہیں آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے۔
فقہ اور قانون میں خدمات:
فقہ اسلامی مسلمانوں کا عظیم علمی کارنامہ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے
مختلف مکاتب فکر کو جنم دیا، جنہوں نے نہ صرف دینی معاملات بلکہ معاشرتی، معاشی اور قانونی مسائل کا حل فراہم کیا۔
اسلامی قانون دنیا کے قدیم ترین قانونی نظاموں میں شمار ہوتا ہے، جو آج بھی مختلف ممالک کے آئین اور قوانین کی بنیاد
ہے۔
طب و علم الادویہ میں خدمات:
مسلمانوں نے طب میں حیرت انگیز ترقی کی۔ ابو علی سینا (ابن سینا) کی کتاب “القانون فی الطب” صدیوں تک یورپ کی
یونیورسٹیوں میں نصاب رہی۔ الرازی نے چیچک اور خسرہ پر پہلی بار تحقیقی کام کیا اور “الحاوی” جیسی عظیم کتاب لکھی۔
زہراوی کو سرجری کا بانی کہا جاتا ہے، جس نے آلاتِ جراحی ایجاد کیے۔ ان خدمات نے طب کو ایک باقاعدہ سائنسی علم کی
شکل دی۔
ریاضی اور فلکیات میں خدمات:
الخوارزمی کو “الجبر” کا بانی کہا جاتا ہے، جس نے ریاضی کو نئی بنیادیں فراہم کیں۔ “الجبرا” اور “الگورزم” جیسے
الفاظ انہی کے نام سے ماخوذ ہیں۔ مسلمان فلکیات کے ماہرین البتانی، البیرونی اور نصیر الدین طوسی نے ستاروں کی
گردش، وقت کی پیمائش، اور تقویم کی تیاری میں شاندار کام کیا۔ اندلس میں مسلم ماہرین فلکیات نے رصد گاہیں قائم کیں
اور جدید فلکیاتی علوم کی بنیادیں رکھیں۔
جغرافیہ اور سفرنامہ نگاری میں خدمات:
مسلمانوں نے جغرافیہ میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ الادریسی نے دنیا کا پہلا جامع نقشہ بنایا۔ ابن بطوطہ نے دنیا کے
مختلف خطوں کے سفرنامے تحریر کیے جو آج بھی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ یعقوبی، ابن حوقل اور المسعودی نے
زمین کی پیمائش، ممالک کی تقسیم اور مختلف اقوام کے حالات پر علمی کام کیا۔
فلسفہ و منطق میں خدمات:
فلسفہ و منطق کے میدان میں الکندی، الفارابی، ابن رشد اور ابن طفیل کے نام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے یونانی
فلسفے کو عربی میں منتقل کیا، اس پر تنقید کی اور اپنی نئی آراء پیش کیں۔ ابن رشد کی شروحات نے یورپی فلسفیوں جیسے
تھامس ایکویناس پر گہرا اثر ڈالا۔ ان مسلم فلسفیوں نے علم و عقل کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر ایک متوازن نظریہ پیش کیا۔
کیمیاء اور طبیعیات میں خدمات:
جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے، جس نے مختلف تیزاب دریافت کیے اور سائنسی تجربات کی بنیاد رکھی۔
البیرونی
نے طبیعیات اور ارضیات میں حیرت انگیز تحقیقات کیں۔ ابن الہیثم نے بصریات (Optics) میں تجرباتی طریقہ اپنایا اور
روشنی
کے انعکاس و انعطاف پر انقلابی نظریات پیش کیے۔ یہ سب جدید سائنس کی بنیادیں ہیں۔
زبان و ادب میں خدمات:
مسلمانوں نے عربی زبان کو بین الاقوامی علمی زبان بنایا۔ عباسی دور میں “دار الحکمہ” قائم ہوا، جہاں تراجم اور
تصانیف
کا عظیم سلسلہ شروع ہوا۔ فارسی اور اردو ادب میں بھی مسلمان علماء اور شعرا نے دنیا کو عظیم ذخیرہ دیا۔ فردوسی،
رومی، حافظ، سعدی، علامہ اقبال جیسے شعرا نے نہ صرف ادب بلکہ فکر و فلسفہ پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔
اہم نکات:
- قرآن و حدیث کی حفاظت اور ان کے علوم کی تدوین مسلمانوں کی اولین علمی خدمت ہے۔
- فقہ اسلامی نے دنیا کو جامع قانونی نظام فراہم کیا۔
- ابن سینا، الرازی اور زہراوی نے طب میں انقلابی خدمات انجام دیں۔
- الخوارزمی، البتانی اور نصیر الدین طوسی نے ریاضی و فلکیات میں نئی راہیں کھولیں۔
- الادریسی اور ابن بطوطہ نے جغرافیہ میں عملی اور تحقیقی کام کیا۔
- الفارابی اور ابن رشد نے فلسفہ و منطق کو عقل و مذہب کے امتزاج سے مضبوط کیا۔
- جابر بن حیان اور ابن الہیثم نے کیمیا اور طبیعیات کی بنیادیں رکھیں۔
- زبان و ادب کے فروغ میں رومی، سعدی اور اقبال جیسے مفکرین نے انسانیت کی رہنمائی کی۔
نتیجہ:
مسلمانوں کی علمی خدمات انسانی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت کے علم سے رہنمائی لے کر دنیاوی علوم میں
بھی ایسی بنیادیں رکھیں جن پر جدید سائنس و ٹیکنالوجی کھڑی ہے۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ مسلمانوں کی انہی علمی خدمات کا
مرہونِ منت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی شاندار علمی روایت کو دوبارہ زندہ کریں، تحقیق اور اجتہاد کی
روش اپنائیں اور دنیا کی رہنمائی کے لیے اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کریں۔
سوال نمبر 15:
درج ذیل آیت مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط
أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾
تعارف:
سورۃ الحجرات کی یہ آیت مسلمانوں کو آدابِ رسالت اور نبی اکرم ﷺ کے مقام و مرتبے کا درس دیتی ہے۔ یہ آیت ان ابتدائی
آیات میں شامل ہے جنہیں قرآن نے مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی آداب کے لیے بنیاد بنایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے
اہلِ ایمان کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ اپنے نبی ﷺ کے سامنے ادب، احترام اور عاجزی کا مظاہرہ کریں
اور اپنی آواز کو آپ ﷺ کی آواز سے بلند نہ کریں۔ یہ حکم نہ صرف ظاہری ادب کے لیے ہے بلکہ یہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا
ہے کہ ایمان کی تکمیل نبی ﷺ کے احترام اور اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔
ترجمہ:
“اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی ان سے یوں بلند آواز میں بات کرو جیسے تم آپس
میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔” (الحجرات: 2)
شانِ نزول:
مفسرین کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر بلند آواز میں بات
کرنے لگے۔ خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے درمیان کسی معاملے پر گفتگو میں آواز بلند ہوگئی۔
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ نبی ﷺ کے سامنے آواز بلند کرنا ایمان کے آداب کے خلاف ہے۔
تفسیر:
اس آیت میں کئی اہم نکات شامل ہیں:
1. نبی ﷺ کی عظمت: نبی ﷺ کی ذات مقدسہ کا ادب ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آواز کو بلند نہ کرنا اس بات کی علامت
ہے کہ آپ ﷺ کا رتبہ عام انسانوں سے مختلف ہے۔
2. ادب کا معیار: جس طرح عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، اس انداز میں نبی ﷺ سے بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ عاجزی،
نرمی اور ادب سے گفتگو کرنی چاہیے۔
3. اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ: نبی ﷺ کے سامنے بے ادبی یا بے توقیری سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع
ہوسکتے ہیں۔ گویا ادبِ رسول ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔
4. باطنی و ظاہری ادب: صرف آواز ہی نہیں بلکہ دل میں بھی نبی ﷺ کا احترام ہونا چاہیے۔
اثرات و اسباق:
یہ آیت مسلمانوں کو زندگی بھر کے لیے یہ سبق دیتی ہے کہ:
– ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ نبی ﷺ کی اطاعت و تعظیم بھی اس کا حصہ ہے۔
– نبی ﷺ کے ادب کے بغیر عبادات اور اعمال ضائع ہوسکتے ہیں۔
– دین میں اجتماعی نظم و ضبط اور بزرگوں کے احترام کو اہمیت دی گئی ہے۔
– آج کے دور میں بھی یہ حکم ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ نبی ﷺ کی سنت اور احادیث کا احترام کریں، ان پر
اعتراضات اور طنزیہ گفتگو سے اجتناب کریں۔
– علما اور دینی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو میں بھی ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نبی ﷺ کی وراثت کے امین ہیں۔
اہم نکات:
- آیت میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔
- نبی ﷺ کے سامنے آواز بلند کرنا منع ہے۔
- عام گفتگو کے انداز میں نبی ﷺ سے بات کرنا آداب کے خلاف ہے۔
- بے ادبی کے نتیجے میں اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔
- ادبِ رسول ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے۔
نتیجہ:
سورۃ الحجرات کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ادب محض ظاہری نہیں بلکہ قلبی اور عملی بھی ہونا چاہیے۔ آپ ﷺ
کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا اس حقیقت کا اظہار ہے کہ آپ ﷺ کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر آج کے مسلمان اس
تعلیم پر عمل کریں اور نبی ﷺ کی سنت و احادیث کو عزت و احترام دیں تو نہ صرف ان کا ایمان مضبوط ہوگا بلکہ ان کی دنیا
و آخرت بھی سنور جائے گی۔
سوال نمبر 16:
انبیاء کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔
تعارف:
اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء ہی اللہ
کے
منتخب بندے ہیں جن کے ذریعے انسانیت کو ہدایت، ایمان، اخلاق اور شریعت کے اصول سکھائے گئے۔ انبیاء کی اطاعت دراصل
اللہ
کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وحی کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں بارہا
مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کریں اور ان کی سنت کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔
قرآن میں انبیاء کی اطاعت کا حکم:
قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہے:
’’اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی بھی جو تم میں صاحبِ امر ہیں‘‘
(النساء: 59)
اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور رسولﷺ کی اطاعت ساتھ ساتھ فرض ہے۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ
کے احکام کو ماننے کا لازمی حکم دیا:
’’اور رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آجاؤ‘‘ (الحشر: 7)
قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رسولﷺ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے:
’’جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی‘‘ (النساء: 80)
سنت نبوی کی روشنی میں اطاعت کی اہمیت:
نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو ہمیشہ اللہ کے احکامات پر چلنے اور آپ ﷺ کی سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ آپ ﷺ نے
فرمایا:
’’تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیم کے تابع نہ ہو‘‘
(مشکوٰۃ)
اسی طرح آپ ﷺ نے اپنی امت کو وصیت کی کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ کبھی گمراہ نہ ہوں۔ یہ بات واضح
کرتی ہے کہ نجات اور کامیابی صرف نبی اکرم ﷺ کی اطاعت میں ہے۔
انبیاء کی اطاعت کے فوائد:
- ہدایت کا ذریعہ: انبیاء کی اطاعت انسان کو سیدھی راہ پر قائم رکھتی ہے اور بھٹکنے سے بچاتی ہے۔
- اللہ کی رضا: نبی کی اطاعت دراصل اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔
- اخلاقی تربیت: انبیاء کی زندگی انسان کے لیے عملی نمونہ ہے، جس پر چل کر اعلیٰ اخلاق اپنائے جا سکتے ہیں۔
- دنیا و آخرت کی کامیابی: اطاعتِ انبیاء سے دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت کی ضمانت ملتی ہے۔
انبیاء کی اطاعت نہ کرنے کے نتائج:
قرآن میں ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، جیسے قومِ نوح، قومِ عاد اور قومِ ثمود۔ ان کی
نافرمانی کے
نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ واقعات اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ انبیاء کی اطاعت نہ کرنے سے دنیا میں
ذلت اور آخرت میں عذاب یقینی ہے۔
اہم نکات:
- انبیاء علیہم السلام اللہ کے منتخب نمائندے ہیں۔
- ان کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔
- قرآن و سنت میں اطاعتِ رسول کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے۔
- اطاعت کے نتیجے میں دنیاوی اور اخروی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔
- انبیاء کی نافرمانی کرنے والی قومیں اللہ کے غضب کا نشانہ بنیں۔
نتیجہ:
انبیاء کی اطاعت دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ایمان
اسی وقت مکمل ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ انبیاء کی اطاعت کو چھوڑ دینا گمراہی اور تباہی کا راستہ
ہے۔
لہٰذا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو انبیاء خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ﷺ کی تعلیمات کے
مطابق
گزارے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔
سوال نمبر 17:
درج ذیل احادیثِ مبارکہ کا ترجمہ و تشریح کریں:
1۔ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ
2۔ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
تعارف:
احادیثِ مبارکہ اسلامی تعلیمات کا وہ بنیادی ذریعہ ہیں جو قرآنِ مجید کے بعد انسان کو ہدایت فراہم کرتے ہیں۔ نبی
کریم ﷺ کے اقوال و افعال ہمارے لیے عملی رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ زیرِ بحث احادیث میں ایک طرف دنیا کے عارضی پن اور
آخرت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف مسلمان کی اصل پہچان یعنی دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ
رکھنا واضح کیا گیا ہے۔ یہ دونوں احادیث دراصل اسلامی اخلاقیات کی بنیاد اور ایک مسلمان کے طرزِ زندگی کا جامع خلاصہ
ہیں۔
پہلی حدیث: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ
ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: “دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزر مسافر ہو۔” (صحیح
بخاری)
تشریح:
اس حدیثِ مبارکہ میں دنیا کی حقیقت کو نہایت حکیمانہ انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، نہ یہاں کسی
کو ہمیشہ رہنا ہے اور نہ یہ انسان کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اجنبی اور مسافر کی مثال دے کر یہ بتایا گیا کہ مسلمان کو
دنیا میں دل لگانے کے بجائے اسے عارضی قیام گاہ سمجھنا چاہیے اور اصل منزل یعنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔
جیسے مسافر ایک سرائے میں آ کر صرف تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح
مومن کو بھی دنیاوی آسائشوں اور فانی لذتوں میں الجھنے کے بجائے آخرت کے دائمی اور ابدی سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔
قرآنِ مجید بھی اس مضمون کی تائید کرتا ہے:
“وَما الحَياةُ الدُّنيا إِلّا مَتاعُ الغُرورِ” (آلِ عمران: 185)
ترجمہ: “دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔”
اس حدیث کا عملی پیغام یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے ہمیشہ آخرت کی کامیابی کو مقدم رکھنا
چاہیے۔ دنیا کی محبت اور مال و دولت کا لالچ انسان کو اصل مقصدِ حیات سے غافل نہ کر دے۔
دوسری حدیث: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: “مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔” (صحیح
بخاری و مسلم)
تشریح:
اس حدیث میں ایک سچے مسلمان کی اصل پہچان بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمان صرف نام یا نسب سے
نہیں بنتا بلکہ اس کی عملی زندگی اور کردار سے اس کی مسلمانی ظاہر ہوتی ہے۔
زبان اور ہاتھ وہ دو بڑے ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زبان کے ذریعے غیبت، بہتان، جھوٹ،
گالی اور دل آزاری کی جاتی ہے جبکہ ہاتھ کے ذریعے مارنا، ستانا، دھوکہ دینا اور ناحق کسی کا مال لینا شامل ہے۔ ایک
حقیقی مسلمان ان دونوں ذرائع کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے معاشرے کے ہر فرد کو امن اور سکون فراہم کرتا ہے۔
قرآنِ کریم میں بھی یہی تعلیم ملتی ہے:
“وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا” (البقرہ: 83)
ترجمہ: “اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔”
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام امن، سلامتی اور بھلائی کا دین ہے اور مسلمان کا وجود دوسروں کے لیے خیر اور سکون کا
ذریعہ ہونا چاہیے۔
اہم نکات:
- پہلی حدیث میں دنیا کی عارضی حقیقت اور آخرت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔
- دنیا کو مستقل ٹھکانہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے سفر کی ایک منزل تصور کیا جائے۔
- دوسری حدیث میں مسلمان کی اصل پہچان بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔
- زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھنا ایمان اور اخلاق کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔
- اسلام امن، اخوت، اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔
نتیجہ:
ان دونوں احادیثِ مبارکہ کا مشترکہ پیغام یہ ہے کہ مسلمان کو دنیاوی زندگی کو اصل مقصود نہ سمجھتے ہوئے آخرت کی
تیاری کرنی چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں ایسا کردار اپنانا چاہیے جس سے دوسروں کو امن، سکون اور بھلائی حاصل ہو۔
دنیا کو سرائے سمجھ کر یہاں صرف اتنا عمل کیا جائے جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور اپنی زبان و ہاتھ کو قابو
میں رکھ کر انسانیت کی خدمت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ یہی حقیقی اسلام کی روح ہے۔
سوال نمبر 18:
عصر حاضر میں مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی مسائل پر علیحدہ علیحدہ نوٹ تحریر کریں۔
تعارف:
عصرِ حاضر میں مسلم دنیا سیاسی اور اقتصادی دونوں پہلوؤں سے کئی مسائل کا شکار ہے۔ اگرچہ مسلم ممالک دنیا کے نقشے پر
ایک وسیع خطے پر پھیلے ہوئے ہیں اور تیل، گیس، معدنیات اور انسانی وسائل کے لحاظ سے دنیا کی اہم طاقت بن سکتے ہیں،
مگر بدقسمتی سے سیاسی انتشار، قیادت کی کمی، داخلی خلفشار اور عالمی طاقتوں کے اثر و رسوخ نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔
یہ مسائل نہ صرف مسلم ممالک کے اندرونی حالات کو متاثر کرتے ہیں بلکہ عالمی سیاست اور معیشت میں بھی ان کے مقام کو
کمزور بناتے ہیں۔ ذیل میں ان مسائل کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔
مسلمانوں کے سیاسی مسائل:
مسلم دنیا کو سب سے زیادہ جس بحران کا سامنا ہے وہ سیاسی ہے۔ یہ بحران کئی جہتوں کا حامل ہے:
1. سیاسی عدم استحکام: بیشتر مسلم ممالک میں جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہیں۔ فوجی مداخلت، بادشاہت یا آمرانہ
طرزِ حکومت کی وجہ سے عوامی نمائندگی کمزور ہے۔ اس کے نتیجے میں عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کی کمی پائی جاتی
ہے۔
2. فرقہ واریت اور داخلی انتشار: شیعہ سنی تنازعات، لسانی اور نسلی اختلافات نے مسلم دنیا کو تقسیم کر دیا
ہے۔ یہ داخلی خلفشار اکثر بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے۔
3. بیرونی مداخلت: مشرقِ وسطیٰ اور دیگر مسلم خطے بڑی طاقتوں کے لیے دلچسپی کا مرکز ہیں۔ تیل، گیس اور
جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے مغربی طاقتیں اکثر مسلم ممالک کی پالیسیوں پر اثرانداز ہوتی ہیں۔ نتیجتاً مسلم ممالک اپنی
خودمختاری کھو بیٹھتے ہیں۔
4. فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ: یہ دو بڑے عالمی تنازعات مسلم دنیا کی یکجہتی اور عالمی حیثیت کا امتحان ہیں۔
فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور کشمیر میں بھارتی مظالم کے باوجود مسلم دنیا کا مؤثر اور متحدہ موقف سامنے نہیں
آیا۔
5. قیادت کا فقدان: مسلم دنیا کو ایسی مؤثر اور بصیرت رکھنے والی قیادت میسر نہیں جو امت مسلمہ کو ایک پلیٹ
فارم پر جمع کر سکے۔ نتیجتاً OIC جیسے ادارے بھی محض رسمی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔
6. آزادیٔ اظہار اور انسانی حقوق کی کمی: کئی مسلم ممالک میں صحافت، اظہارِ رائے اور بنیادی آزادیوں پر
پابندیاں ہیں، جو سیاسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔
مسلمانوں کے اقتصادی مسائل:
سیاسی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کو بڑے پیمانے پر اقتصادی مسائل کا بھی سامنا ہے:
1. غربت اور بے روزگاری: دنیا کے کئی غریب ترین ممالک کا تعلق مسلم دنیا سے ہے۔ افریقی مسلم ممالک خصوصاً
نائجیریا، سوڈان اور صومالیہ غربت، قحط اور بے روزگاری کے شکار ہیں۔
2. وسائل کا ضیاع: تیل اور گیس کے وافر ذخائر کے باوجود بیشتر مسلم ممالک اپنی معیشت کو پائیدار ترقی کی طرف
نہیں لے جا سکے۔ ان وسائل کو تعلیم، سائنسی ترقی اور صنعت کاری کے بجائے عیش و عشرت اور دفاعی اخراجات پر استعمال
کیا جاتا ہے۔
3. تعلیمی پسماندگی: مسلم ممالک میں شرح خواندگی عالمی اوسط سے کم ہے۔ سائنسی و ٹیکنالوجی کے میدان میں
پسماندگی معیشت کی ترقی کو محدود کرتی ہے۔
4. غیر ملکی قرضوں کا بوجھ: اکثر مسلم ممالک عالمی مالیاتی اداروں (IMF, World Bank) کے قرضوں تلے دبے ہوئے
ہیں۔ ان قرضوں کی شرائط ملکی خودمختاری اور اقتصادی پالیسی کو متاثر کرتی ہیں۔
5. صنعتی و ٹیکنالوجی کی کمی: مسلم ممالک زیادہ تر خام مال (Raw Material) برآمد کرتے ہیں اور تیار شدہ
مصنوعات درآمد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھتا ہے۔
6. عدم مساوات: چند تیل سے مالا مال مسلم ممالک انتہائی خوشحال ہیں جبکہ باقی ممالک غربت و بدحالی میں ڈوبے
ہوئے ہیں۔ اس معاشی تفاوت نے مسلم دنیا کے اتحاد کو بھی کمزور کر دیا ہے۔
7. عالمی معیشت پر انحصار: مسلم ممالک اپنی معیشت کے لیے مغربی ممالک پر انحصار کرتے ہیں۔ نتیجتاً ان کی
پالیسیاں اکثر بیرونی دباؤ کے تحت بنتی ہیں۔
اہم نکات:
- مسلم دنیا سیاسی عدم استحکام، فرقہ واریت اور بیرونی مداخلت کا شکار ہے۔
- فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل مسلم ممالک کی یکجہتی کے فقدان کو ظاہر کرتے ہیں۔
- اقتصادی طور پر مسلم دنیا غربت، بے روزگاری اور تعلیمی پسماندگی میں مبتلا ہے۔
- تیل و گیس کے ذخائر کے باوجود وسائل کے بہتر استعمال کی کمی ہے۔
- مسلم دنیا عالمی مالیاتی اداروں اور مغربی طاقتوں پر انحصار کرتی ہے۔
- قومی و بین الاقوامی سطح پر مؤثر قیادت اور پالیسی سازی کا فقدان ہے۔
نتیجہ:
عصرِ حاضر میں مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی مسائل کی جڑ داخلی کمزوریاں اور بیرونی دباؤ ہیں۔ اگر مسلم دنیا اپنے
وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرے، تعلیم اور سائنس پر سرمایہ کاری کرے، جمہوری اداروں کو مضبوط بنائے اور ایک
متحدہ پلیٹ فارم پر عالمی طاقتوں کا سامنا کرے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم ممالک
اندرونی انتشار ختم کریں، مشترکہ اقتصادی و سیاسی پالیسی بنائیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انصاف،
مساوات اور اتحاد کو فروغ دیں۔ یہی راستہ مسلمانوں کو ترقی، وقار اور عالمی قیادت کی طرف لے جا سکتا ہے۔