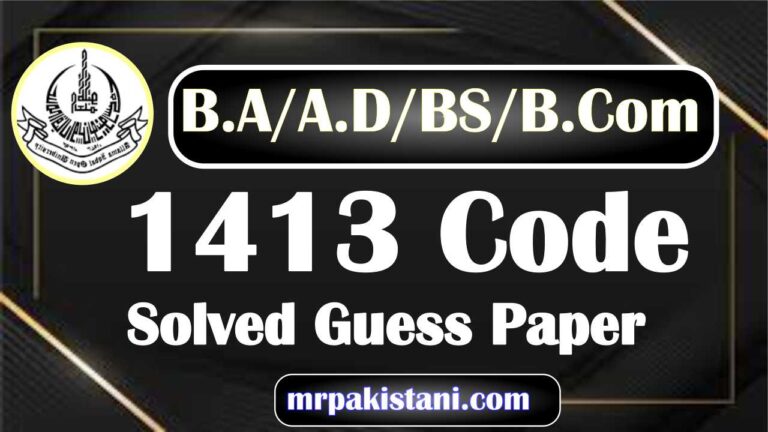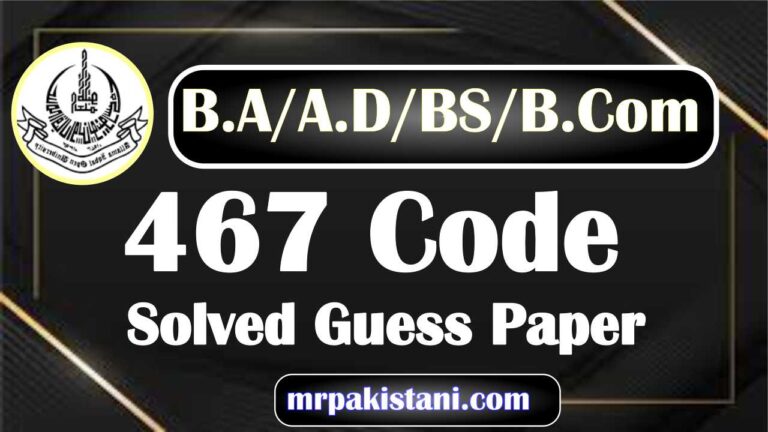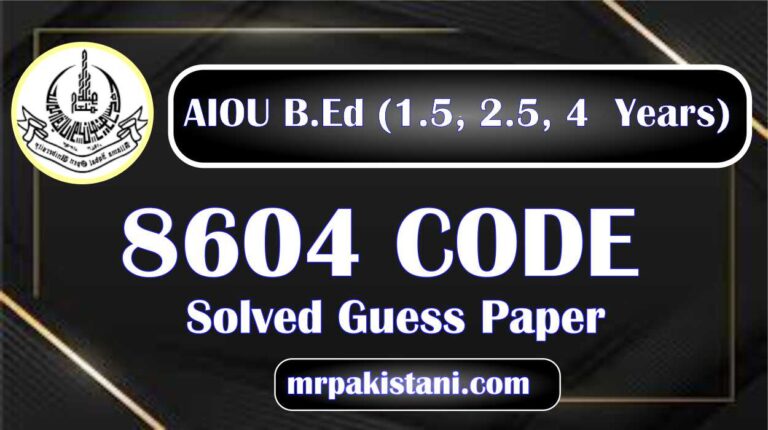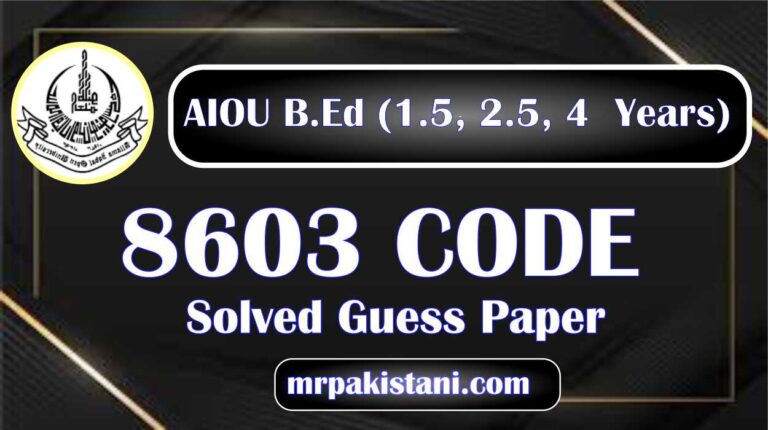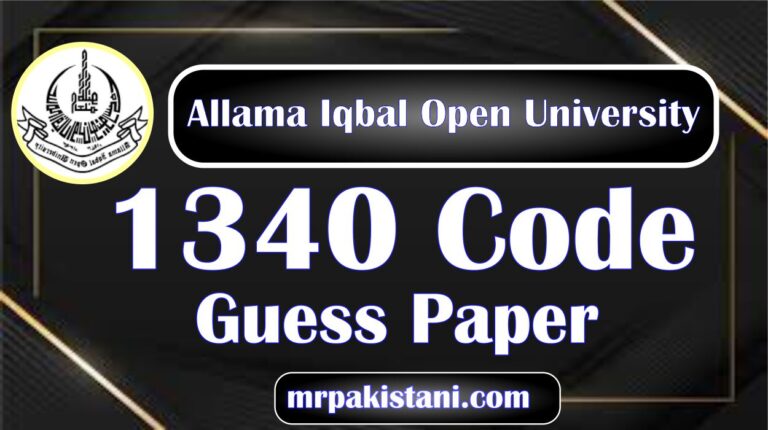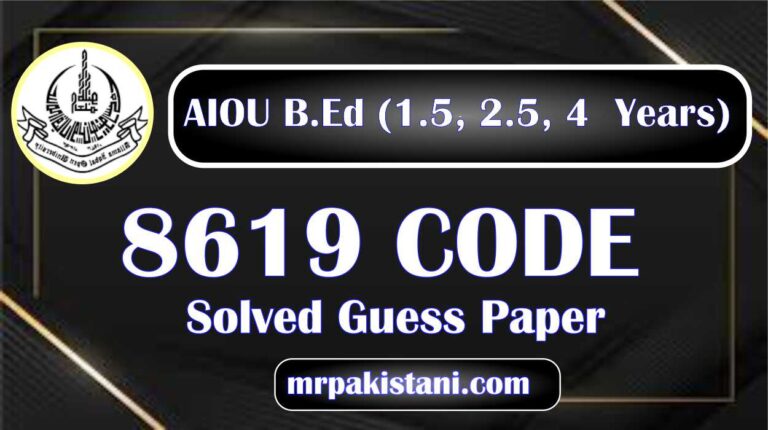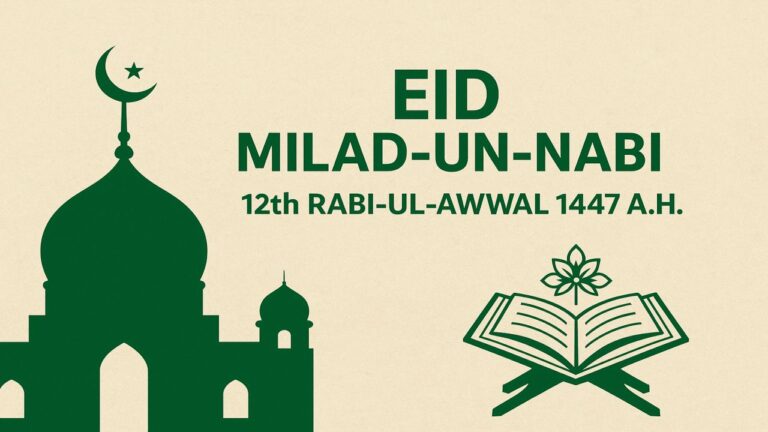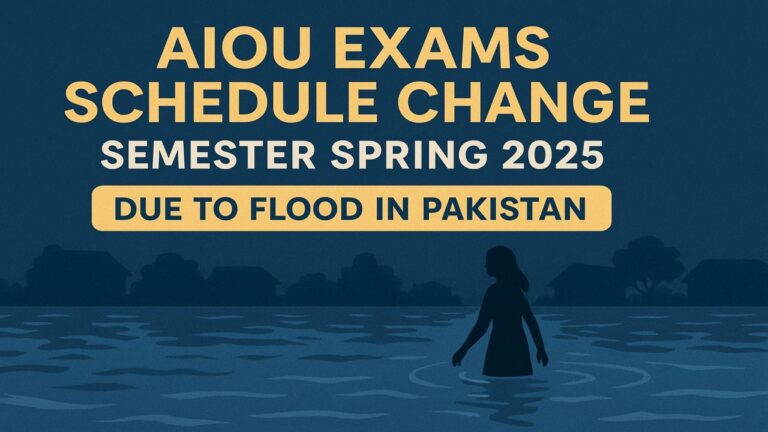AIOU 472 Code Quran-e-Hakim Guess Paper
AIOU 472 Code Quran-e-Hakim Guess Paper – Get well-prepared for your exams with our specially designed Guess Paper for AIOU 472 Code Quran-e-Hakim (کتاب: قرآنِ حکیم). This guess paper focuses on the most important topics and frequently asked questions from the syllabus. It covers essential surahs, translation-based questions, tafseer, and core Islamic concepts to guide students effectively in their preparation.
If you’re looking for more educational support like solved assignments, past papers, and additional guess papers, head over to mrpakistani.com. Also, subscribe to our YouTube channel Asif Brain Academy for video-based learning and tips for success.
AIOU 472 Code Quran-e-Hakim Guess Paper
سوال نمبر 1:
سورۃ البقرہ کی آیات کی روشنی میں “گائے کا واقعہ” اور “ہاروت و ماروت کا قصہ” پر نوٹ لکھیں۔
تعارف:
سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے کئی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو نصیحت ملے اور وہ ان غلطیوں سے بچیں
جو
پچھلی امتوں نے کیں۔ ان میں دو اہم واقعات نمایاں ہیں: “گائے کا واقعہ” اور “ہاروت و ماروت کا قصہ”۔ یہ دونوں واقعات
ایمان، اطاعت اور اللہ کی آزمائشوں کے تناظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔
گائے کا واقعہ:
قرآن مجید میں (سورۃ البقرہ: 67-73) گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل کا واقعہ پیش آیا جس میں
قاتل
نامعلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کے ذریعے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کی ایک حصے کو مقتول کے
جسم
سے لگایا جائے۔ اس معجزہ سے مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیتا۔
مگر بنی اسرائیل نے سادہ حکم پر عمل کرنے کے بجائے بار بار غیر ضروری سوالات کیے، مثلاً گائے کی عمر کیا ہو؟ رنگ
کیسا
ہو؟ کیسی خصوصیات ہوں؟ آخرکار جب وہ سخت شرائط پوری کرتے کرتے ایک گائے لائے اور ذبح کی، تب جا کر حکم پورا ہوا۔
یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے احکام پر بلا چوں و چرا عمل کرنا چاہیے، ورنہ زیادہ بحث و سوالات
انسان
کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔
اہم اسباق:
- اللہ کے حکم پر سیدھا اور فوری عمل کرنا سب سے بہتر ہے۔
- بے جا سوالات اور ٹال مٹول انسان کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔
- اطاعتِ الٰہی ہی اصل کامیابی کی راہ ہے۔
ہاروت و ماروت کا قصہ:
قرآن مجید (سورۃ البقرہ: 102) میں ہاروت و ماروت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے بابل شہر (عراق) میں
لوگوں کو جادو کی حقیقت بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ لوگوں کو آزمانے کے لیے جادو سکھاتے لیکن ساتھ ہی یہ بھی
کہتے:
“ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔”
مگر لوگ ان کی نصیحت کو نظرانداز کرتے ہوئے جادو سیکھنے لگے اور اسے اپنے مقاصد، خصوصاً میاں بیوی میں جدائی ڈالنے
کے
لیے استعمال کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جادو کا اثر صرف اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور جو لوگ اس پر یقین کر کے اسے اختیار
کرتے ہیں وہ اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔
اہم اسباق:
- جادو حقیقت رکھتا ہے مگر یہ کفریہ عمل ہے۔
- اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
- دنیاوی فائدے کے لیے ایمان اور آخرت کو ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔
نتیجہ:
گائے کا واقعہ اور ہاروت و ماروت کا قصہ دونوں ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت پر سیدھا اور خلوص کے ساتھ عمل
کرنا چاہیے۔ غیر ضروری بحث و سوالات یا دنیاوی لالچ انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب
وہی
لوگ ہوتے ہیں جو ایمان، صبر اور اطاعت اختیار کرتے ہیں۔
سوال نمبر 2:
سورۃ البقرہ کی آیات کی روشنی میں “قصہ آدم و ابلیس” کی تفصیل بیان کریں۔
تعارف:
قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس کئی مقامات پر بیان ہوا ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی آیات (30 تا 39) میں اس واقعے کو
خصوصی انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کی
نافرمانی کے ساتھ ساتھ انسان کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنے کی حکمت بھی واضح کی ہے۔ یہ قصہ ایمان، اطاعت اور نافرمانی
کے نتائج کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔
آدم علیہ السلام کی تخلیق:
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا آپ ایسے کو
پیدا کریں گے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا: “میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔” اس کے بعد اللہ
تعالیٰ نے آدمؑ کو پیدا فرمایا اور انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا تاکہ آدمؑ کا
مقام ظاہر ہو۔
سجدے کا حکم:
اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدمؑ کو سجدہ کریں۔ سب نے اطاعت کی مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا اور
کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدمؑ مٹی سے۔ اس نافرمانی پر اللہ نے اسے لعنت کا مستحق قرار دے کر ذلیل و رسوا کر
دیا۔
آدم و حواؑ کا امتحان:
اللہ نے آدمؑ اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور کہا کہ سب کچھ کھاؤ پیو مگر ایک درخت کے قریب نہ
جانا۔ لیکن ابلیس نے انہیں بہکا دیا اور وہ اس درخت کے قریب گئے۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکال کر
زمین پر بھیج دیا گیا۔ تاہم اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور ہدایت بھی نازل کی تاکہ وہ دنیا میں زندگی گزار
سکیں۔
اہم اسباق:
- انسان کو اللہ نے عزت و شرف دے کر خلیفہ مقرر کیا ہے۔
- علم انسان کی سب سے بڑی فضیلت ہے جس کی بنیاد پر فرشتوں نے آدمؑ کے سامنے عاجزی کی۔
- تکبر سب سے بڑا گناہ ہے، یہی ابلیس کی ہلاکت کا سبب بنا۔
- انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن سچی توبہ اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔
- دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے جہاں اللہ کی ہدایت پر چلنا اصل کامیابی ہے۔
نتیجہ:
قصہ آدم و ابلیس ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہی اصل کامیابی ہے جبکہ نافرمانی اور تکبر بربادی کا راستہ
ہیں۔ انسان علم، عبادت اور توبہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن غرور اور شیطان کی پیروی اسے ہمیشہ خسارے
میں ڈال دیتی ہے۔
سوال نمبر 3:
درج ذیل آیت کا ترجمہ، شانِ نزول اور مباہلہ کی شرعی حیثیت پر مفصل نوٹ تحریر کریں: “فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ”
تعارف:
قرآن مجید کی یہ آیت (سورۃ آل عمران: 61) “آیتِ مباہلہ” کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمدﷺ کو
حکم
دیا کہ نصاریٰ نجران کے پادریوں اور علما کے ساتھ حق و باطل کے فیصلے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ یہ آیت اسلامی تاریخ
میں ایک نہایت اہم واقعہ سے جڑی ہوئی ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوا۔
آیت کا ترجمہ:
“پھر کہہ دو (اے نبیﷺ) آؤ! ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم
اپنی
عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو، پھر ہم دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔”
شان نزول:
یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہﷺ سے حضرت عیسیٰؑ کی
حقیقت پر گفتگو کرنے لگے تو انہوں نے عیسیٰؑ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ آپﷺ نے قرآن کی آیات کے ذریعے وضاحت کی کہ حضرت
عیسیٰؑ
اللہ کے نبی اور بندے ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ مگر وہ ضد پر قائم رہے۔ آخرکار اللہ نے اپنے نبیﷺ کو حکم دیا کہ ان
سے
مباہلہ کیا جائے، یعنی سب اپنے اہلِ خانہ کو لے کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔
روایت کے مطابق رسول اللہﷺ اپنے ساتھ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو لے کر نکلے۔ جب عیسائیوں
نے
یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور مباہلے سے انکار کر دیا اور صلح کا معاہدہ کر کے واپس لوٹ گئے۔
مباہلہ کی شرعی حیثیت:
- مباہلہ کا مقصد حق و باطل میں فیصلہ کرانا ہے جب دلیل اور منطق سے معاملہ طے نہ ہو۔
- یہ ایک غیر معمولی صورت ہے اور عام حالات میں اسے اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ صرف آخری حجت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
- مباہلہ میں صدق دل سے حق پر قائم ہونا ضروری ہے، ورنہ جھوٹا شخص اللہ کی لعنت اور عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔
- یہ واقعہ اسلام کی سچائی اور رسول اللہﷺ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپﷺ نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اہلِ بیت کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لیے نکلنے کا اعلان فرمایا۔
اہم اسباق:
- اسلامی تعلیمات میں دلیل و برہان کو اولین اہمیت حاصل ہے، مگر ضد کی صورت میں مباہلہ ایک حتمی راستہ ہے۔
- اہلِ بیت کی عظمت و مقام اس واقعے سے اجاگر ہوتا ہے کہ رسول اللہﷺ انہیں ساتھ لے کر مباہلے کے لیے نکلے۔
- باطل ہمیشہ حق کے سامنے جھک جاتا ہے جیسا کہ نجران کے عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر کے صلح کر لی۔
- یہ آیت مسلمانوں کے لیے اس بات کا درس ہے کہ حق پر ڈٹے رہنے کے لیے یقین اور اخلاص سب سے بڑی طاقت ہے۔
نتیجہ:
آیتِ مباہلہ اسلام کی صداقت، رسول اللہﷺ کی نبوت کی سچائی اور اہلِ بیت کی فضیلت کا عظیم ثبوت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے
کہ
باطل کے مقابلے میں دلیل و برہان سے بات کی جائے، اور اگر معاملہ پھر بھی نہ طے ہو تو اللہ کی عدالت میں مباہلہ کے
ذریعے فیصلہ کروایا جا سکتا ہے۔ تاہم مباہلہ ایک غیر معمولی شرعی عمل ہے جسے صرف انتہائی ضرورت میں اختیار کیا جانا
چاہیے۔
سوال نمبر 4:
سورۃ آلِ عمران میں “وفد نجران” کے واقعے کی تفصیل بیان کریں۔
تعارف:
قرآن مجید کی سورۃ آلِ عمران میں “وفد نجران” کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب
مدینہ منورہ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھ کر نجران (یمن کے علاقے) کے عیسائی علماء اور سردار رسول اللہﷺ
کے
پاس آئے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور اسلام کی دعوت کے بارے میں بحث و مکالمہ کیا جا سکے۔ یہ واقعہ
اسلامی تاریخ میں “مباحثہ نجران” اور “مباہلہ” کے نام سے مشہور ہے۔
وفد نجران کی آمد:
نجران کے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد (تقریباً ساٹھ افراد پر مشتمل) مدینہ آیا۔ ان میں سردار اور مذہبی پیشوا بھی شامل
تھے۔ یہ لوگ اپنے خوبصورت لباس اور مذہبی جاہ و جلال کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ ان کا مقصد رسول اللہﷺ سے
مناظرہ کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے عقائد کا دفاع کرنا تھا۔
گفتگو اور دلائل:
عیسائی وفد نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰؑ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ الوہیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہﷺ نے قرآن کی آیات کے
ذریعے واضح فرمایا کہ عیسیٰؑ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، جیسا کہ حضرت آدمؑ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طرح عیسیٰؑ
بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، نہ کہ الوہیت کی دلیل۔
اس کے باوجود نجران کے وفد نے اپنی ضد برقرار رکھی اور قرآن کے دلائل کو ماننے سے انکار کر دیا۔
آیت مباہلہ کا نزول:
جب بحث و مباحثہ کے باوجود کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے آیتِ مباہلہ (آل عمران: 61) نازل فرمائی:
“فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ…”
اس آیت کے مطابق فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں فریق اپنے اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ باہر آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو
جھوٹا
ہو اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔
رسول اللہﷺ کا اہلِ بیت کو ساتھ لانا:
مباہلے کے لیے رسول اللہﷺ اپنے ساتھ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو لے کر نکلے۔ یہ منظر دیکھ
کر نجران کے عیسائی سردار خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے: “اگر یہ واقعی مباہلہ کر بیٹھے تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔”
چنانچہ انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور صلح پر آمادہ ہو گئے۔
صلح کا معاہدہ:
عیسائی وفد نے معاہدہ کیا کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے مگر جزیہ ادا کر کے مسلمانوں کی حکومت کے زیرِ سایہ امن و
سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ یوں یہ مسئلہ جنگ کے بجائے پرامن معاہدے سے حل ہوا۔
اہم نتائج اور اسباق:
- یہ واقعہ اسلام کی صداقت اور قرآن کے دلائل کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔
- اہلِ بیت کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ رسول اللہﷺ نے انہیں مباہلے کے لیے اپنے ساتھ لیا۔
- اسلام دشمنوں سے مناظرہ اور مکالمہ علمی انداز میں کرتا ہے، نہ کہ صرف قوت کے ذریعے۔
- یہ واقعہ بتاتا ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے سامنے دب جاتا ہے، جیسا کہ نجران کے وفد نے مباہلے سے پیچھے ہٹ کر صلح کو اختیار کیا۔
- اسلام امن و رواداری کا دین ہے جو اختلاف کے باوجود پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔
نتیجہ:
سورۃ آل عمران میں بیان کیا گیا “وفد نجران” کا واقعہ اس بات کی عظیم مثال ہے کہ اسلام دلیل، حکمت اور حق کے ساتھ
باطل کو شکست دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان پر قائم رہنا، اہلِ بیت کا احترام کرنا اور پرامن مکالمے کے ذریعے
حق کی وضاحت کرنا اسلامی طرزِ عمل ہے۔
سوال نمبر 5:
سورۃ البقرہ کی آیات کے ذریعے “ایمان” کے موضوع پر نوٹ لکھیں۔
تعارف:
سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے جس میں ایمان کے بنیادی تقاضے، اس کے ثمرات اور ایمان والوں کے اوصاف
کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ایمان اسلام کی بنیاد اور ہر نیک عمل کی روح ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہی میں
ایمان والوں کے اوصاف ذکر کر کے واضح کر دیا گیا کہ کامیابی انہی کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ تقویٰ اور عملِ صالح کو
اپناتے ہیں۔
ایمان کے بنیادی اجزاء سورۃ البقرہ میں:
- ایمان بالغیب:
سورت کے آغاز (آیت 3) میں فرمایا گیا کہ مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں، آخرت اور ان امور پر یقین رکھتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے مگر وحی کے ذریعے ثابت ہیں۔ - ایمان بالکتب:
ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ تمام الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں (آیت 4)۔ یعنی صرف قرآن پر ہی نہیں بلکہ تورات، انجیل اور دیگر سابقہ صحیفوں کو بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں۔ - ایمان بالرسل:
اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ کی متعدد آیات (مثلاً آیت 136) میں وضاحت ہے کہ ایمان والے تمام انبیاء کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے۔ - ایمان بالآخرت:
آخرت کے دن اور جزا و سزا پر ایمان ایمان کی تکمیل کا لازمی حصہ ہے۔ سورۃ البقرہ (آیت 4) میں مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
ایمان والوں کی خصوصیات سورۃ البقرہ میں:
- نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو زندگی کا مرکز بناتے ہیں۔
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں اور محتاجوں کا حق ادا کرتے ہیں۔
- مشکلات میں صبر اور آزمائش میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔
- ایمان کے ساتھ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔
ایمان کے فوائد اور نتائج:
- ایمان والے ہدایت اور فلاح پاتے ہیں (آیت 5)۔
- ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں پر خوف اور غم نہیں ہوگا (آیت 62)۔
- ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اللہ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔
- ایمان انسان کو نفاق اور کفر سے بچا کر سیدھی راہ پر قائم رکھتا ہے۔
چیلنجز اور ایمان کی آزمائش:
سورۃ البقرہ میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ ایمان کا دعویٰ زبانی نہیں بلکہ عمل اور قربانی سے پرکھا جاتا ہے۔ اہلِ
ایمان پر مصائب آئیں گے، کبھی بھوک اور خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا (آیت 155)۔ لیکن صبر اور استقامت ہی ایمان کی
سچائی کا ثبوت ہے۔
نتیجہ:
سورۃ البقرہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ ایک عملی طرزِ زندگی ہے جو غیب پر یقین، اللہ کی
اطاعت، انبیاء کی تصدیق، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان ہی انسان کو اللہ کی رحمت کا
مستحق بناتا ہے اور حقیقی کامیابی اسی میں مضمر ہے۔
سوال نمبر 6:
سورۃ آلِ عمران اور سورۃ البقرہ کا تعارف مختصر بیان کریں۔
تعارف:
قرآنِ حکیم کی دونوں طویل سورتیں “سورۃ البقرہ” اور “سورۃ آلِ عمران” کو ایک ساتھ “زہراوین” کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں
ایمان، ہدایت، شریعت، صبر و جہاد اور اسلامی معاشرت کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ ان میں نہ صرف عقائد کو
مضبوط کرنے کا پیغام ہے بلکہ اہلِ کتاب کے اعتراضات کے جوابات بھی بیان کیے گئے ہیں۔
سورۃ البقرہ کا تعارف:
- ترتیب اور مقامِ نزول: یہ قرآن کی دوسری سورت ہے اور سب سے طویل سورت ہے۔ مدنی سورت ہے جس میں 286 آیات ہیں۔
- اہم موضوعات:
- ایمان بالغیب، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ۔
- بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر۔
- قبلہ کی تبدیلی (بیت المقدس سے کعبہ کی طرف)۔
- جہاد، روزہ، حج، نکاح و طلاق اور معاملاتِ زندگی کے احکام۔
- آیت الکرسی (ایمان کی اساس)۔
- خصوصیات: یہ سورت مسلمانوں کے لیے ایک مکمل آئین کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: “جو گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔”
سورۃ آلِ عمران کا تعارف:
- ترتیب اور مقامِ نزول: قرآن کی تیسری سورت ہے، مدنی سورت ہے جس میں 200 آیات ہیں۔
- اہم موضوعات:
- اللہ کی واحدانیت اور دینِ اسلام کی حقانیت۔
- اہلِ کتاب (خصوصاً عیسائیوں) سے مکالمہ اور وفدِ نجران کے سوالات کے جوابات۔
- غزوۂ بدر اور غزوۂ احد کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے دروس۔
- ایمان، صبر، تقویٰ اور اتحاد کی تعلیم۔
- انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں قربانی کی ترغیب۔
- خصوصیات: اس سورت میں اہلِ ایمان کو مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے، اہلِ کتاب کے اعتراضات کا مدلل جواب دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔
مشترکہ خصوصیات:
دونوں سورتیں اسلام کے عقائد، عبادات، اخلاقیات اور اجتماعی زندگی کے اصولوں کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ان میں ایمان
کے استحکام، اللہ پر توکل، صبر اور جہاد کی روح اجاگر کی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں سورتوں کو روشنی کا ذریعہ
قرار دیا ہے۔
نتیجہ:
سورۃ البقرہ اور سورۃ آلِ عمران قرآن کریم کی وہ بنیادی سورتیں ہیں جو ایک مسلمان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے
لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ایک طرف یہ ایمانیات اور احکامِ شریعت واضح کرتی ہیں تو دوسری طرف مشکلات اور
فتنوں میں ثابت قدمی کا پیغام دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو قرآن کی “زہراوین” کہا جاتا ہے اور ان کی تلاوت
ایمان کے نور اور قلبی سکون کا ذریعہ ہے۔
سوال نمبر 7:
سورۃ آلِ عمران کی روشنی میں حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کے واقعات کی تفصیل بیان کریں۔
تعارف:
سورۃ آلِ عمران (آیات: 33–37، 42–47، 59) میں حضرت مریمؑ کے خاندان، ان کی ولادت و پرورش، اللہ کی جانب سے ان کے
انتخاب
اور پھر حضرت عیسیٰؑ کی معجزانہ پیدائش کی بشارت نہایت جامع انداز میں بیان ہوئی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت مریمؑ کی ولادت اور حضرت عیسیٰؑ کی ولادت دونوں اللہ کی خاص مشیت اور کُنْ فَيَكُون کے اصول پر قائم
معجزات ہیں جو انسان کو توحید، تقدیرِ الٰہی پر یقین اور اطاعتِ ربانی کی طرف بلاتے ہیں۔
حضرت مریمؑ: نسب و خاندان کا انتخاب
سورۃ آلِ عمران مریمؑ کے خاندانی پس منظر سے آغاز کرتی ہے: اللہ نے آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ کے خاندان اور عمران کے
خاندان کو اہلِ عالم پر منتخب فرمایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریمؑ ایک پاکیزہ، منتخب اور موحد خانوادے
میں
پیدا ہوئیں جہاں دین داری، نذر اور عبادت کی روایت راسخ تھی۔
نذرِ والدہ اور مریمؑ کی ولادت:
عمران کی بیوی نے اپنے ہاں ہونے والی اولاد کو اللہ کی راہ کے لیے مخصوص کرنے کی نذر مانی: “اے پروردگار! جو میرے
پیٹ میں ہے اسے تیرے نام وقف کرتی ہوں۔” جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے عرض کیا: “پروردگار! یہ تو بیٹی ہوئی ہے”
(اور اللہ بہتر جانتا تھا جو پیدا ہوا)، پھر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کے لیے اللہ کی
پناہ طلب کی۔ اس مرحلے پر قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے مریمؑ کو بہترین قبولیت عطا فرمائی، انہیں خوب نشوونما
دی اور ان کی کفالت حضرت زکریاؑ کے سپرد کر دی۔
پرورش، عبادت گاہ اور کراماتِ طفولیت:
مریمؑ کی پرورش عبادت گاہ (محراب) میں ہوئی۔ حضرت زکریاؑ جب محراب میں آتے تو ان کے پاس بے موسم رزق پاتے۔ سوال
کرتے: “اے مریم! یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟” وہ کہتیں: “یہ اللہ کی طرف سے ہے۔” اس واقعے سے مریمؑ کی
تقویٰ، توکل اور اللہ کے خصوصی فضل کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی پاکیزہ فضا ان کے اس عظیم معجزے کے لیے
تمہید بنی جو آگے وقوع پذیر ہونا تھا۔
اللہ کی جانب سے انتخاب اور تزکیہ:
فرشتوں نے مریمؑ سے کہا: “اے مریم! اللہ نے تمہیں چن لیا، پاکیزہ رکھا اور دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی۔ اے مریم!
اپنے پروردگار کے حضور جھک جاؤ، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔” یہ تعلیمات مریمؑ کے باطنی
تزکیہ، عبادت گزاری اور عفت و عصمت کی تکمیل ہیں۔
حضرت عیسیٰؑ کی بشارت: “کَلِمَةٌ مِّنْهُ”
فرشتوں نے مریمؑ کو خوش خبری دی: “اللہ تمہیں اپنی ایک کلمہ (کلمۃُ اللہ) کی بشارت دیتا ہے جس کا نام
المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں وجیہ (عزت والے) ہوں گے اور مقربین میں سے
ہوں گے۔ وہ گہوارے میں بھی کلام کریں گے اور بڑھاپے میں بھی، اور صالحین میں سے ہوں گے۔” اس بشارت میں عیسیٰؑ کی
نسبتِ الیٰ اللہ بطور “کلمہ” بیان ہوئی—یعنی اللہ کے حکم “ہو جا” سے ان کی تخلیق—نہ کہ الوہیت کی دلیل۔
اسی بشارت میں ان کے معجزات (مثلًا جھولے میں کلام) اور مقام و مرتبہ بھی بیان ہوا۔
مریمؑ کا سوال اور معجزۂ تخلیق:
مریمؑ نے پوچھا: “پروردگار! مجھے بچہ کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی مرد نے نہ چھوا؟” جواب ملا: “اللہ جو چاہتا ہے پیدا
کرتا ہے؛ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتا ہے ‘ہو جا’ اور وہ ہو جاتا ہے۔” یہاں اصولِ تخلیق
کُنْ فَيَكُون کو واضح کیا گیا—یعنی حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش بغیر باپ، محض اللہ کے حکم سے
ہوئی، جیسا کہ حضرت آدمؑ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا (آل عمران: 59)۔
عیسیٰؑ کے آنے کا مقصد اور پیشگی نشانیاں:
آلِ عمران بتاتی ہے کہ عیسیٰؑ بنی اسرائیل کے لیے رسول ہوں گے، اللہ کے اذن سے معجزات کے حامل ہوں گے، اور
توراة
کی تصدیق اور بعض حلال و حرام میں تخفیف کی بشارت دیں گے۔ یہ سارا تعارف قبل از ولادت دیا جا رہا ہے تاکہ
واضح ہو کہ یہ ولادت کسی انسانی منصوبے کی نہیں بلکہ الٰہی منصبِ رسالت کے قیام کی تمہید ہے۔
واقعاتِ ولادت کا خلاصہ (سورۃ آلِ عمران کے مطابق):
- عمران کے خاندان کا انتخاب؛ ایک موحد، پاکیزہ نسبت کا تعین۔
- مریمؑ کی والدہ کی نذر اور مریمؑ کی پیدائش، نام رکھنا اور اللہ کی پناہ میں دینا۔
- اللہ کی “قبولیتِ حسنہ”: مریمؑ کی غیر معمولی نشوونما اور کفالتِ زکریاؑ؛ محراب میں بے موسمی رزق۔
- فرشتوں کی ندا: مریمؑ کی تطہیر، انتخاب اور عبادت کی تاکید۔
- بشارتِ عیسیٰؑ: “کلمۃٌ منہ”—المسیح عیسیٰ ابن مریم؛ دنیا وآخرت میں وجاہت، گہوارے اور عنفوانِ شباب میں کلام۔
- معجزۂ تخلیق: “کُنْ فَيَكُون”—بغیر باپ کے پیدائش؛ اللہ کے ارادہ و امر سے کارِ تخلیق۔
- عقلی مثال: “مثَلُ عیسٰی عندَ اللہ کَمَثَلِ آدم”—الٰہی قدرت کا تسلسل اور توحیدی عقیدہ کی تقویت۔
عقائدی و شرعی نکات:
- توحید اور قدرتِ باری تعالیٰ: عیسیٰؑ کی ولادت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، الوہیت کی دلیل نہیں۔ نسبتِ “کلمہ” سے مراد الٰہی حکم کے ذریعے تخلیق ہے، نہ کہ خدانواز (نعوذ باللہ) نسبت۔
- عفت و عصمتِ مریمؑ: قرآن مریمؑ کی پاکدامنی کی شہادت دیتا ہے؛ وہ منتخب، مطہرہ اور قانتہ ہیں۔ عورت کی عزت و عظمت اور دینی قیادت میں اس کے مقام کو واضح کیا گیا۔
- نذر اور وقفِ اولاد: مریمؑ کی والدہ کی نذر سے معلوم ہوا کہ اولاد کی دینی تربیت اور اسے دین کے لیے وقف کرنا مقبول عمل ہے۔
- نبوتِ عیسیٰؑ: آلِ عمران عیسیٰؑ کو اللہ کا رسول قرار دیتی ہے؛ ان کی رسالت، معجزات اور شریعتی رہنمائی سب اللہ کے اذن سے ہیں۔
- ایمان بالملائکہ و الوحی: فرشتوں کا نزول اور بشارت دینا وحی کے نظام اور ایمان بالغیب کی اساس کو مضبوط کرتا ہے۔
دروس و اسباق:
- نسبتِ ایمان اصل شرف ہے؛ اللہ جسے چاہے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔
- پاکیزہ ماحول، عبادت اور ذکر نوجوانی میں بھی کرامتِ باطن پیدا کرتے ہیں—مریمؑ کی پرورش اس کی مثال ہے۔
- اللہ کی راہ میں اخلاص سے کی گئی نذر “قبولیتِ حسنہ” بن جاتی ہے اور پھر اللہ خود کفالت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔
- معجزات توحید کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؛ قدرتِ الٰہی کے سامنے اسباب مقہُور ہیں۔
- عیسیٰؑ کی مثالِ آدمؑ شبہاتِ الوہیت کا علمی رد ہے اور عقیدۂ توحید کو دلائل کے ساتھ واضح کرتی ہے۔
نتیجہ:
سورۃ آلِ عمران میں حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کا بیان انسانی تاریخ کے دو بلند ترین مقدسات—عفتِ مریمؑ
اور
قدرتِ الٰہی—کو روشن کرتا ہے۔ مریمؑ کا انتخاب، ان کی عبادت گزاری اور پھر عیسیٰؑ کی کُنْ فَيَكُون سے
پیدائش اس حقیقت پر مہرِ تصدیق ہے کہ ہدایت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ واقعات ایمان، توکل، عبادت اور توحید کے
عنوانات کو زندگی کے مرکز میں رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔
سوال نمبر 8:
سورۃ آلِ عمران آیت 144 کا ترجمہ و تشریح کریں:
“وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ”
تعارف:
سورۃ آلِ عمران کی یہ آیت اُحد کے موقع پر نازل ہوئی، جب جنگ کے دوران یہ خبر پھیلی کہ حضور اکرم ﷺ شہید ہوگئے ہیں۔
اس موقع پر کچھ مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے واضح فرمایا کہ ایمان کسی شخصیت کے
ساتھ نہیں بلکہ اللہ اور اُس کے دین کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔
آیت کا ترجمہ:
“محمد ﷺ تو صرف ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے
جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟” (آلِ عمران: 144)
تشریح:
- رسالت کی حقیقت:
یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ محمد مصطفی ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ ﷺ کو الوہیت یا خدائی صفات حاصل نہیں بلکہ آپ بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک عظیم رسول ہیں، جنہیں اللہ نے دین کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ - انبیاء کی سنت:
آیت میں فرمایا گیا کہ “قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ”، یعنی آپ ﷺ سے پہلے بھی رسول آئے اور اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہوگئے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کی بعثت اور وفات ایک الٰہی سنت ہے، جس میں کسی کو دوام حاصل نہیں۔ - ایمان کا امتحان:
جنگ اُحد میں جب مسلمانوں پر مشکل وقت آیا تو ان میں سے بعض کمزور دل لوگ یہ سوچنے لگے کہ اب دین کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مومنین کو متنبہ کیا کہ دین کا رشتہ صرف نبی اکرم ﷺ کی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل تعلق اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہے۔ - منافقت اور کمزوری کی مذمت:
اس آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ اگر نبی اکرم ﷺ کی وفات یا شہادت کی خبر سے کوئی شخص دین سے پھر جائے، تو وہ دراصل ایمان میں کمزور اور منافقت کا شکار ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ کے دین کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہے۔ - حضرت ابوبکرؓ کا تاریخی حوالہ:
جب حضور اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام پر غم کی شدت طاری تھی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے یہی آیت تلاوت کی، جس سے سب کی آنکھیں کھل گئیں اور حقیقت واضح ہوگئی کہ اسلام کی بقا کسی ایک شخصیت کی زندگی یا وفات سے وابستہ نہیں۔
اہم اسباق:
- ایمان کا تعلق صرف اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی شخصیت کے ساتھ مشروط نہیں۔
- رسول ﷺ کی وفات یا شہادت کے باوجود دین باقی اور قائم رہتا ہے۔
- مؤمن کو مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے۔
- یہ آیت منافقین اور کمزور ایمان والوں کے لیے تنبیہ ہے کہ دین سے پھرنا دراصل ہلاکت کا راستہ ہے۔
- اسلام ایک کامل نظام ہے جو قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔
نتیجہ:
سورۃ آلِ عمران کی یہ آیت ایمان اور اسلام کی پائیداری کا عظیم پیغام دیتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ
کی وفات کے بعد بھی دین قائم ہے، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ رہے، مشکلات میں صبر کرے اور
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ یہ آیت دراصل امتِ مسلمہ کے لیے ایمان کی پختگی اور استقامت کا بنیادی اصول
فراہم کرتی ہے۔
سوال نمبر 9:
سورۃِ البقرہ کی روشنی میں “طلاق اور عدت” کے احکام تفصیل سے بیان کریں۔
تعارف:
اسلام نے شادی کو مقدس بندھن قرار دیا ہے مگر جب ازدواجی زندگی میں ایسی صورتِ حال آئے کہ تعلق برقرار رکھنا ممکن نہ
رہے،
تو شرع نے طلاق کو ایک محدود، منظم اور اصولوں کے تابع طریقِ حل کے طور پر اجازت دی۔ سورۃِ البقرہ میں طلاق و عدت
کے اصول واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں تاکہ مرد و عورت دونوں کے حقوق کی حفاظت ہو، بچے کے نسب کی وضاحت ممکن رہے
اور معاشرے میں اجتماعی عدل برقرار رہے۔ اسلام نے طلاق کو “آخری حل” قرار دیا اور عدت کو توازن، عزت و حفاظت اور
اصلاح کا دور بنایا۔
1. طلاق کیا ہے؟ (تعریف):
طلاق شرعی طور پر وہ اعلانیہ عمل ہے جس سے شوہر بیوی کے نکاح کا تعلق یا تو مستقل یا وقتی طور پر ختم کرتا ہے۔ قرآن
میں طلاق کے احکام میں اعتدال، عدت کے اہداف اور طلاق کے بعد کے حقوق و فرائض بتائے گئے ہیں۔ سورۃِ البقرہ میں
طلاق کے متعلق اہم آیات خاص طور پر (آیاتِ متفرقات حوالہ: بیاناتِ فقہی میں اکثر 2:226–232 شامل ہوتی ہیں) میں
موجود ہیں جن سے بنیادی اصول اخذ ہوتے ہیں۔
2. طلاق کے بنیادی اصول (سورۃِ البقرہ کی روشنی میں):
- طلاق کا محدود اور اصولی ہونا:
قرآن میں طلاق کو ایسا عمل بتایا گیا ہے جس کے لیے حدود مقرر کی گئی ہیں؛ یعنی یہ بلا وجہ، جلدبازی یا ذلت کے ساتھ استعمال نہ کی جائے، بلکہ عاقل و بالغ ارادے اور متعقل انداز میں ہونا چاہیے۔ - عددِ طلاق اور طریقِ بازگشت:
سورۃِ البقرہ میں اللہ نے طلاق کی تعداد اور اس کے اثرات کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا کہ طلاق (عام طور پر) ایک یا دو بار رجعی (یعنی عدت کے اندر شوہر واپس لے سکے) ہو سکتی ہے اور اگر تین بار طلاق ہو جائے تو اس کے بعد نکاح میں خاص ضابطے آتے ہیں۔ (قرآن میں حکم دیا گیا کہ طلاق دو بار کے بعد یا تو باہمی بھلائی کے ساتھ رکھو یا عزت کے ساتھ رخصت کرو؛ اور اگر تیسری بار طلاق دے دی تو عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی اور سے نکاح کر کے طلاق نہ ہو جائے۔) - عدت کا مقصد:
قرآن عدت کو تین بنیادی مقاصد کے لیے وضع کرتا ہے:- حمل کی صورت میں بچے کی نسبت واضح ہو سکے۔
- عزت و وقار کی حفاظت ہو اور عورت کو وقت ملے کہ وہ صدمے سے نکل کر مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے۔
- مصالحت اور صلح کا موقع ملے؛ عدت دراصل رائے سازی اور باہمی سمجھ بوجھ کا وقت ہے۔
- طلاق کا اعلان اور نیت:
قرآن کا طرزِ عمل اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ طلاق کا اعلان احتیاط سے ہو؛ جو شخص عجلت یا غضب میں طلاق دے وہ شرعی اصولوں کے تابع ہو کر پھر بھی عدالتِ شریعت اور نیت کی روشنی میں جواب دہ ہوگا۔
3. رجعی اور بائن طلاق (فرق اور اثرات):
رجعی طلاق: وہ طلاق جس میں شوہر عدت کے دوران بیوی کو بغیر نئے نکاح کے واپس بلا سکتا ہے (بعض
فقہا کے مطابق اسی مرحلے میں رجوع پر ماضی کا نکاح بحال رہتا ہے)۔
بائن طلاق: وہ طلاق جو ناقابلِ بازگشت ہو (خاص طور پر تیسری طلاق کے بعد)؛ اس صورت میں دوبارہ
وہی فرد بیوی بنانے کے لیے نئی نکاح و مہر کی شرط ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں اگر تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس
شخص کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی اور سے نکاح کر کے طلاق نہ ہو جائے (حِلّہ کا مسئلہ)۔ (یہی قرآنی حکمت کا ایک حصہ
ہے جو طلاق کو سنجیدہ اور سنبھل کر استعمال کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔)
4. عدت کی اقسام اور مدت (تفصیلی):
- حیض والی عورت: عدت کی مدت تین حیضی دور ہے — یعنی تین حیض کے مکمل چکر۔ اس کا مقصد حمل کی جانچ اور مصالحت کا وقت ہے۔ (قرآن نے طلاق کے سلسلے میں یہ نصیحہ دیا کہ عورتیں اپنے عدت کے دور کو پورا کریں۔)
- حاملہ عورت: اگر عورت حملہ ہو تو عدت اُس کے بچے کی ولادت تک برقرار رہے گی؛ یعنی عدت کی مدت حمل کے ختم ہونے (بچے کی ولادت) پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ نسب کی تشخیص ضروری ہے اور حمل کی صورت میں انتظار منطقی ہے۔
- بے حیض (نابالغ یا محروم) عورت: جو عورت حیض کا تجربہ نہیں کرتی (جیسے بچی یا مینوپاز)، فقہی عموم میں عدت کی مدت تین مہینے یا تین قمری مہینے مانے جاتے ہیں—تاہم فقہاء میں اِس معاملے میں اختلاف ہے؛ قرآن نے عدت کی بنیادی حکمت واضح کی مگر فقہی جزئیات میں مکاتبِ فکر کی تشریحات مختلف رہیں۔
- شوہر کے انتقال پر بیوہ کی عدت: سورۃِ البقرہ میں ایک واضح حکم یہ بھی ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کو فوت پائیں، وہ چار ماہ اور دس دن (فقہی عموم: چہار ماہ و عشرۃ یوم) تک عدت میں رہیں۔ اس مدت کا مقصد احترامِ مرنے والے، جذباتی بقاء اور نسب کی صراحت ہے۔
5. عدت کے دوران حقوق و واجبات:
- عزت و وقار کا تحفظ: عدت کے دوران عورت کا مقام معاشرتی طور پر معزز رکھا جائے؛ اسے بے آبرو نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو فراہم کردہ حقوق سے محروم رکھا جائے۔
- کفالت و نفقہ: قرآن نے ازدواجی رشتہ میں انصاف و کفالت پر زور دیا؛ اگر طلاق رجعی ہو اور عورت عدت میں ہو تو عام شرعی اصول یہ ہے کہ عورت کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے—خاصة اگر وہ گھر میں رہے یا حاملہ ہو تو کفالت کا معاملہ قابلِ غور ہے۔ (تفصیلی نفاذ و مقدار فقہی دلائل پر مبنی ہے اور مکاتبِ فقہ میں تفصیلی قواعد مختلف ہیں۔)
- حکمِ مشورہ و صلح: سورۃِ البقرہ زوجین کو عدت کے دوران اصلاح (مصالحت) کا وقت قرار دیتی ہے؛ قرآن میں صلح کی ترغیب اور بدسلوکی سے روکا گیا ہے۔
6. نکاحِ دوبارہ اور حقوقِ بعد از عدت:
جب عدت پوری ہو جائے تو دونوں طرف آزاد ہوئے ہوتے ہیں؛ اگر شوہر چاہے تو نیک نیتی اور مناسب طریقے سے دوبارہ نکاح
کر سکتا ہے (اگر طلاق رجعی تھی تو بعض حالات میں رجوع سے نکاح بحال ہوتا ہے)، اور اگر طلاق بائن تھی تو نیا نکاح،
مہر اور شُرُوط ضروری ہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو مار کر یا حق تلف کر کے رکاؤ نہ بنایا جائے؛
اجازت اور منع میں انصاف ملحوظ رہے۔
7. اخلاقی، اجتماعی اور فقہی نکات (سورۃِ البقرہ سے حاصل شدہ):
- قرآن طلاق کو مباح مگر محدود اور احتیاطی قرار دیتا ہے — یعنی اسے بطور حل مانا جائے مگر اعمال میں عدل و انصاف بنیادی شرط ہوں۔
- عدت کا بنیادی مقصد بچے کے نسب اور عورت کے وقار کی حفاظت ہے؛ عدت کے ذریعے مصالحت کی راہیں کھلتی ہیں۔
- قرآن میں بار بار طلاق کے متعلق امن، نیکی اور باہمی احترام کی ہدایت ہے — یعنی دین کا نفاذ ظلم یا ذلت کے بدلے نہیں ہونا چاہیے۔
- فقہی مسائل (مثلاً تین طلاقوں کی ایک وقت میں بُنیاد، خلع کی تفصیل، نفقہ کی مخصوص مقدار وغیرہ) میں مختلف مکاتبِ فکر کے درمیان تفصیلی اختلافات پائے جاتے ہیں؛ اس لیے عمل میں مقامی فقہی رائے اور ماہرِ شرعی سے مشورہ بہتر رہتا ہے۔
8. عملی مشورے (اسلامی شریعت کی روح کے مطابق):
- طلاق سے پہلے صلح و مصالحت کے تمام راستے آزما لیں، مشورہ کریں، حکمت و شائستگی اختیار کریں۔
- طلاق کا اعلان باوقار، تحریری (جہاں قانون ایسا مانگے) اور شواہد کے ساتھ کریں تاکہ بعد میں الجھن نہ ہو۔
- عدت کے دوران عورت کے حقوق کی پاسداری کریں، خصوصاً اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی صحت اور بچے کی کفالت کا خیال رکھیں۔
- قومی قوانین اور شرعی اصول کے تقاضوں کو ساتھ رکھیں — جدید معاشروں میں طلاق کے قانونی اثرات (نفاذِ ہتک، گھریلو حقوق، بچوں کی تحویل وغیرہ) کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
نتیجہ:
سورۃِ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ طلاق اور عدت قرآنی اصولوں کے تحت ایک متوازن، انسان دوست اور معاشرتی مفاد کو
مقدم کرتے ہوئے نافذ ہونے چاہئیں۔ طلاق کو ہتھیار یا نفرت کے طور پر استعمال نہ کیا جائے؛ عدت کو ایک پاکیزہ دور
سمجھ کر عورت کی عزت، وقار اور بچوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ جہاں فقہی تفصیلات درکار ہوں وہاں ماہرِ فقہ و قانون
سے راہنمائی لی جائے تاکہ شرع و قانون دونوں کی روشنی میں عمل کیا جا سکے۔
سوال نمبر 10:
سورۃ البقرہ کی روشنی میں “نمرود، میسر اور قصاص” یا “شراب اور جوئے کی حرمت” پر مختصر نوٹ لکھیں۔
تعارف:
سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معاشرتی، اخلاقی اور قانونی احکام بیان کیے ہیں۔ ان میں نمرود کے باطل دلائل،
میسر (جوا) اور خمر (شراب) کی ممانعت اور قصاص (جان کے بدلے جان) کا حکم شامل ہیں۔ یہ احکام فرد اور معاشرے کو
فتنہ و فساد سے بچانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے نازل ہوئے۔
۱۔ نمرود:
سورۃ البقرہ آیت 258 میں نمرود کا ذکر ہے جس نے اللہ کی ربوبیت کے مقابلے میں دعویٰ کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باطل عقائد کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا
ہے۔
نمرود نے جواب میں کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ پھر ابراہیمؑ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے
نکالتا ہے،
اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ یہ واقعہ توحید کی عظمت اور باطل کی کمزوری کو واضح کرتا
ہے۔
۲۔ میسر (جوا):
قرآن مجید نے جوئے کو شیطانی عمل قرار دیا ہے کیونکہ یہ محنت کے بجائے اتفاق پر مبنی ناجائز کمائی ہے۔
سورۃ البقرہ (آیت 219) میں فرمایا گیا: “وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے:
ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔”
اس سے واضح ہوتا ہے کہ جوا انسانی عقل، اخلاق اور معیشت کو تباہ کرتا ہے۔
۳۔ قصاص:
سورۃ البقرہ (آیت 178) میں قصاص کا قانون بیان کیا گیا: “اے ایمان والو! تم پر قتل کے معاملے میں قصاص فرض کیا گیا
ہے،
آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔” یہ حکم معاشرے میں انصاف قائم کرتا ہے اور
قتل و خونریزی کو روکتا ہے۔ قصاص کا مقصد انتقام نہیں بلکہ عدل قائم کرنا اور انسان کی جان کو تحفظ دینا ہے۔
۴۔ شراب کی حرمت:
شراب کے متعلق ابتدا میں نرم انداز اپنایا گیا اور اس کے نقصانات بیان کیے گئے۔
آخرکار سورۃ المائدہ میں مکمل حرمت نازل ہوئی، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت 219 میں ہی واضح کر دیا گیا کہ
شراب کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ شراب انسان کی عقل، صحت اور معاشرتی وقار کو برباد کرتی ہے۔
اہم اسباق:
- باطل دلیل کبھی حق کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی، جیسے نمرود لاجواب ہوا۔
- جوا اور شراب انسان کی اخلاقی اور ذہنی صلاحیتوں کو تباہ کرتے ہیں۔
- قصاص کا قانون معاشرتی عدل اور امن قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
- قرآن نے انسان کو عدل، پرہیزگاری اور عقل مندی کی تعلیم دی ہے۔
نتیجہ:
سورۃ البقرہ میں بیان کردہ یہ احکام فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح کے لیے ہیں۔ نمرود کے قصے سے توحید کی سچائی،
جوئے اور شراب کی ممانعت سے اخلاقی پاکیزگی اور قصاص کے قانون سے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔
ان پر عمل کر کے ہی ایک پرامن اور صالح معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔
سوال نمبر 11:
سورۃ البقرہ کی روشنی میں “صبر” کی تعریف، فضیلت اور “شہید” کے فضائل تفصیل سے بیان کریں۔
تعارف:
سورۃ البقرہ میں صبر اور شہادت جیسے عظیم موضوعات پر نہایت حکمت اور جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔
صبر انسان کی شخصیت کا بنیادی ستون ہے اور شہادت اللہ کی راہ میں قربانی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ قرآن ان دونوں کو
ایمان، اخلاص اور قرب الٰہی کے لازمی عناصر کے طور پر بیان کرتا ہے۔
۱۔ صبر کی تعریف:
صبر کا مطلب ہے مشکلات، آزمائشوں اور تکالیف میں ثابت قدمی اختیار کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔
سورۃ البقرہ (آیت 153) میں ارشاد ہے:
“اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔”
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر محض برداشت نہیں بلکہ ایک فعال رویہ ہے جو مومن کو اللہ کی قربت تک پہنچاتا ہے۔
۲۔ صبر کی فضیلت:
- اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اپنی خاص معیت (ساتھ) کا وعدہ دیا ہے۔
- صابرین کے لیے قیامت کے دن اجر بے حساب ہے (سورۃ الزمر: 10 کی روشنی میں بھی وضاحت ہوتی ہے)۔
- صبر مشکلات کو آسان اور دل کو مطمئن کرتا ہے۔
- قرآن نے صبر کو کامیاب مومن کی پہچان قرار دیا ہے۔
۳۔ شہید کے فضائل:
سورۃ البقرہ (آیت 154) میں فرمایا گیا:
“اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔”
اس سے شہید کی عظمت اور ان کی ابدی زندگی کا تصور ملتا ہے۔
شہید کی خصوصیات:
- شہید زندہ ہے اور اسے رب کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے۔
- شہید کا خون گواہی ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی پر اخروی کامیابی کو ترجیح دی۔
- شہید کو قبر کے عذاب اور حساب کتاب سے نجات حاصل ہے۔
- شہید کی ایک عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے خون سے دین کی آبیاری کرتا ہے اور امت کے لیے مثال بنتا ہے۔
۴۔ صبر اور شہادت کا باہمی تعلق:
صبر اور شہادت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بغیر صبر کے شہادت ممکن نہیں، کیونکہ شہادت کے لیے پہلے دنیاوی لالچ،
خوف اور مشکلات پر قابو پانا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے صبر کو اہلِ ایمان کی صفت اور شہادت کو ان کے اعلیٰ مقام کا
ثمرہ قرار دیا۔
اہم اسباق:
- صبر انسان کو اللہ کے قریب اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
- صابر انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ امید اور دعا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔
- شہادت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔
- صبر اور شہادت دونوں ایمان کے اعلیٰ معیار کی علامت ہیں۔
نتیجہ:
سورۃ البقرہ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ صبر ہر آزمائش میں مؤمن کا ہتھیار ہے اور شہادت ایمان کا عروج ہے۔
صبر سے دل مطمئن اور زندگی پرسکون رہتی ہے جبکہ شہادت سے دین زندہ اور امت کی حفاظت ہوتی ہے۔
یہ دونوں اوصاف ایک مثالی مومن کی پہچان اور کامیابی کی کنجی ہیں۔
سوال نمبر 12:
“انفاق فی سبیل اللہ” پر قرآنی آیات کی روشنی میں تفصیلی مضمون یا بحث لکھیں۔
تعارف:
قرآنِ مجید میں “انفاق فی سبیل اللہ” کو ایمان کا لازمی حصہ اور قربِ الٰہی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔
انفاق سے مراد ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال، وسائل، وقت یا صلاحیتوں کو خرچ کرنا۔ سورۃ البقرہ میں
اس موضوع پر خاص زور دیا گیا ہے تاکہ مسلمان دنیاوی لالچ سے بلند ہو کر معاشرتی فلاح اور دینی تقویت کے لیے قربانی
دیں۔
۱۔ انفاق فی سبیل اللہ کی تعریف:
انفاق لغوی طور پر “خرچ کرنے” کو کہتے ہیں اور فی سبیل اللہ کا مطلب ہے “اللہ کی راہ میں”۔ یعنی اپنے
مال و دولت کو محض دکھاوے یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور مخلوقِ خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا۔
سورۃ البقرہ (آیت 261) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
“جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے سات بالیاں اگائیں، ہر بالی
میں سو دانے ہوں۔”
اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا اجر بے شمار ہے۔
۲۔ انفاق کے مقاصد:
- غربت اور معاشی نابرابری کا خاتمہ۔
- معاشرے میں ایثار، قربانی اور بھائی چارے کو فروغ دینا۔
- اسلامی معاشرتی نظام کو مضبوط کرنا۔
- انسان کو بخل، لالچ اور خودغرضی سے پاک کرنا۔
۳۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اقسام:
- فرض انفاق: جیسے زکوٰۃ جو ہر صاحبِ نصاب مسلمان پر لازم ہے۔
- نفلی انفاق: جیسے صدقہ، خیرات، یتیموں اور مسکینوں کی مدد۔
- قومی و اجتماعی انفاق: جیسے جہاد میں خرچ کرنا، مساجد اور تعلیمی ادارے قائم کرنا۔
۴۔ قرآنی آیات کی روشنی میں انفاق کی فضیلت:
- سورۃ البقرہ (آیت 262): “جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے خرچ کے پیچھے احسان جتانا اور ایذا نہیں دیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔”
- سورۃ البقرہ (آیت 274): “جو لوگ رات دن، خفیہ اور علانیہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔”
- سورۃ البقرہ (آیت 267): “اے ایمان والو! پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور زمین سے نکالی ہیں۔”
۵۔ انفاق کے اصول:
- انفاق خالص نیت کے ساتھ ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔
- پاک اور حلال مال سے انفاق کیا جائے۔
- محتاجوں، مسکینوں اور محروموں کو ترجیح دی جائے۔
- انفاق کے بعد احسان جتلانا یا تکلیف دینا سخت منع ہے۔
اہم اسباق:
- انفاق دل کو سکون اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے۔
- یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔
- انفاق سے معاشرتی انصاف اور مساوات قائم ہوتی ہے۔
- یہ عمل دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ضامن ہے۔
نتیجہ:
انفاق فی سبیل اللہ دراصل ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو فرد کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ
معاشرتی نظام کو بھی متوازن اور خوشحال بناتا ہے۔ قرآن کریم نے انفاق کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں خوشخبری دی ہے۔
اگر مسلمان اس حکم پر عمل کریں تو غربت، بھوک اور نابرابری ختم ہو سکتی ہے اور امتِ مسلمہ ایک مضبوط اور
مثالی معاشرہ بن سکتی ہے۔
سوال نمبر 13:
سورۃ البقرہ کی روشنی میں “متقین کی صفات” اور سورۃ آلِ عمران کی روشنی میں “توکل اور استغفار” پر مختصر نوٹ لکھیں۔
تعارف:
قرآنِ مجید انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے اور یہ اہلِ تقویٰ کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ سورۃ البقرہ اور
سورۃ آلِ عمران میں بالخصوص تقویٰ، توکل اور استغفار جیسی بنیادی صفات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ اوصاف نہ صرف فرد کو
اخلاقی اور روحانی کمال عطا کرتے ہیں بلکہ اجتماعی طور پر امتِ مسلمہ کی فلاح اور کامیابی کے ضامن ہیں۔
الف) متقین کی صفات (سورۃ البقرہ کی روشنی میں):
سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب “متقین” کے لیے ہدایت ہے۔ ان متقین کی نمایاں صفات درج ذیل ہیں:
- ایمان بالغیب: وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ، فرشتوں، آخرت اور ان امور پر جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔
- اقامتِ صلاۃ: نماز کو پابندی اور خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔
- انفاق فی سبیل اللہ: اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔
- ایمان بالکتب والرسل: قرآن سمیت تمام آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
- یقین بالآخرت: آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم کامیاب اور فلاح یافتہ قرار دیتا ہے۔
ب) توکل اور استغفار (سورۃ آلِ عمران کی روشنی میں):
سورۃ آلِ عمران میں اہلِ ایمان کو مشکلات اور آزمائشوں کے وقت دو عظیم صفات اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے: توکل اور استغفار۔
- توکل علی اللہ:
اللہ پر بھروسہ کرنا متقین کی سب سے بڑی علامت ہے۔ سورۃ آلِ عمران (آیت 159) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: “جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بیشک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔” اس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے بعد اصل اعتماد اللہ کی قدرت پر ہونا چاہیے۔ - استغفار:
گناہوں سے بچنے کے باوجود جب انسان لغزش کا شکار ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا اہلِ ایمان کی صفت ہے۔ سورۃ آلِ عمران (آیت 135) میں فرمایا گیا: “اور وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔” یہ آیت استغفار کی اہمیت اور اللہ کی رحمت پر یقین کو ظاہر کرتی ہے۔
اہم اسباق:
- تقویٰ ایمان، عبادت اور انفاق کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے۔
- توکل انسان کو مشکلات میں حوصلہ اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔
- استغفار گناہوں کی بخشش اور دل کی طہارت کا ذریعہ ہے۔
- یہ اوصاف امتِ مسلمہ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔
نتیجہ:
سورۃ البقرہ اور سورۃ آلِ عمران میں بیان کردہ اوصاف دراصل ایک مثالی مسلمان کی پہچان ہیں۔ متقین کی صفات انسان کو
اللہ کا محبوب بناتی ہیں جبکہ توکل اور استغفار اسے مشکلات سے نجات دلاتے ہیں۔ اگر مسلمان ان صفات کو اپنالیں تو ان
کی زندگی میں سکون، خوشحالی اور کامیابی یقینی ہو جائے۔
سوال نمبر 14:
سورۃ آلِ عمران کی روشنی میں حضرت عیسیٰؑ کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔
تعارف:
قرآنِ مجید میں حضرت عیسیٰؑ کی شخصیت کو نہایت عظمت، پاکیزگی اور حقیقت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ آلِ عمران میں
ان کی ولادت، معجزات، دعوت اور مقام کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تاکہ امتِ مسلمہ ان کی اصل حقیقت سے واقف ہو اور
کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔
حضرت عیسیٰؑ کی شخصیت کے اہم پہلو:
- معجزانہ ولادت:
حضرت عیسیٰؑ بغیر باپ کے حضرت مریمؑ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ قرآن (آلِ عمران: 47) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: “اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف کہتا ہے ‘ہو جا’ اور وہ ہو جاتا ہے۔” یہ ولادت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ - اللہ کے برگزیدہ نبی:
حضرت عیسیٰؑ کو اللہ نے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہیں کتاب (انجیل) عطا کی گئی اور وہ لوگوں کو توحید اور تقویٰ کی طرف بلاتے تھے۔ - معجزات:
سورۃ آلِ عمران (49) میں حضرت عیسیٰؑ کے معجزات کا ذکر ہے، جیسے:- مٹی سے پرندے کی شکل بنانا اور اللہ کے حکم سے اس میں جان ڈال دینا۔
- پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔
- مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔
- لوگوں کو ان کے گھروں میں چھپے ہوئے راز بتانا۔
- دعوتِ توحید:
حضرت عیسیٰؑ نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ ہمیشہ فرماتے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اور میری ماں کو خدا نہ بناؤ۔ - انسانی حیثیت:
سورۃ آلِ عمران (59) میں حضرت عیسیٰؑ کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ان کی مثال حضرت آدمؑ کی طرح ہے، جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ - بشارت دینے والے نبی:
حضرت عیسیٰؑ نے اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی حضرت محمد ﷺ کی بشارت بھی دی۔ اس سے ان کی نبوت کا مقصد واضح ہوتا ہے کہ وہ سلسلۂ انبیاء کی ایک کڑی ہیں۔
اہم اسباق:
- حضرت عیسیٰؑ کی ولادت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔
- وہ صرف اللہ کے نبی اور بندے تھے، نہ کہ خدا یا خدا کے بیٹے۔
- ان کے معجزات اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے تاکہ لوگ ایمان لائیں۔
- انہوں نے اپنی امت کو توحید اور آخری نبی ﷺ کی بشارت دی۔
نتیجہ:
سورۃ آلِ عمران کی روشنی میں حضرت عیسیٰؑ کی شخصیت ایک عظیم نبی، سچے رسول اور اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر
سامنے آتی ہے۔ ان کی زندگی توحید، رسالت اور معجزات کا حسین امتزاج ہے جو انسانیت کو ایمان، اللہ پر بھروسہ اور
ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔
سوال نمبر 15:
“آیت الکرسی” کا اعراب، ترجمہ اور اس کے فضائل بیان کریں۔
تعارف:
آیت الکرسی قرآنِ مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے جسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ
تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت، علم اور بادشاہت کو جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اسے قرآن کی “سیدۃ
الآیات” قرار دیا۔
اعراب:
آیت الکرسی کا اعراب نہایت وسیع ہے، یہاں اختصار کے ساتھ اہم نکات ذکر کیے جا رہے ہیں:
- اللّٰہُ: مبتدا مرفوع بالضمة۔
- لَا إِلٰهَ: “لا” نافیۂ للجنس، “إلٰهَ” اسم لا منصوب۔
- إِلَّا هُوَ: “إلا” کے بعد “هو” بدل یا خبر۔
- الحَيُّ القيُّومُ: دونوں خبرِ ثانی ہیں۔
- لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ: “لا” نافیۂ، “تأخذه” فعل مضارع مرفوع، “سنة” فاعل مؤخر۔
- له ما في السماوات وما في الأرض: “له” جار و مجرور مقدم، “ما” موصول مبتدا مؤخر۔
- اسی طرح باقی جملے اللہ کی قدرت، علم اور سلطنت کے بیان پر مشتمل ہیں۔
ترجمہ:
“اللہ! اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو
کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو
کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے مگر جتنا وہ
چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہی بلند و برتر ہے۔”
فضائلِ آیت الکرسی:
- سب سے عظیم آیت:
حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: “اے ابوالمنذر! کیا تجھے قرآن کی سب سے عظیم آیت معلوم ہے؟” انہوں نے عرض کیا: ‘اللّٰہُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ’۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: ‘تمہیں علم و برکت نصیب ہوئی’۔” (مسلم) - حفاظت کا ذریعہ:
جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ (بخاری) - شیطان سے نجات:
آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک ڈھال ہے جو مؤمن کو ہر قسم کے وسوسوں اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ - ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اجر:
نبی کریم ﷺ نے فرمایا: “جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے جنت میں داخلے میں موت کے سوا کوئی چیز حائل نہیں۔” (نسائی، ابن حبان) - دل کو سکون:
آیت الکرسی پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ آیت اللہ کی عظمت اور قدرت کا جامع اعلان ہے۔
اہم اسباق:
- اللہ تعالیٰ اکیلا، زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔
- اس کی بادشاہت اور علم ہر چیز پر محیط ہے۔
- کسی کو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کا حق نہیں۔
- اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ، وہ ہمیشہ بیدار اور نگہبان ہے۔
- آیت الکرسی پڑھنا مؤمن کی حفاظت اور جنت کا ذریعہ ہے۔
نتیجہ:
آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور علم کا جامع اعلان ہے۔ اس کے پڑھنے سے دنیاوی و اخروی برکات حاصل ہوتی
ہیں۔ یہ نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور خطرات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے
مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو اپنی زندگی کا مستقل وظیفہ بنائے۔
سوال نمبر 16:
سورۃ الفاتحہ کا عربی متن، ترجمہ اور مضامین کا اختصار کے ساتھ بیان کریں۔
تعارف:
سورۃ الفاتحہ قرآنِ مجید کی پہلی سورت ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے۔ اسے “اُمّ الکتاب”، “سبع
مثانی” اور “سورۃ الشفاء” بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت قرآن کی اساس ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس
کی تلاوت فرض ہے۔
عربی متن:
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَۙ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِۙ
مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِۙ
اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُۙ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَۙ
صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْۙ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّیْنَ
ترجمہ:
“شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔
نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ جزا و سزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے
ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ
گمراہوں کا۔”
مضامینِ سورۃ الفاتحہ:
- توحید اور حمدِ باری تعالیٰ:
سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ تمام جہانوں کا پروردگار صرف اللہ ہے۔ - رحمت اور ربوبیت:
اللہ تعالیٰ کی دو اہم صفات یعنی الرحمن اور الرحیم کا بیان، جو اس کی لا محدود شفقت اور مہربانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ - یومِ جزا پر ایمان:
“مالکِ یوم الدین” ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخرت میں ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ - عبادت اور استعانت:
“ایاک نعبد و ایاک نستعین” کے ذریعے واضح کیا گیا کہ عبادت اور مدد صرف اللہ ہی سے ہے۔ یہ آیت بندگی کے عہد اور اللہ پر توکل کا اعلان ہے۔ - ہدایت کی دعا:
“اہدنا الصراط المستقیم” میں راہِ حق پر چلنے کی دعا کی گئی ہے، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ - راہِ نجات اور راہِ ہلاکت:
سورت کے آخر میں دو راستوں کا فرق بیان کیا گیا ہے: انعام یافتہ کا راستہ اور گمراہ و مغضوب کا راستہ، تاکہ مومن صحیح راہ کو اختیار کرے۔
اہمیت اور فضائل:
- یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے اور ہر نماز کا لازمی حصہ ہے۔
- اسے “اُمّ القرآن” کہا گیا کیونکہ قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔
- یہ دعا اور ذکر دونوں کا حسین امتزاج ہے۔
- رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔
نتیجہ:
سورۃ الفاتحہ قرآنِ حکیم کا خلاصہ ہے جس میں توحید، رسالت، آخرت، عبادت اور ہدایت کی جامع تعلیم دی گئی ہے۔ یہ سورت
ہر مسلمان کی روز مرہ زندگی اور عبادات کی بنیاد ہے اور اسی وجہ سے اسے قرآن کی روح کہا گیا ہے۔
سوال نمبر 17:
قرآنی آیات کی روشنی میں “تحویلِ قبلہ” کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کریں۔
تعارف:
تحویلِ قبلہ سے مراد وہ اہم واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عبادت کی سمت (قبلہ) کو بیتِ المقدس (بنی
اسرائیل
کے ساتھ روحانی تسلسل کے اظہار کے طور) سے بدل کر کعبہ (مسجدِ الحرام، مکہ) کی طرف مقرر فرمایا۔ یہ واقعہ اسلام
کی شناخت، امت کو الگ کرنے اور توحیدی تسلسل کو واضح کرنے کے لحاظ سے نہایت معنی خیز ہے۔ قرآنِ مجید میں اس واقعے
کی اہم آیات بنیادی طور پر سورۃِ البقرہ میں آئی ہیں (خصوصاً آیات 125 اور 142–150 کے دائرۂ معنی میں)۔
قرآنی ماخذ (مختصر حوالہ):
سورۃِ البقرہ کی چند آیتیں اس واقعہ کی تشریح اور حکمت بتاتی ہیں — خصوصاً آیات جو یہ بیان کرتی ہیں کہ بعض لوگ
تعجب یا اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدلا، نیز وہ آیات جو صراحت کے ساتھ رسول ﷺ کو حکم دیتی ہیں
کہ رخ مسجدِ الحرام کی جانب کر دیں۔ (قرآنی حوالہ جات: البقرہ: 125، 142–150 — تفسیری کتابوں میں ان آیات کی
تفسیر میں تفصیلی بیانات ملتے ہیں)
واقعہ کی تفصیل (نمط بیان):
1. ابتدا — ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں نے ابتدا میں قبلۂ نماز کے طور پر بیتِ المقدس (بیتُ الْمَقْدِس / مسجدِ
الاقصیٰ) کی طرف رخ کیا۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے نبیوں کی تسلسل اور مواصلت کا اظہار ہو اور مکہ سے
نئی امت کے لیے ایک عبوری شناخت ملے۔
2. اعلانِ فیصلۂ الٰہی — بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسولِ کریم ﷺ کو ہدایت دی کہ قبلہ تبدیل کر کے کعبہ
مبارک کی طرف رخ کرو۔ قرآن اس تبدیلی کو بطور حکمت و امتحان اور امت کے مخصوص ہدف کی علامت بتاتا ہے۔
3. غیردانستہ اعتراضات — قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعض کم فہم لوگ یا مخالفین تعجب کریں گے اور کہیں
گے:
“انھیں کیا چیز ان کے قبلے سے پھیر رہی ہے؟” (قرآنی اندازِ بیان میں یہی سوال بطور اعتراض ذکر ہوتا ہے)۔
4. حکمتیں اور دلیلیں — قرآن ان حکمتوں کا ذکر کرتا ہے جن میں امت کے لیے امتیاز (تفرقہ نمائی) پیدا کرنا، بندگی
اور اطاعت کا امتحان، اور ابراہیمی وراثت کی تکمیل شامل ہیں۔ نیز یہ عمل لوگوں کو دلیل کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے
تاکہ یہ
دکھایا جا سکے کہ اسلام محض کسی مقام یا ملت کی تقلید نہیں بلکہ براہِ راست الٰہی ہدایت کا تقاضا ہے۔
5. عملی نفاذ — حکم نازل ہوتے ہی نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کو قبلہ بدلنے کی ہدایت کی اور ازراہِ فرمانِ الٰہی مسلمان
نماز میں کعبہ کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ اس تبدیلی نے امت میں فوری روحانی وحدت پیدا کی — چاہے مسلمان جہاں بھی ہوں
وہ ایک ہی سمت کی طرف کھڑے ہوتے۔
قرآنی نکات اور تشریحی مضامین:
- امتحانی رکن: قرآن اس تبدیلی کو ایک آزمائش کا حصہ بتاتا ہے — بعض لوگ اس سے گرجاتے یا طنز کرتے، مگر ثابت قدمی ہی ایمان کی نشانی ہے۔
- امتِ وسط کا کردار: سورۃِ البقرہ میں جملۂ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی روشنی میں تغییرِ قبلہ کو امت کی مخصوص حیثیت، توازن اور رہنمائی کے اظہار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
- تاریخی تسلسل و توحید: قبلہ بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ سابق انبیاء کی طرف رخ غلط تھا، بلکہ یہ توحیدی تسلسل میں ایک مرحلہ ہے — کعبہ کو ابراہیمی مرکز کے طور پر واضح کیا گیا تاکہ امتِ اسلامیہ کے لیے عملی محور قائم ہو۔
- دینی خودمختاری: تبدیلی نے یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کی عبادات براہِ راست الٰہی ہدایت کے تابع ہوں گی، نہ کہ کسی انسانی یا اجتماعی دباؤ کی مرہونِ منت۔
صحابہ اور اہلِ کتاب کا ردِ عمل (مختصر):
بعض یہودیوں نے اس واقعے کو برا دیکھا یا تنقید کا موضوع بنایا—قرآن ان اعتراضات کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو صبر،
سمجھ داری اور الٰہی حکم کی اطاعت پر قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے حکمِ الٰہی کے مطابق فوراً عمل کیا
اور اس تبدیلی کو اطاعت و فرمان برداری کی اعلیٰ مثال بنایا۔
شرعی و عملی اثرات:
- قبلہ تبدیل ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے نماز کے لیے کعبہ کی طرف رخ کرنا بنیادی لوازم میں شامل ہو گیا — یہ امت کو عالمی وحدت کا شعوری اظہار بناتا ہے۔
- تغیرِ قبلہ نے حج اور عمرۃ کے مراحل کی شمولیت میں کعبہ کو مرکزی مقام قرار دے دیا۔
- شرعی طور پر سابقہ قبلی نمازیں (جو قبلے کے طور پر بیتِ المقدس کی طرف ادا کی گئیں) بطور عملِ صالح تسلیم کی گئیں — اس تبدیلی نے فقہی مسائل کو جنم دیا مگر عمومی اصل یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت میں عمل واجب ہے۔
روحانی و نظریاتی اہمیت — اسباق:
- اللہ کی ہدایت پر بے چون و چرا اطاعت؛ خواہ وہ حکم کسی بھی طریقے سے ظاہر ہو۔
- دینی شناخت اور امت کی اجتماعی یکجہتی کے لیے عملی نشانات (مثلًا مشترکہ قبلہ) ضروری ہیں۔
- تاریخی حلقوں اور سابقہ انبیاء کے ساتھ احترام کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے اپنا مخصوص مرکز قائم کیا — یہ توحیدی تسلسل اور نئی امتِ اسلامی کی الگ شناخت دونوں کو یکجا کرتا ہے۔
خلاصہ/نتیجہ:
تحویلِ قبلہ ایک قرآنی احکامی واقعہ ہے جو امتِ مسلمہ کی تاریخ میں سنگِ میل ہے۔ قرآنی آیات اس واقعہ کو صرف ایک
انسانی رخ بدلنے سے بڑھ کر بیان کرتی ہیں — یہ اطاعت، امتحان، امت کی پہچان اور ابراہیمی وراثت کے تسلسل کا مظہر
ہے۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو عالمِ اسلام میں ایک مشترکہ مرکز اور عبادتی یکجہتی دی، اور ہمیں سکھایا کہ دینی اہداف
اور الٰہی ہدایات پر عمل امت کو مضبوط اور مربوط رکھتے ہیں۔
سوال نمبر 18:
آیت کا ترجمہ اور “محبتِ رسول” پر نوٹ لکھیں:
“قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ”
تعارف:
محبتِ رسول ﷺ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ قرآنِ مجید نے مختلف مقامات پر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت
اور مغفرت کے دروازے اسی وقت کھلتے ہیں جب انسان رسول اللہ ﷺ کی پیروی اختیار کرتا ہے۔ مذکورہ آیت سورۃ آلِ عمران
(آیت 31) میں نازل ہوئی جو محبتِ الٰہی کے مدعیوں کو آزمائش کی کسوٹی پر پرکھتی ہے۔ یہ آیت محبتِ رسول کو محبتِ
الٰہی تک رسائی کا ذریعہ قرار دیتی ہے۔
آیت کا ترجمہ:
“کہہ دیجیے (اے نبی ﷺ)! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ
بخش دے گا۔” (سورۃ آلِ عمران: 31)
پس منظرِ نزول:
مفسرین کے مطابق بعض لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تاکہ واضح کر دیا
جائے کہ محض زبانی دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ ﷺ کی کامل اتباع ہے۔
محبتِ رسول کی حقیقت:
- ایمانی تقاضا: محبتِ رسول ﷺ ایمان کی اصل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: “تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔”
- اتباعِ رسول: محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل میں نبی کریم ﷺ کی سنت کی پیروی کرے۔ قرآن نے واضح کیا ہے کہ اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔
- اطاعت و فرمانبرداری: محبتِ رسول کا عملی مظہر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں رسول اکرم ﷺ کی تعلیمات کو اپنائیں، خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات یا اخلاقیات۔
محبتِ رسول کے ثمرات:
- اللہ کی محبت کا حصول: جو رسول اللہ ﷺ سے محبت اور اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔
- مغفرتِ الٰہی: اتباعِ رسول کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
- دینی و دنیاوی کامیابی: محبتِ رسول کے ذریعے انسان کو دنیا میں سکونِ قلب اور آخرت میں نجات نصیب ہوتی ہے۔
- امت کا اتحاد: رسول ﷺ سے محبت امت کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے اور روحانی یکجہتی عطا کرتی ہے۔
محبتِ رسول کے عملی تقاضے:
- نبی کریم ﷺ کی سنت پر عمل پیرا ہونا۔
- آپ ﷺ کے اخلاق و سیرت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا۔
- آپ ﷺ پر درود و سلام کی کثرت کرنا۔
- دین کی خدمت، تبلیغ اور پیغامِ رسالت کو آگے پہنچانا۔
- آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کے ہر پہلو سے اجتناب اور دفاعِ رسالت میں ثابت قدمی۔
خلاصہ/نتیجہ:
قرآن کی یہ آیت محبتِ رسول کی اصل حقیقت بیان کرتی ہے۔ حقیقی محبت زبانی دعووں میں نہیں بلکہ عملی اتباع میں ہے۔
جو شخص رسول اکرم ﷺ کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کا حق دار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر
لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور ﷺ کو اپنا آئیڈیل بنائے اور محبتِ رسول کو اپنی زندگی کا مقصدِ اعلیٰ
قرار دے۔
| AIOU Course Code 472 Guess Paper 2025 AIOU BA Guess Paper 2025 MRPAKISTANI.COM | |
|---|---|
| 472 Code Past Papers & Solved Assignments | |
| 472 Code Past Papers | Download Here |
| 472 Code Assignments | Download Here |
| For admission, guess paper, past papers, jobs and any educational information visit website MR Pakistani and youtube channel Asif Brain Academy. | |